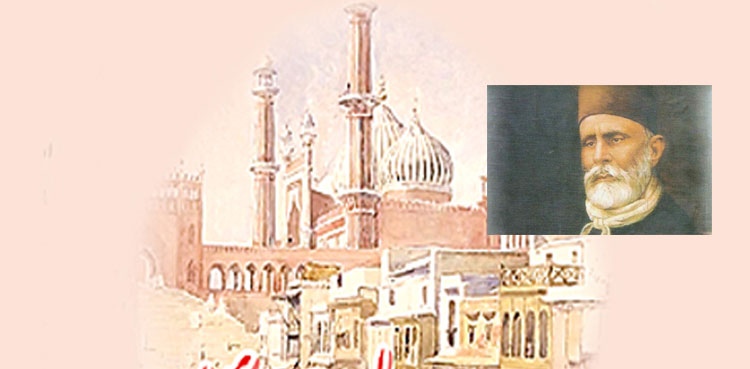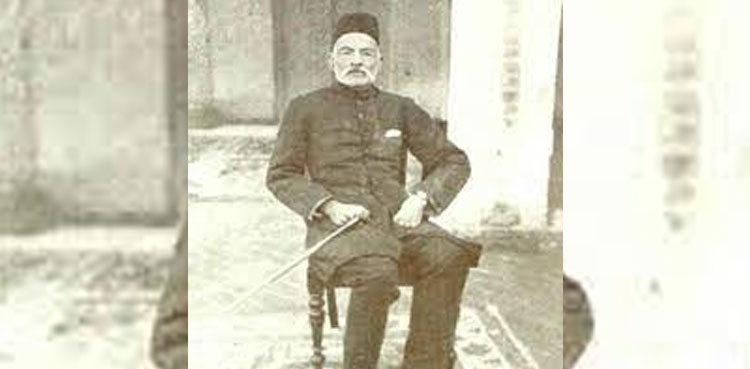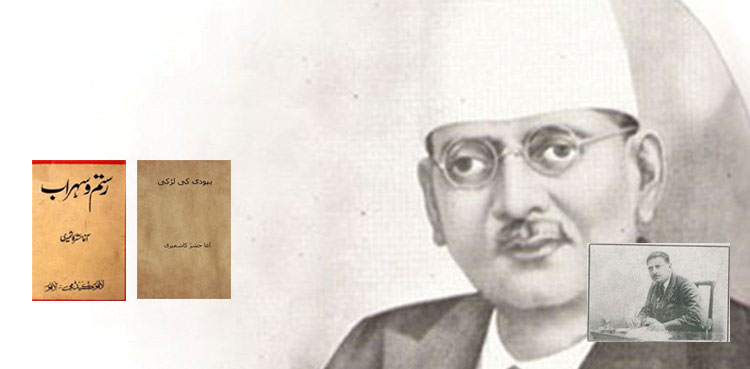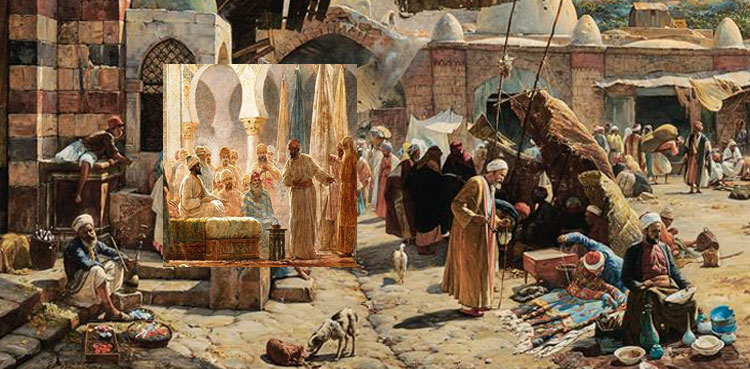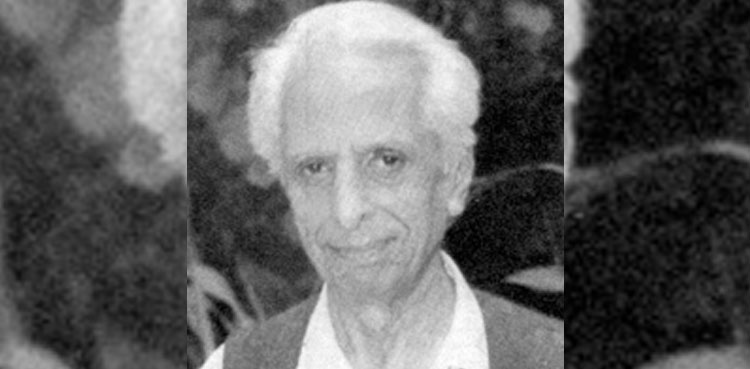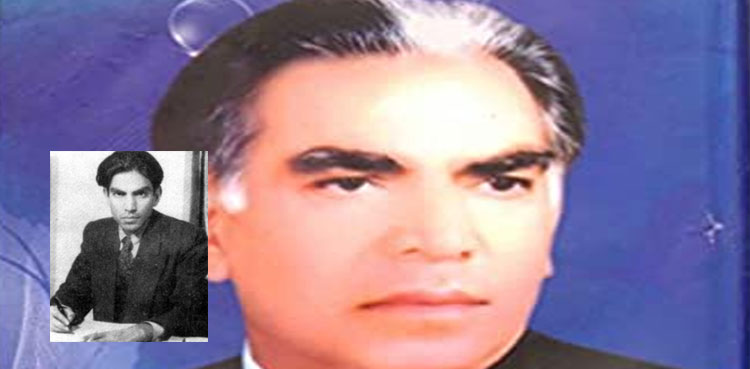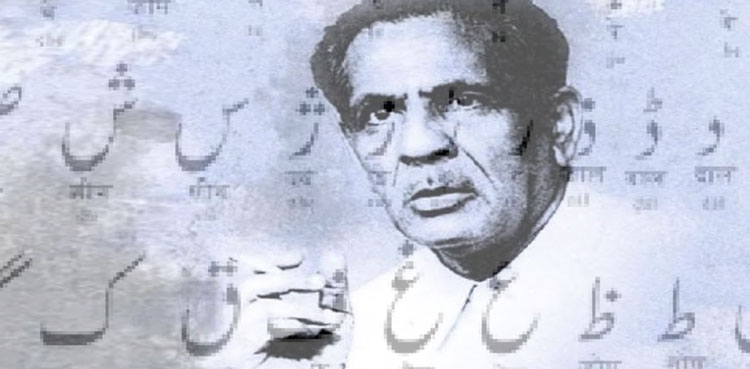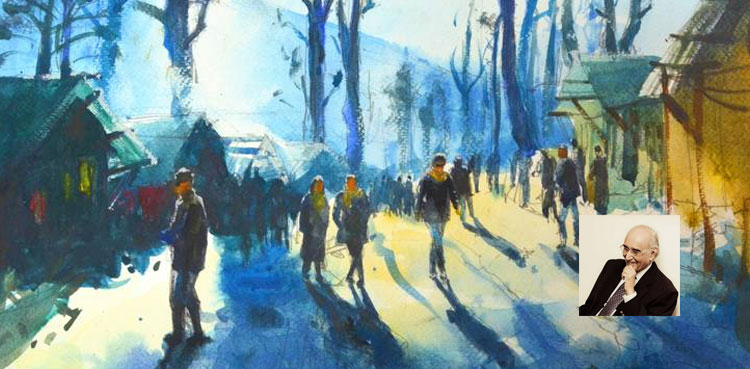حالی کے دوست بے شمار تھے، لیکن دشمنوں اور مخالفوں کی کمی بھی نہ تھی۔ ان کے مخالفین میں مذہبی غیر مذہبی اور دوست نما دشمن شامل تھے۔
حالی کی مخالفت کی ایک خاص وجہ ان کی سر سیّد سے دوستی، علی گڑھ تحریک سے وابستگی اور سر سیّد کی سوانح حیاتِ جاوید کی تصنیف تھی۔ ہماری اس تحریر میں چند پردہ نشین مردوں کے نام بھی آئیں گے جو ظاہراً دوستی کا دَم بھرتے تھے، لیکن ان کے دل حالی سے صاف نہ تھے۔ بقول میر انیس ”میں نے تو ایک دل بھی نہ دیکھا جو صاف ہو۔“
حالی کی مخالفت ادیبوں اور شاعروں کا مرغوب مشغلہ تھا۔ اگرچہ سر سیّد، شبلی نعمانی، ڈپٹی نذیر احمد اور علّامہ اقبال کی طرح حالی پر کفر کا فتویٰ نہیں لگایا گیا، مگر حالی کی شخصیت اور فن کو مسلسل نشانہ بنایا گیا۔
مذہبی لوگ حالی کو سر سیّد کی بانسری اور نیچری کہتے تھے۔ حالی نے جو اُردو شاعری کی پاکیزگی کی مہم کو اپنا شعار بنایا تھا وہ بہت سے شاعروں اور ادیبوں کو کھلتا تھا کیوں کہ وہ حالی کو اہلِ دلّی اور لکھنؤ نہیں مانتے تھے، وہ حالی کو پانی پت کا ایک معمولی شاعر جانتے تھے۔
”دلّی دلّی کیسی دلّی، پانی پت کی بھیگی بلی“
حالی کی مخالفت ان کی موضوعاتی نظموں سے شروع ہو چکی تھی۔ مسدسِ حالی کی عوام میں پذیرائی ان کے مخالفین کے لیے خطرے کی گھنٹی محسوس ہو رہی تھی جو فن برائے فن وہ بھی بطور تفنّن کے قائل تھے۔ حالی ایسی شاعری کو عفونت میں سنڈاس سے بدتر بتا رہے تھے اور ایسے شاعروں کی موجودگی یا غیر موجودگی سے متاثر نہ تھے جیسا کہ انھوں نے مسدس میں اعلانیہ کہا تھا:
یہ ہجرت جو کر جائیں شاعر ہمارے
کہیں مِل کے خس کم جہاں پاک سارے
مقدمہ شعر و شاعری میں چوما چاٹی کی شاعری پر شدید رد عمل نے لکھنؤ اور دلّی کے رومانی شعرا کو حالی کے مقابل کر دیا۔ درجنوں حالی کو دشنام اور نازیبا خطوط ملنے لگے۔ مختلف روزنامے اور رسالے مستقل طور پر حالی کے خلاف صف آرا ہو گئے جن میں حسرت موہانی کا اردوئے معلّیٰ اور سجاد حسین لکھنوی کا اودھ پنج پیش پیش تھے۔ حالی کے خلاف سوقیانہ ہجو لکھی جانے لگیں۔ اودھ پنج کے سرورق پر کئی سال تک یہ شعر چھپتا رہے:
ابتر ہمارے حملوں سے حالی کا حال ہے
میدانِ پانی پت کی طرح پائمال ہے
حالی کو خالی، جعلی، مالی، خیالی اور ڈفالی جیسے ناموں سے یا د کیا جانے لگا۔ لکھنؤ اور دلّی کے اہلِ زبان کہتے تھے، یہ پانی پتی شخص کس جرأت سے اہلِ زبان کے ہم زبان ہی نہیں بلکہ مسیحائے زبان ہونے کی کوششیں کررہا ہے۔ حالی ان تمام حملات کا خاموشی سے جواب دے رہے تھے اور ہمہ تن دن رات چمنستانِ شعر کی پاکیزگی میں مصروف تھے۔
اردو دنیا اور دنیائے ادب کی تاریخ پر نظر ڈالی جائے تو ہمیں معاصرین پر تخریبی تنقید نظر آتی ہے جیسے والٹیر کا حملہ شیکسپیئر پر، سودا کا حملہ میر پر، شیفتہ کا حملہ نظیر پر رجب علی بیگ کا حملہ میر امن پر وغیرہ۔ چنانچہ ہر ادب اور ہر دور میں تخریبی تنقید نظر آتی ہے۔
یہاں ہم حالی کے چند معاصرین کی معاندانہ تنقید کو مستند حوالوں سے درج کرتے ہیں۔ حسرت موہانی اُردوئے معلّیٰ میں حالی پر سخت اعتراضات کرتے تھے۔ ایک اسی قسم کا واقعہ تذکرہ حالی میں شیخ اسماعیل پانی پتی نے یوں لکھا ہے:
”علی گڑھ کالج میں کوئی عظیم الشان تقریب تھی۔ نواب محسن الملک کے اصرار پر مولانا حالی بھی اس میں شرکت کے لیے تشریف لائے اور حسبِ معمول سید زین العابدین مرحوم کے مکان پر فروکش ہوئے۔
ایک صبح حسرت موہانی دو دوستوں کے ساتھ مولانا کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ چندے اِدھر اُدھر کی باتیں ہوا کیں۔ اتنے میں سیّد صاحب موصوف نے بھی اپنے کمرے میں سے حسرت کو دیکھا۔ اُن میں لڑکپن کی شوخی اب تک باقی تھی۔ اپنے کتب خانے میں گئے اور اُردوئے معلّیٰ کے دو تین پرچے اُٹھا لائے۔ حسرت اور اُن کے دوستوں کا ماتھا ٹھنکا کہ اب خیر نہیں۔ اور اُٹھ کر جانے پر آمادہ ہوئے، مگر زینُ العابدین کب جانے دیتے تھے۔ خود پاس بیٹھ گئے۔ ایک پرچے کے ورق الٹنا شروع کیے اور مولانا حالی کو مخاطب کر کے حسرت اور اُردوئے معلّیٰ کی تعریفوں کے پُل باندھ دیے، کسی کسی مضمون کی دو چار سطریں پڑھتے اور واہ خوب لکھا ہے کہہ کر داد دیتے، حالی بھی ہوں، ہاں سے تائید کرتے جاتے تھے۔
اتنے میں سیّد صاحب مصنوعی حیرت بلکہ وحشت کا اظہار کرکے بولے:
”ارے مولانا یہ دیکھیے آپ کی نسبت کیا لکھا ہے اور کچھ اس قسم کے الفاظ پڑھنا شروع کیے۔ سچ تو یہ ہے کہ حالی سے بڑھ کر مخربِ زبان کوئی نہیں ہوسکتا اور وہ جتنی جلدی اپنے قلم کو اُردو کی خدمت سے روک لیں اُتنا ہی اچھا ہے۔
فرشتہ منش حالی ذرا مکدّر نہیں ہوئے اور مسکرا کر کہا تو یہ کہا کہ نکتہ چینی اصلاحِ زبان کا بہترین ذریعہ ہے اور یہ کچھ عیب میں داخل نہیں۔“
کئی روز بعد ایک دوست نے حسرت سے پوچھا اب بھی حالی کے خلاف کچھ لکھو گے؟ جواب دیا جو کچھ لکھ چکا، اُسی کا ملال اب تک دل پر ہے۔ حالی کا یہ ضبط، وقار اور عالی ظرفی بڑے بڑے مخالفوں کو شرمندہ اور نکتہ چینوں کو پشیمان کردیتی تھی۔
سچ تویہ ہے کہ لعن و طعن، گالی و شنام، طنز و اعتراضات کے طوفان کو حالی نے ایک نرالے طریقے سے زیر کیا۔
کیا پوچھتے ہو کیونکر سب نکتہ چیں ہوئے چُپ
سب کچھ کہا اُنھوں پر ہم نے دَم نہ مارا
(سید تقی عابدی کے مضمون سے اقتباسات)