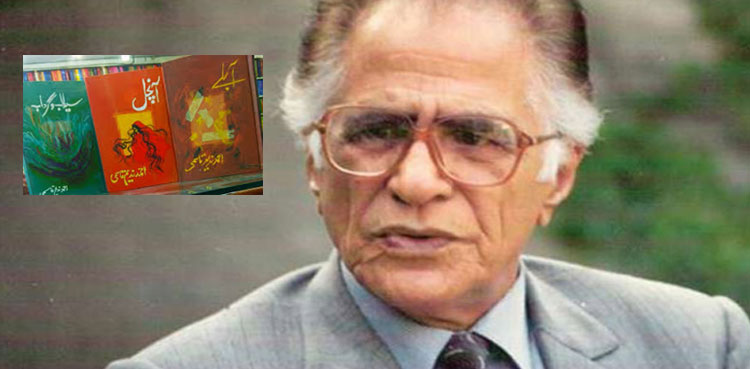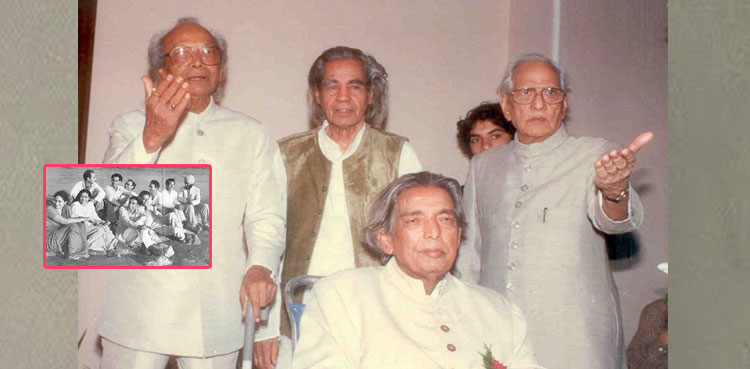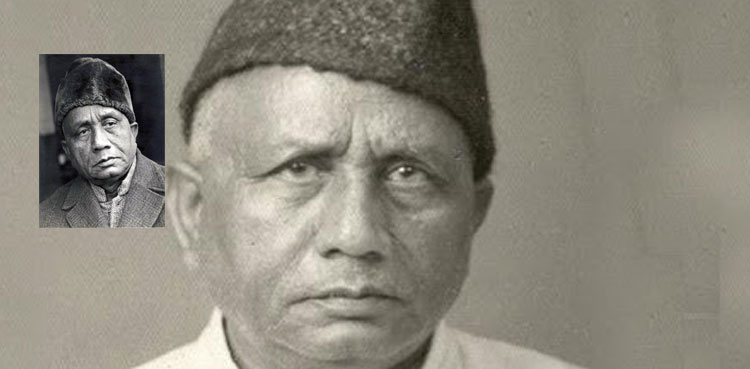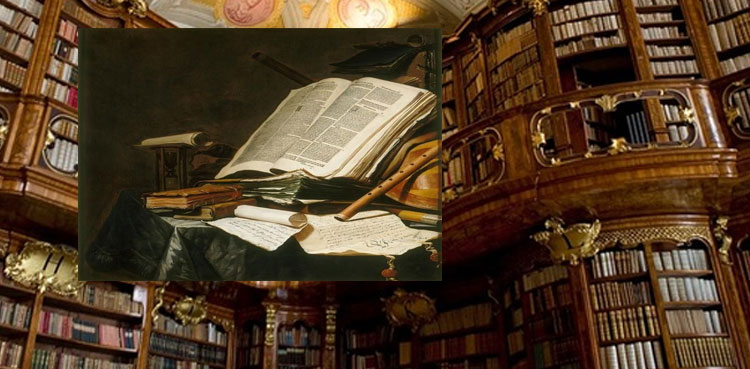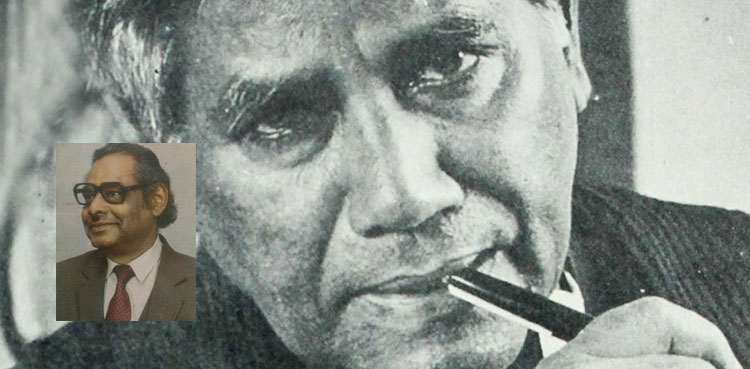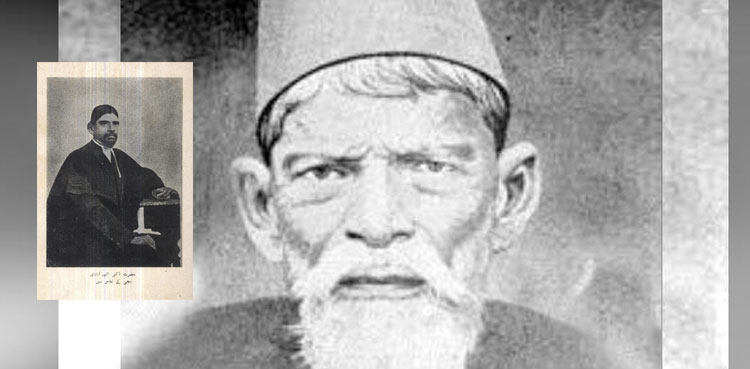ایک سوداگر جو ایک قلعے میں زندگی بسر کرتا تھا، اس کا پیشہ پوستین دوزی تھا۔ وہ گاؤں کے قصّابوں سے بھیڑ، گائے کی کھالیں خریدتا۔ انھیں رنگتا اور پھر پوستینیں بناتا اور بیچتا۔
ایک رات ایسا اتفاق ہوا کہ ایک بھوکی لومڑی قلعے کے پاس سے گزر رہی تھی کہ اچانک بھیڑ کی کھال کی بُو اس کی ناک میں دَر آئی اور وہ خوراک کے لالچ میں قلعے کے نزدیک کی ایک بدر رو کے رستے قلعے میں داخل ہوگئی، بُو سونگھتی سونگھتی پوستین دوز کی دکان تک جا پہنچی اور کھالوں کے سراغ میں مصروف ہوگئی۔ وہ کھالوں کی بُو سے سرشار اور خوش ہو گئی تھی۔
اس نے چند کھالوں پر اپنے دانت صاف کیے اور ان سے کُچھ تکّے نوچ کھائے، بعض کھالوں کو جگہ جگہ سے پھاڑ ڈالا اور جب دیکھا کہ یہ تو صرف کھالیں ہیں اور ان میں گوشت نام کو نہیں تو جس راستے سے آئی تھی، اسی سے لوٹ گئی اور صحرا کی طرف بھاگ نکلی۔
اگلی کئی راتوں تک اس کا یہی وتیرہ رہا۔ کھالوں کی بُو اور گوشت کے لالچ میں وہ بدر رو کے رستے قلعے میں داخل ہوتی، سوداگر کی دکان کے اندر جاتی اور اُسی طرح کھالوں کو چیرتی پھاڑتی اور پھر لوٹ آتی۔
بیچارہ سوداگر لومڑی کے پاؤں اور پنجوں کے نشان دیکھ کر حقیقتِ حال کو جان گیا تھا۔ لومڑی کے ہاتھوں اس کا ناک میں دَم آگیا تھا۔ اُس نے اپنے آپ سے کہا: بہتر ہے کہ میں کچھ راتیں بے خوابی میں گزاروں اور چالاک لومڑی کو اس کے کیے کا مزہ چکھاؤں۔ اس نے ایسا ہی کیا۔
اسے معلوم تھا کہ قلعے کی دیواریں بہت بلند ہیں اور اس کے دروازے بھی رات کو بند ہو جاتے ہیں۔ اسے یہ بھی اندازہ ہوگیا کہ کتّوں کے ڈر سے لومڑی دن کے وقت قلعے میں نہیں رہ سکتی۔ بالآخر وہ یہ راز پا گیا کہ لومڑی بدر رو کے رستے قلعے میں داخل ہوتی ہے۔
ایک رات سوداگر نے اپنے اوپر نیند کو حرام کیا۔ وہ بدر رو کے سوراخ کے قریب گھات میں بیٹھ گیا۔ بیٹھا رہا، بیٹھا رہا حتّٰی کہ صبح ہونے سے کچھ پہلے لومڑی حسبِ معمول بدر رو کے رستے اندر آئی اور اس نے کھالوں کے ذخیرے کی جانب رخ کیا۔ سوداگر نے بھی اپنی جگہ سے حرکت کی اور اس تختے سے، جسے وہ ساتھ لیتا آیا تھا، بدر رو کا رستہ بند کردیا اور اس کے ساتھ مٹی کا پشتہ لگا کر اسے خوب مضبوط کر دیا۔ پھر اس نے لاٹھی ہاتھ میں لی اور لومڑی کے کھوج میں چل پڑا۔
جب وہ اپنی دکان کے قریب پہنچا، لومڑی اپنے کام سے فارغ ہوکر واپس جارہی تھی۔
جونہی لومڑی کی نگاہ اس شخص پر پڑی جو ہاتھ میں لاٹھی تھامے اس کے درپے تھا، اس نے راہِ فرار اختیار کی۔ سوداگر بھی اس کے پیچھے تیزی سے دوڑا۔
جب لومڑی بدر رو کے سوراخ کے نزدیک پہنچی تو اُسے بند پایا۔ اس نے چاہا کہ دروازے کے رستے بھاگ لے، مگر قلعے کا دروازہ بھی بند تھا۔ اسے خیال آیا کہ گلی کوچوں میں داخل ہوکر بھاگ نکلے، مگر کتّوں کی عَو عَو نے اسے خوف میں مبتلا کر دیا۔ ناچار اس نے سوچا کہ سوداگر کو خوف زدہ کرنے کے لیے اس پر حملہ کرے۔ اس سے پہلے کہ وہ ایسا کرتی، سوداگر نے لاٹھی سے اس کے سَر پر ایسی ضرب لگائی کہ وہ درد سے بے حال ہوکر زمین پر گر پڑی۔
لومڑی نے بھانپ لیا تھا کہ اس کے فرار کے سارے رستے بند ہوچکے ہیں۔ اب اگر وہ زیادہ دوڑ دھوپ کرتی ہے تو یا تو وہ لاٹھیاں کھا کر ماری جائے گی یا اس شور غوغے سے کتّوں کو خبر ہو جائے گی اور معاملہ اور بگڑ جائے گا، لہٰذا اس نے عافیت اسی میں سمجھی کہ وہ یونہی بے حس و حرکت پڑی رہے، گویا مرچکی ہے۔
جب سوداگر کو اندازہ ہوا کہ اس کی پہلی ضرب ہی کاری ثابت ہوئی اور اس نے لومڑی کو ادھ موا کردیا تو اس کے دل میں رحم آیا اور وہ خود سے کہنے لگا: بس کافی ہے۔ اگر وہ مرنے کے لائق تھی تو قریبِ مرگ ہے۔ اگر ایسا نہیں تو بھی وہ بہرحال تائب ہو جائے گی اور دوبارہ اس قلعے کے نزدیک نہیں پھٹکے گی۔
جاتے جاتے اس نے اُسے پاؤں سے ایک ٹھوکر بھی لگائی، مگر اسے بے حس و حرکت پاکر اپنے گھر لوٹ آیا۔ اسی اثناء میں اندھیرا چھٹنے لگا تھا اور لوگ اپنے اپنے گھروں سے باہر آنا جانا شروع ہوگئے تھے۔
بدفطرت لومڑی جس وقت زمین پر پڑی خود کو جھوٹ موٹ مردہ ظاہر کررہی تھی، اسے خیال آیا کہ قلعے کا دروازہ اور بدر رو کا رستہ تو بند ہے، اب اگر میں حرکت کرتی ہوں اور کوئی مجھے دیکھ لے تو داد فریاد شروع ہو جائے گی، کتّوں کو خبر ہو جائے گی اور وہ میری تِکّہ بوٹی کر ڈالیں گے۔ بہتر یہی ہے کہ میں اسی طرح مچلی بنی پڑی رہوں تاکہ دھوپ نکل آئے، قلعے کا دروازہ کھُل جائے اور میں فوراً اٹھوں اور فرار کر جاؤں۔
آہستہ آہستہ فضا زیادہ روشن ہوتی گئی۔ لوگ آنے جانے لگے اور ان کی نگاہیں لومڑی پر پڑنے لگیں۔ ان میں سے ایک قریب آیا اور اسے مردہ سمجھ، ٹھوکر مار کر آگے بڑھ گیا۔ ایک اور شخص نے اسے دیکھا، بُرا بھلا کہا اور چل دیا۔ اُدھر سے کچھ بچّوں کا بھی گزر ہوا۔ انھوں نے لومڑی کی دُم پکڑ کر ادھر اُدھر کھینچنا شروع کر دی، بڑی عمر کے لوگوں نے ان کی سرزنش کی۔
لومڑی یونہی چپکی پڑی رہی اور اس نے کسی قسم کا ردِّعمل ظاہر نہ کیا اور یہی سوچتی رہی کہ جب تک کتّے قلعے کے اندر ہیں اور جب تک دروازہ بند ہے، راہِ فرار کی کوئی صورت نہیں۔ سو صبر کرنا چاہیے کیوں کہ صبر اور خاموشی ہر چیز سے بہتر ہے۔
رفتہ رفتہ کچھ بیکار اور آوارہ منش لوگ لومڑی کے گرد آن اکٹھے ہوئے اور لگے اس کے بارے میں باتیں کرنے۔ ہر کوئی اپنی اپنی ہانک رہا تھا۔ وہ جاننا چاہتے تھے کہ یہ کہاں سے آٹپکی اور یہاں موت سے کیسے دوچار ہوئی۔
ایک بولا: اسے یقیناً کتّوں نے مارا ہے۔ دوسرے نے جواب دیا: نہیں اگر کتّوں کی نگاہ اس پر پڑی ہوتی تو وہ اتنی آسانی سے اُسے چھوڑ نہ دیتے۔ اتنے میں ایک بوڑھا، جو دراصل قلعے کا دروازہ کھولنے پر مامور تھا، موقع پر آن پہنچا اور گویا ہوا: میں نے ایک فال گیر سے سنا ہے کہ اگر لومڑی کے بال آگ میں جلائے جائیں تو جادو ٹونے کا اثر زائل ہوجاتا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی جیب سے چاقو نکالا اور لومڑی کے جسم سے تھوڑی سی پشم کاٹ کر کاغذ میں رکھ، جیب میں اُڑس لی اور قلعے کا دروازہ کھولنے چل دیا۔
ایک اور شخص جو وہاں کھڑا تھا بولا: یہ فضول باتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جادو ٹونا جھوٹ ہے اور اس کا چنداں اثر نہیں ہوتا۔ دوسری بات یہ کہ لومڑی کے بالوں کا سحر اور جادو سے کیا تعلق؟
لومڑی کہ اپنے اردگرد کھڑے لوگوں کی بھانت بھانت کی بولیاں سن رہی تھی، اپنے دل میں کہنے لگی: یہ جو کہتے ہیں کہتے رہیں، پروا نہ کر۔ بہتر ہے صبر کر اور جب بھیڑ چَھٹ جائے، فرار ہو جا۔ وہ بوڑھا جو میرے جسم کی تھوڑی سی پشم کاٹ لے گیا، توجہ کے قابل نہیں۔ اِس وقت صبر اور خاموشی ہر چیز سے بہتر ہے۔
اتنے میں ایک بڑھیا بھی موقعے پر آپہنچی۔ اس نے لوگوں کے ہجوم کو چیر کر اپنا راستہ بنایا اور کہنے لگی: میں نے بڑے بوڑھوں سے سنا ہے کہ لومڑی کا کان چشمِ بد سے محفوظ رہنے کے لیے اچھا ہے۔ اس نے بھی آگے بڑھ کر لومڑی کے کان کا ذرا سا حصہ کاٹا اور ساتھ لیے چل پڑی۔ لومڑی کو کان کے کٹنے سے بڑی تکلیف پہنچی اور اس کا دل چاہا کہ روئے پیٹے، مگر لوگوں کے ہجوم سے ڈر کر اس نے چُپ سادھے رکھی اور خود سے کہنے لگی: کان کے ذرا سے حصّے کے کٹ جانے کا کیا مضائقہ۔ جانے دے، بڑھیا بھی اس سے خوش ہوئی ہوگی۔ میرے لیے صبر اور خاموشی ہر چیز سے بہتر ہے۔
اس موقع پر ایک اور شخص وہاں آدھمکا۔ لومڑی کو دیکھا اور کہا: واہ واہ! میں نے سنا ہے کہ اگر کسی شخص کے پاس لومڑی کا دانت ہو تو کتّا اس پر حملہ آور نہیں ہوتا۔ یہ کہا اور ایک پتھر سے لومڑی کا ایک دانت توڑا اور اپنے ساتھ لے کر چلتا بنا۔
اب لومڑی کی قوتِ برداشت جواب دے چکی تھی اور وہ دل ہی دل میں کہہ رہی تھی: کیسے احمق لوگ ہیں۔ یہ نہیں سوچتے کہ اگر میرے ایک دانت سے یہ معجزہ ممکن ہے تو پھر میں خود، جو منہ میں سولہ دانت رکھتی ہوں، کتّوں سے کیوں خوف کھاتی ہوں۔ خیر کوئی بات نہیں ایک دانت کے چلے جانے کا کیا غم۔ جلد بازی میں حرکت کرنا خطرناک ہے اور جب تک چھری میری ہڈیوں تک نہیں جاپہنچتی، صبر اور خاموشی ہر چیز سے بہتر ہے۔
اسی اثنا میں قلعے سے باہر کا کوئی شخص گھومتا گھامتا وہاں آپہنچا۔ لومڑی کو دیکھا اور گویا ہوا: تعجب ہے، کیا یہ لومڑی مرچکی ہے؟ کتنا اچھا ہوا کہ میں یہاں چلا آیا۔ میرے شہر میں لوگ لومڑی کی دُم خریدتے ہیں اور اسے اپنے لباس پر مڑھ لیتے ہیں۔ بہت خوب، میں اس لومڑی کی دُم لے جاتا ہوں۔ یہ کہا اور چھری جیب سے نکالی کہ اس کی دُم کاٹ لے۔
لومڑی نے دل میں کہا: میں کس مصیبت میں آن پھنسی ہوں۔ یہ لوگ جب تک میرے جسم کی بوٹی بوٹی نہ کرلیں گے، ٹلیں گے نہیں۔ جب تک معاملہ میری پشم تک تھا، میں نے پروا نہ کی، جب بات میرے کان کی ہورہی تھی، میں نے پروا نہ کی اور سست اور ساکت پڑی رہی، جب میرا دانت لے اُڑنے کے لیے سوچا جارہا تھا، میں نے جی کڑا کر کے صبر سے کام لیا مگر اب جب چھری میری ہڈیوں تک پہنچنے کو ہے، صبر اور خاموشی ہر چیز سے بدتر ہے۔
مجھے چاہیے کہ اٹھوں اور خود کو نجات دلاؤں۔ اگر میں اب بھی یہاں پھنسی رہی تو میرے ساتھ بہت بُرا ہوگا۔ سو جونہی مذکورہ شخص چھری ہاتھ میں لیے نزدیک آیا، اچانک لومڑی نے جست لگائی اور لوگوں کے ٹانگوں اور پاؤں کے بیچ سے، جو اس کے اچانک حرکت کرنے سے وحشت زدہ ہوگئے تھے، نکلی اور قلعے سے فرار ہوگئی۔
(فارسی ادب سے کہانی جس کا اردو ترجمہ ڈاکٹر تحسین فراقی نے کیا ہے)