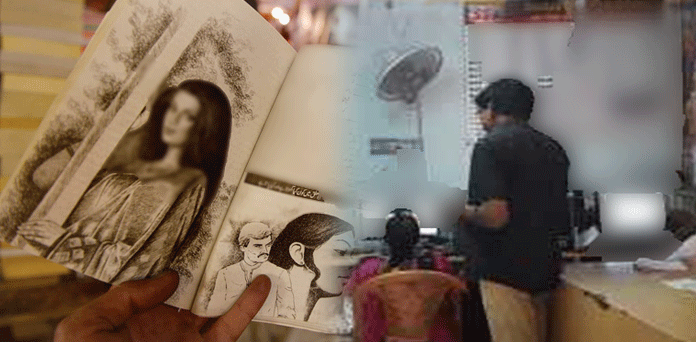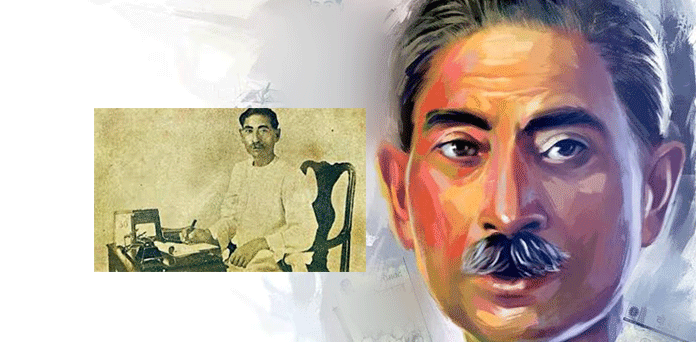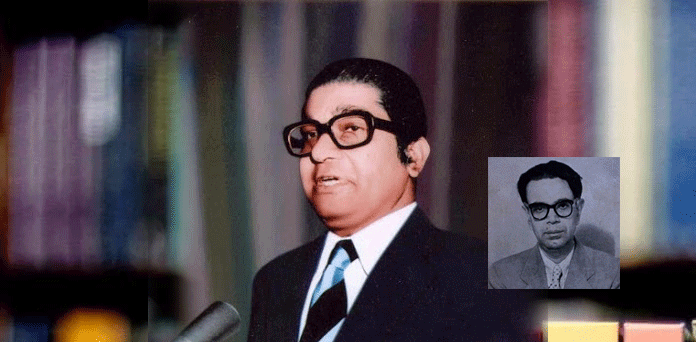پاکستان کی نام ور افسانہ و ناول نگار حجاب امتیاز علی تاج کی رومانی تحریریں بہت مقبول ہوئیں۔ ان کا نام اردو کی ایسی فکشن نگار کے طور پر لیا جاتا ہے جنھوں نے اپنی کہانیوں کو دل کش انداز سے لفظوں کا جامہ پہنایا اور بہت شہرت پائی۔
حجاب، اردو کے مشہور ڈرامہ نگار سید امتیاز علی تاج کی اہلیہ تھیں۔ دکن میں پیدا ہونے والی حجاب امتیاز علی تاج اپنے دور کی ایک روشن خیال اور تعلیم یافتہ خاتون تھیں۔ وہ ہندوستان کی پہلی مسلمان خاتون ہوا باز ہونے کا اعزاز بھی رکھتی ہیں۔ حجاب کی یہ کہانی حیرت انگیز اور تجسس آمیز ہے جس میں انھوں نے دو لڑکیوں اور ایک پروفیسر کو کردار بناتے ہوئے ایک طویل سفر طے کر کے دوسرے شہر میں قدیم مقام پر جاتے ہوئے پیش کیا ہے۔ اس شہر میں ان کا قیام ایک ایسی عورت کے گھر ہوتا ہے جس کا دس روز قبل انتقال ہوا ہے مگر اپنی منزل پر پہنچنے کے بعد وہی عورت ان کا استقبال کرتی ہے۔ کہانی پڑھیے!
مجھے ایک مدت سے سمرد کے کھنڈر دیکھنے کا اشتیاق تھا۔ اتفاق سے ایک دن باتوں باتوں میں میں نے اپنے شوق کا ذکر بوڑھے ڈاکٹر گار سے کیا۔ وہ سنتے ہی بولے، ’’اتنا اشتیاق ہے تو بیٹی وہاں کی سیر کو جاتی کیوں نہیں؟ تمہارے قیام کا انتظام میں کیے دیتا ہوں۔ مادام حمرہ دلی خوشی سے تمہیں اپنا مہمان بنائیں گی۔ کہو تو آج ہی انہیں خط لکھ دوں؟‘‘
’’مادام حمرہ کون ہیں؟‘‘ میں نے سوال کیا۔ بوڑھے ڈاکٹر گار نے نسوار کی ڈبیہ پتلون کی جیب سے نکالی اور اس پر انگلی مارتے ہوئے بولا،‘‘ تم مادام حمرہ کو نہیں جانتیں روحی؟ دو سال ہوئے یہ خاتون سمرد سے کوئی چالیس میل کے فاصلے پر کار کے حادثہ میں بری طرح زخمی ہوگئی تھیں۔ اتفاق کی بات اسی زمانہ میں ہماری پارٹی شکار کی غرض سے نکلی ہوئی تھی۔ خیمے قریب ہی لگے۔ رات کا وقت تھا۔ شہر دور تھا۔ ایک میں ہی وہاں ڈاکٹر تھا۔ اللہ نے وقت پر مجھے توفیق دی اور میں اس بچاری خاتون کو اپنے خیمے میں اٹھا لایا۔ چوٹیں سخت آئی تھیں مگر چار دن کی تیمار داری اور علاج نے خطرے سے باہر کردیا اور میں نے انہیں اپنی کار میں بٹھا کر ان کے گھر پہنچا دیا۔ وہ دن اور آج کا دن، ہمیشہ ان کا اصرار رہا کہ میں کچھ دن کو ان کے ہاں جاؤں اور ان کا مہمان رہوں مگر باوجود اس بچاری کی شدید اصرار کے میں ادھر اب تک نہ جا سکا۔ نہ کھنڈروں کی سیر کے لیے وقت نکال سکا۔ بیماری کی خدمت سے جو وقت بچتا ہے وہ مطالعہ کی نذر ہوجاتا ہے۔ اب یہ موقع اچھا پیدا ہوگیا۔ اپنی بجائے میں تمہیں بھیج دوں گا۔ انہیں خوشی ہوگی تمہاری ضرورت پوری ہو جائے گی۔‘‘
یہ سن کر میں بولی، ’’واقعی موقع تو اچھا ہے مگر ڈاکٹر اکیلی میں نہیں جاتی۔ بخدا مجھے لطف نہ آئے گا تم بھی ساتھ چلو۔‘‘ ڈاکٹر نے اپنے قدیم انداز میں صاف انکار کردیا ، ’’نہ بیٹی میرا جی نہیں چاہتا کون سوٹ کیس بھرے اور سفر کی زحمت اٹھائے۔‘‘ جسوتی برآمدے کے سر ے پر بیٹھی میوہ کھارہی تھی۔ یہ سن کر وہیں سے بولی، ’’سوٹ کیس میں بھر دوں گی پیارے گاری۔ آپ ضرور چلیں۔‘‘ جسوتی بچپن سے بوڑھے ڈاکٹر کو گاری گاری کہنے کی عادی ہے۔
ڈاکٹر گار نے تھوڑی دیر کے غور کے بعد اپنی عادت کے مطابق ارادہ بدل ڈالا، بولا، ’’تم لوگوں کی فرمائش ٹالتے ہوئے بھی طبیعت آزردہ ہوتی ہے تو پھر جسوتی! میرے سوٹ کیس تم کو بھرنے ہوں گے اور میری نسوارکی پڑیوں کی دیکھ بھال روحی تم کرو۔‘‘
بوڑھے ڈاکٹر کی اسی ایک گندی عادت سے مجھے نفرت ہے۔ مجھے نسوار کو چھونے سے بھی گھن آتی ہے مگر کیا کرتی اس وقت مطلب اپنا تھا۔ ناچار وعدہ کرلیا کہ نسوار کی پڑیوں کا اہتمام میں کر لوں گی۔ ڈاکٹر گار نے اسی وقت مادام حمرہ کو خط لکھ دیا کہ ہفتہ عشرہ میں ہم لوگوں سمیت وہاں پہنچ رہے ہیں۔ لیکن ڈاکٹر کے پاس بعض ایسے اہم کیس آتے رہے کہ خط لکھنے کے پندرہ دن بعد ہم اپنی سفر شروع کرسکے۔
اس روز میری محبوب اکلوتی سہیلی جسوتی اور ڈاکٹر گار ہم تینوں ڈاکٹر کی چھوٹی سی سفری کار میں چل پڑے۔ دن کی گرمی سے بچنے کے لیے رات کا کھانا کھا کر سفر شروع کیا گیا۔ پروگرام یہ بنا کہ سمرد کے راستے میں رات مادام حمرہ کے ہاں بسر کر کے ان کی خوشی پوری کریں اور دوسری صبح سمرد کے کھنڈروں میں پہنچ جائیں۔ یہ خبر نہ تھی کہ یہ رات زندگی کی نہایت خوفناک راتوں میں سے ایک ہوگی۔۔۔مالک کی پناہ!
ماہ مئی کی تپتی ہوئی چاندنی رات تھی۔ ہماری ننھی سی ’’ہیمنٹ لے‘‘ ویران سڑک پر کسی تیز رفتار کیڑے کی طرح چلی جارہی تھی۔ نو بج چکے تھے، خیال تھا کہ بارہ ساڑھے بارہ بجے تک ہم مادام حمرہ کے ہاں پہنچ جائیں گے۔ سڑک پر کوئی راہ گیر نہ تھا۔ زرد چاند موسم گرما کے شفاف آسمان پر دم بخود تھا۔ تاڑ کے فلک بوس چھتری نما درخت رات کی فسوں کاری سے مبہوت کھڑے تھے۔
جسوتی کار چلا رہی تھی۔ میں اس کے پہلو میں بیٹھی ٹافی کھا رہی تھی۔ بوڑھا ڈاکٹر بجھا ہوا سگار منہ میں دبائے غنودگی کے عالم میں پچھلی سیٹ پر پڑا تھا۔ غنودی سے چونکتا تو مزے میں آکر عمر خیام کی کوئی شوخ رباعی اپنی موٹی غیر شاعرانہ آواز میں گا دیتا۔ یہ اس کی مخصوص عادتوں میں سے ایک عادت تھی۔
دل فریب چاندنی تھی اور خوابناک سماں۔ دفعتاً جسوتی نے کار کھڑی کردی۔ ’’کیوں کیا ہوا؟‘‘ میں نے چاکو لیٹ کا ایک ٹکڑا نگلتے ہوئے پوچھا۔ وہ بولی، ’’کوئی خرابی روحی!‘‘ اور پھر سیٹ سے اترکر انجن کھول کر دیکھنے لگی۔ میں نے کہا، ’’ناممکن۔۔۔ اچھا ٹھہرو میں دیکھتی ہوں۔‘‘ یہ کہہ کر میں نے اپنا دستی بٹوہ ڈاکٹر گار کی گود میں پھینک دیا اور خود انجن کو دیکھنے لگی۔ آدھے گھنٹے کی مسلسل کوشش کے بعد ہم نے مایوس ہوکر ایک دوسرے کو تکا۔ ’’اب کیا ہوگا روحی؟‘‘ جسوتی نے کھسیانے لہجہ میں پوچھا۔
اسی وقت تاڑ کے دیو قد درخت پر تہذیب و تمدن سے نا آشنا صحرائی الو نے ایک وحشیانہ چیخ ماری۔ بھلا جسوتی کے کان جو ستار کی موسیقی اور محبت کی شیریں سرگوشیوں کے عادی تھے الو کی اس زیادہ کی تاب کب لاسکتے تھے وہ مارے خوف کے مجھ سے چمٹ گئی لیکن میں تو غیر ہموار زمینوں اور مہا ذری جیسے دشوار گزار پہاڑیوں کی سیاحت کی عادی ہوں۔ اس کی بزدلی پر اس کو ہمت دلائی۔ اتنے میں بوڑھا ڈاکٹر گار حافظ کا ایک عشقیہ شعر پڑھتا ہوا اٹھ بیٹھا اور پوچھنے لگا، ’’کیا ہم پہنچ گئے؟‘‘
کچھ دیر بعد پریشانی کے عالم میں ہم تینوں کار سے نیچے اتر آئے اور سراسمیگی سے ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ رات زیادہ گہری ہوتی چلی جاتی تھی۔ چاند کی زرد روشنی میں رات کا کوئی پرند اپنے بڑے بڑے بازو پھیلائے کسی سمت اڑتا تو ہم کسی راہ گیر یا گاڑی بان کے دھوکے میں اسی سمت تکنے لگتے۔ بہت دیر بعد دور سے بغیر چھت کے دیہاتی وضع کی ایک مضحکہ انگیز گاڑی آتی ہوئی نظر آئی۔ جسوتی نے اسے دیکھ کر غمگین لہجہ میں کہا، ’’اگر ہم دیر میں پہنچے تو وہ سوچکی ہوں گی۔ اس لیے اس گاڑی میں چلے چلو۔’’
گاڑی سڑک کے کنارے بے فکری سے چہل قدمی کرتی ہوئی چلی جارہی تھی۔ ڈاکٹر گار نے دور سے آواز دی، ’’بڑے میاں! ایوب محلہ میں عشرت خانہ نامی کوٹھی تک ہمیں پہنچا دو گے؟‘‘ گاڑی بان نے بغیر ہماری طرف دیکھے دیہاتیوں کے سے اکھڑ لہجہ میں جواب دیا، ’’نہیں بارہ بج گئے ہیں۔ دیر ہوگئی ہے۔‘‘
یہ بد تہذیب اور ٹکا سا جواب سن کر بہت ہی غصہ آیا۔ ضبط کر کے میں اور جسوتی اس کے پاس گئیں۔ وہ ہمارے بیش قیمت زریں لباس اور باوقار چہرے کو دیکھ کر گاڑی سے نیچے اُتر آیا۔ ’’یہ لو۔۔۔‘‘ میں نے جاتے ہی چاندی کا ایک چمکدار سکہ اس کے ہاتھ میں رکھ دیا اور بولی، ’’اب ہمیں جلدی سے عشرت خانہ تک پہنچا دو۔‘‘ وہ مرعوب ہوگیا اور مؤدب لہجہ میں بولا، ’’سوار ہوجائیے حضور دو گھنٹوں میں پہنچا دوں گا۔‘‘
گاڑی کے پائیدان پر قدم رکھا تو ایسا معلوم ہوا کہ گاڑی سر پر آرہے گی۔ اس لیے فوراً میں نے اس کی چھت تھام لی۔ جسوتی نے اس کے پہیے کو مضبوطی سے پکڑ کر گاڑی پر قدم رکھا۔ غرض ہم تینوں چڑھ کر بیٹھ گیے۔ اب گاڑی چلی جارہی تھی۔ آہستہ آہستہ جیسے کسی جاں بلب مریض کا سانس چل رہا ہو۔ چاند زرد پڑ گیا تھا۔ ہواؤں میں خوفناک سرسراہٹ پیدا ہوگئی تھی۔
بوڑھا ڈاکٹر گار گاڑی کے ہچکولوں سے ناخوش اور چڑا ہوا معلوم ہوتا تھا۔ ہم دونوں گرمی سے نڈھال ہاتھوں میں خس کی زریں پنکھیاں لیے جن کی ڈنڈیاں خوشبودار صندل کی لکڑی کی تھیں، بار بار بے کلی سے پہلو بدل رہی تھیں۔ آہ! اللہ وہ گرم اور ویران چاندنی رات! سانس آگ کے شعلوں کی طرح ناک سے نکلتا تھا۔ زبان سوکھے پتوں کی طرح خشک تھی۔ جسوتی رہ رہ کر اپنی پری کی وضع کی چھوٹی سی نقرئی صراحی سے پانی انڈیل انڈیل کر پی رہی تھی۔ مشرقی ممالک کی یہ وہی گرم رات تھی جس کے متعلق ہمارے ان ایشیائی ممالک میں مشہور ہے کہ سبز چشم پریاں بھی اپنی آبی دنیا سے باہر نکل آتی ہیں۔
دور سے ایک سفید شاندار عمارت نظر آنے لگی۔ پھر یک لخت بوڑھا ڈاکٹر گار گاڑی بان پر اور میں جسوتی پر جا پڑی اور اس طرح ہماری مضحکہ خیز گاڑی ایک جھٹکے ساتھ عشرت خانہ کے شاندار پھاٹک میں مڑگئی۔ میں نے رونے کے لہجہ میں کہا، ’’ایسی بھدی گاڑی میں اپنے میزبان کے سامنے جاتے ہوئے میں تو زمین میں گڑ جاؤں گی۔‘‘ اس پر بوڑھے ڈاکٹر گار نے کہا، ’’مگر روحی! اس میں شرم کی کیا بات ہے؟ وہ کیا سمجھ نہ جائیں گی کہ مجبوری کو اس گاڑی میں سوار ہونا پڑا ہوگا۔‘‘ جسوتی نے کہا، ’’نہ نہ جتنی جلدی ہوسکے اس کو واپس کردو۔‘‘
چاندنی کی سفید دھاریاں خوش قطعے اور تنگ روشوں پر پڑی ہوئی تھیں۔ ہماری گاڑی صدر دروازے پر جاکر لگ گئی۔ ہم نے فوراً اسے واپس کردیا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھ کر کہا ، ’’یہاں کی دنیا تو خواب میں ملفوف نظر آتی ہے۔ چوکیدار کا بھی پتہ نہیں۔‘‘ جسوتی نے کہا، ’’کہ کون جانے مادام حمرہ یہاں ہیں یا نہیں۔‘‘ ڈاکٹر کہنے لگا، ’’ہوں گی کیوں نہیں؟ انہوں نے میرے خط کا جواب دیا تھا کہ میں دلی اشتیاق سے آپ سب کی آمد کی منتظر رہوں گی۔‘‘
ہم نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ پہلے احتیاط سے آہستہ آہستہ پھر کچھ دیر بعد زور زور سے۔ مکان کا طواف کیا۔ نوکروں کو پکارا۔ چوکیدار کو آوازیں دیں۔ غرض جتنی کوششیں ہوسکتی تھیں کرلیں مگر زرد چاندنی میں سفید مرمریں محرابوں والا عالی شان محل ساکت کھڑا رہا۔ وسیع برآمدوں میں لمبے لمبے ستونوں کا عکس چاندنی میں ترچھا پڑ رہا تھا۔ چنبیلی کی بیل میں جھینگر اپنا نغمۂ تنہائی الاپ رہا تھا۔
جب مایوس ہوکر ہم لوگ زینے سے اترنے لگے تو اچانک اندر کسی کمرے سے ایک ایسی آواز آئی جیسے کسی نے دیا سلائی جلائی ہو۔ ڈاکٹر گار نے چونک کر کہا، ’’ٹھہرو۔ میرا خیال ہے کہ کوئی جاگ اٹھا۔‘‘ ہم تینوں پھر زینے طے کر کے دروازے کے پاس اس امید میں جا کھڑے ہوئے کہ اب کھلتا ہے اور اب کھلتا ہے۔ اندر سے کبھی کبھی کوئی خفیف سی آواز آجاتی تھی۔ پانچ منٹ اسی حالت میں گزر گئے۔ ہم بند دروازے پر نظریں گاڑے کھڑے رہے۔
آخر ڈاکٹر نے حیران ہوکر کہا، ’’یہ کیا بات ہے؟‘‘ میں نے شیشوں میں سے اندر جھانکنے کی کوشش کی۔ وہاں سوائے تاریکی کے کچھ نہ تھا۔ ڈاکٹر بیزار ہو کر چلایا ، ’’ارے بھئی یہاں کوئی ہے بھی؟‘‘ اس کے چلانے کا اثر یہ ہوا کہ اندر پھر کچھ گڑبڑی سی ہونے لگی۔ دو لمحہ بعد دروازہ یکایک اس زور سے کھلا کہ ہماری تو آنکھیں بند ہوگئیں۔ اس کا کھلنا تھا کہ تیز و تند ہوا کا ایک سرد جھونکا اچانک ہمارے گرم چہروں سے یوں آکر لگا جیسے کسی نے تھپڑ مارا ہو۔ میری تو آنکھیں بند ہوگئیں اور ساتھ ہی ہم تینوں کھڑے کھڑے کانپ سے گئے لیکن دروازہ کے سامنے جو موجود کوئی نہ تھا۔ ڈاکٹر گار حیران اور پریشان ہوکر بولا، ’’یہ دروازہ کھولا کس نے؟‘‘
اندر کی ویران تاریکی میں داخل ہونے کی ہمت نہ ہوتی تھی۔ ڈاکٹر نے ایک قدم اندر رکھا تھا کہ جسوتی نے اسے روک دیا۔ بیزار ہو کر ہم نے پھر باغ کی طرف جانے کا ارادہ کیا۔ یک لخت پھر اندر کے کسی دروازے کے پٹ سے کھلنے کی آواز آئی اور ساتھ ہی سرد اور تند ہوا کا جھونکا ایک بار پھر ہم تک پہنچا۔ دیکھتے ہی دیکھتے تاریکی میں ایک ہلکی سی روشنی نظر آنے لگی جو بتدریج موم بتی میں تبدیل ہوگئی۔ ہم نے نگاہ موم بتّی سے ذرا اوپر اٹھائی تو اٹھائیس انتیس سالہ ایک حسین اور دلفریب خاتون نظر آئی جس نے نہایت سادہ اور سفید لمبے لمبے لرزاں دامنوں کا لباس پہن رکھا تھا۔ موم بتی اس کے ہاتھ میں تھی۔ ڈاکٹر گار کو دیکھ کر وہ مسکرائی اور سر جھکایا۔ ’’مزاج شریف مادام حمرہ۔۔۔ یہ دونوں لڑکیاں میری ہیں، انہیں کا ذکر میں نے خط میں کیا تھا۔‘‘ خاتون حمرہ نے نہایت دلکش انداز میں ہماری طرف دیکھ کر خیر مقدم کے طور پر سر جھکایا۔
پھر ایک لمحہ بعد بغیر کوئی بات کیے انہوں نے اشارے سے ہمیں اپنے پیچھے بلایا اور روشنی دکھاتے ہوئے خود سامنے چلنے لگیں۔ ایک بل کھائے ہوئے ناگ کے پھن پر موم بتی جل رہی تھی۔ ہوا سے ان کے لمبے لمبے دامن ان کے پیچھے دو ردور تک لہرا رہے تھے۔ چال ایسی تھی جیسے کوئی پری ہوا میں تیر رہی ہو۔ سیاہ بال سفید ریشمی چادر کے نیچے ہوا کی شوخیوں سے لہرا رہے تھے۔ چہرے پر حوروں کی سی مسکراہٹ تھی۔
اسی وقت جسوتی نے سرگوشی کی، ’’روحی! یہاں کیسی خنک ہوا چل رہی ہے، باہر تو سڑکوں پر لو کی تکلیف دہ لپٹوں سے ہمارے چہرے گرم ہورہے تھے۔‘‘ جسوتی کا فقرہ ختم ہوا ہی تھا کہ ہم ایک عالی شان محل میں پہنچے جہاں ایک سیاہ لمبی اعلیٰ پالش شدہ چمکدار میز پر انواع اقسام کے پھل برگ نما نقرئی طشتوں میں سجے ہوئے تھے۔ دل کی شکل کی ننھی کٹوریوں میں شربت رکھا ہوا تھا۔ میز کے اوپر چھت میں کنول کے پھولوں کی وضع کے فانوس آویزاں تھے۔ دروازوں پر ارغوانی رنگ کے زریں پردے لگے ہوئے تھے۔ دیواروں پر کسی قدیم جنگ چین کے مناظر لٹک رہے تھے۔
مادام حمرہ نے اپنی سانپ کی شکل کا شمع دان میز پر رکھ دیا اور خود سرے والی میز پر بیٹھ گئیں۔ ’’لیکن!‘‘ ڈاکٹر گار نے کہا، ’’میری پیاری مادام۔۔۔ رات کے دو بجے ایسی لذیذ میز سے کوئی کس طرح لطف اندوز ہوسکتا ہے؟ اس وقت تو ایک نرم آرام دہ بستر عنایت ہوجائے تو بڑی مہربانی ہوگی۔‘‘
یہ سنتے ہی مادام حمرہ بغیر کسی قسم کا کوئی لفظ منہ سے نکالے اٹھ کھڑی ہوئیں۔ کھانے کے لیے مطلق اصرار نہ کیا۔ اپنا وہی ناگ کی وضع کا شمع دان اٹھا لیا اور مسکرا کر گردن کے اشارے سے ہمیں اپنے پیچھے پیچھے آنے کو کہا۔ ایک پرتکلف خواب گاہ میں جہاں مدھم روشنیوں کے نیچے نفیس اور رنگین ریشمی بستر بچھے ہوئے تھے لے گئیں۔ یہاں پہنچ کر سر کے اشارے سے ہمیں شب بخیر کہا اور چپ چاپ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی ہوئی اسی طرح باہر چلی گئیں۔
میں ایک کمزور دل کی وہمی عورت ہوں۔ اپنی میزبان کی ان حرکات نے میرا خون خشک کر دیا تھا۔ چنانچہ ان کے کمرے سے باہر جاتے ہی میں نے ڈاکٹر گار کا ہاتھ تھام لیا اور بولی، ’’یہ بات کیوں نہیں کرتیں؟‘‘ گار بولا، ’’میں خود حیران ہوں نہ جانے کیا معاملہ ہے؟‘‘
’’یہاں سے بھاگ چلو ڈاکٹر۔‘‘ میں نے بیزار لہجہ میں کہا۔ جسوتی بولی، ’’ان کی کیسی میٹھی شکل ہے۔ پر کہیں گونگی تو نہیں؟‘‘ ڈاکٹر گار نے کہا ’’نہیں بیٹی! نہیں! وہ بے حد باتونی ہیں۔‘‘ میں سوچتے ہوئے بولی، ’’باوجود ان کے حسن کے انہیں دیکھ کر مجھے دہشت سی محسوس ہوتی ہے۔‘‘
ڈاکٹر گار اپنے کمرے میں چلا گیا۔ جسوتی اور میں اس راز کو سلجھانے کی کوشش کرتی ہوئی کوئی تین بجے کے قریب اپنی اپنی چارپائیوں پر لیٹ گئیں۔ صبح کی عبادت کے وقت عادتاً میری آنکھ کھل گئی۔ پروگرام کے مطابق آٹھ بجے ہمیں سمرد کے کھنڈروں کی طرف روانہ ہوجانا تھا اس لیے میں نے جسوتی کو بھی جگا دیا۔ ہم دونوں نے نماز پڑھی۔ صبح گرم اور خوشگوار تھی۔ نماز کے بعد سامنے چنبیلی کی بیلوں میں بیٹھ کر بہت دیر تک چائے کا انتظار کیا۔ مگر جب مایوسی ہوئی تو میں ڈاکٹر گار کے کمرے میں گئی اور بولی، ’’ڈاکٹر! ابھی تک سورہے ہو؟‘‘ وہ بولے، ’’چائے کے انتظار میں پڑا ہوں روحی۔ چائے آجائے تو اٹھوں۔ ذرا وہ نسوار کی ڈبیا پکڑا دینا۔ شکریہ۔‘‘ نوبج گئے اور کسی نے خبر نہ کی تو میں نے کہا، ’’چلیے ڈاکٹر ذرا باہر نکل کر دیکھیں۔ چائے یا کوئی خادمہ کیوں نہیں آتی؟‘‘
ڈاکٹر گار نے جلدی جلدی کپڑے پہن لیے۔ ہم تینوں وسیع برآمدے سے گزر کر بڑے ہال میں آئے۔ تمام دروازے بند تھے۔ ہر طرف سناٹا اور ویرانی تھی۔ بیش قیمت فرنیچر پر گرد تھی۔ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ کوٹھی کئی روز سے بند پڑی ہے۔ ہم نے ڈرتے ڈرتے کھنکھار کر آہٹ کر کے ایک ایک کمرے کو کھولا لیکن ہر کمرہ خالی تھا۔ ہر کمرے کے سامان کی یہ حالت تھی جیسے برتا نہیں جاتا۔ سنگو کر رکھ دیا گیا ہے۔ ساری کوٹھی دیکھ ڈالی۔ اس میں کہیں کوئی متنفس نہ تھا۔ ہمارے دلوں پر دہشت ایک بوجھ کی طر ح بیٹھنے لگی۔ پریشان ہوکر باہر باغ میں نکل آئے۔ سمجھ میں نہ آتا تھا کہ یہ راتوں رات کیا ہوگیا۔۔۔ نوکر کدھر ہیں؟ مادام حمرہ کہاں غائب ہوگئیں۔
دس بجنے آگئے۔ ہم پریشانی کے عالم میں اس ویران گھر کے زینے پر کھڑے سوچ رہے تھے کہ کیا کریں؟ اتنے میں دیکھا کہ بوڑھا ملازم باغ سے ہوکر اندر آیا اور چپ چاپ ایک کمرے میں داخل ہوگیا پھر اس نے فرنیچر نکال کر باہر رکھنا شروع کردیا۔ ساتھ ہی ساتھ وہ زور زور سے روتا بھی جارہا تھا۔ ہم لوگ تیزی سے اس کی طرف گئے۔ وہ ہمیں دیکھ کر ٹھٹک سا گیا اور پھر حیران ہوکر ہمارا منہ تکنے لگا۔ ڈاکٹر گار نے پوچھا، ’’مادام حمرہ کہاں ہیں؟‘‘
بوڑھا متعجب ہوکر دیوانوں کی طرح ڈاکٹر کا منہ تکنے لگا۔ ڈاکٹر گار نے پھر کہا ’’ہم ان کے مہمان ہیں۔ مادام حمرہ کہاں گئیں؟‘‘ بوڑھے نے حیران ہوکر کہا، ’’مادام حمرہ۔۔۔؟ آہ حضور بیگم صاحبہ کو تو سانپ نے ڈس لیا۔ ان کے انتقال کو آج پورے دس دن ہوگئے۔ آج گھر کا سامان نیلام ہونے والا ہے۔‘‘ یہ سنتے ہی میں نے جسم میں ایک پھریری سی محسوس کی۔ رات کا وہ پراسرار سرد ہوا کا جھونکا پھر ایک دفعہ مجھے قریب محسوس ہونے لگا اور میں بید مجنوں کی طرح کانپنے لگی۔ اس کے بعد مجھے مطلق یاد نہیں کہ کیا ہوا تھا؟