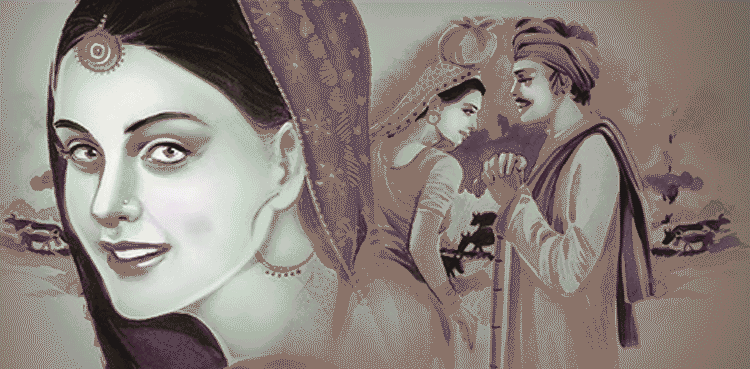آج سے دو ہزار سال پہلے پمپیائی سلطنت روم کا ایک نہایت خوبصورت شہر تھا۔ اس شہر کے باہر ایک آتش فشاں پہاڑ تھا جسے ویسوَیس کہتے تھے۔ پمپیائی کے باشندے بڑے عیّاش اور بد کار لوگ تھے۔ اُن میں نیکی اور خدا ترسی نام کو یہ تھی۔ طاقت ور کم زوروں کو بے گناہ مار ڈالتے۔ ساہوکار اور مال دار غریبوں کا خون چوستے اور اس طرح اُنہوں نے اپنے گھروں میں بے شمار سونا چاندی جمع کر لیا تھا۔
آخر جب ان لوگوں کے گناہ حد سے زیادہ ہو گئے تو اُن پر خدا کا عذاب نازل ہوا۔ ایک روز آتش فشاں پہاڑ پھٹ گیا اور اُس میں سے پگھلتا ہوا سرخ لاوا پانی کی طرح بہہ نکلا۔ پمپیائی پر آگ کے شعلوں کی بارش ہوئی اور سارا شہر ایک خوف ناک زلزلے سے تھوڑی ہی دیر میں خاک کا ڈھیر بن کر رہ گیا۔ یہ کہانی جو ہم تمہیں سنا رہے ہیں اِسی پمپیائی سے تعلّق رکھتی ہے۔
ٹیٹو اور اُس کا کُتّا بمبو، شہر کی فصیل کے باہر رہا کرتے تھے۔ قریب ہی بڑا دروازہ تھا، جس کے راستے باہر کے لوگ شہر میں جاتے تھے۔ ٹیٹو اور بمبو یہاں سونے کے لیے آتے تھے۔ اُن کا یہاں گھر نہ تھا۔۔۔ اُن کا گھر تو کہیں بھی نہ تھا۔ وہ جہاں چاہتے، چلے جاتے اور جس جگہ جی چاہتا سو جاتے۔ شہر میں ہر وقت دھماچوکڑی مچی رہتی تھی۔ میدانوں میں مختلف کھیل تماشے ہوتے رہتے۔ اسٹیڈیم میں جنگی کھیل دکھائے جاتے۔ غلاموں کی آپس میں لڑائیاں کرائی جاتیں اور کبھی کبھی بھُوکے شیروں سے بھی لڑوایا جاتا۔
سال میں ایک مرتبہ روم کا بادشاہ پمپیائی آیا کرتا تھا۔ اس کی آمد پر شہر میں کئی روز تک خوشیاں منائی جاتیں اور خوب جشن ہوتے لیکن بے چارہ ٹیٹو ان کھیل تماشوں کو نہیں دیکھ سکتا تھا وہ اندھا تھا۔ شہر کے کسی باسی کو معلوم نہ تھا کہ اُس کے ماں باپ کون تھے؟ اس کی عمر کیا ہے اور کہاں سے آیا ہے۔ اس بھری دنیا میں اُس کا ہمدرد اور غم خوار صرف بمبو تھا اور وہ ہمیشہ اُس کے ساتھ رہا کرتا تھا۔ لیکن دن میں تین مرتبہ ایسا ہوتا کہ وہ اپنے دوست کو کسی محفوظ جگہ چھوڑ کر چلا جاتا اور تھوڑی دیر بعد منہ میں روٹی یا گوشت کا ٹکڑا دبائے واپس آ جاتا۔ پھر دونوں مِل بانٹ کر کھا لیتے اور خدا کا شکر ادا کرتے۔
کُتّے کی بدولت ٹیٹو کو دِن میں تین وقت کھانا مِل جایا کرتا تھا اور کبھی فاقے کی نوبت نہیں آئی تھی لیکن اِس کے باوجود وہ ہر وقت اُداس سا رہتا تھا۔ وہ پمپیائی کی گلیوں میں بچّوں کو بھاگتے دوڑتے ہوئے سُنتا، کبھی وہ آنکھ مچولی کھیلتے اور کبھی چور اور بادشاہ کا کھیل۔ اُن کے اچھلنے کودنے کی آوازیں ٹیٹو کے کانوں میں پہنچتیں تو اُس کا دل چاہتا کہ وہ بھی اُن کے ساتھ کھیلے لیکن وہ ایسا نہ کر سکتا تھا۔ وہ تو ایک بے سہارا، غریب اور اندھا لڑکا تھا اور سوائے ایک کتّے کے اُس کا کوئی دوست نہ تھا۔ خدا نے اگرچہ اُسے آنکھوں کی روشنی سے محروم کر دیا تھا لیکن سننے، سونگھنے اور چُھو کر محسوس کرنے کی قوّتیں دگنی دے دی تھیں۔ وہ انہی قوّتوں کی بدولت ان چھوٹی چھوٹی باتوں سے بھی واقف ہو جاتا جو دوسرے لوگ آنکھیں رکھنے کے باوجود معلوم نہ کر سکتے تھے۔
جب دونوں دوست شہر کی سیر کے لیے نکلتے تو ٹیٹو ارد گرد کی آوازیں سن کر صحیح اندازہ لگا سکتا تھا کہ یہاں کیا ہو رہا ہے۔
پمپیائی کی اکثر عمارتیں بالکل نئی تھیں کیونکہ بارہ سال پہلے یہاں ایک زلزلہ آیا تھا جس سے بہت سی عمارتیں گِر گئی تھیں۔ لیکن تھوڑے ہی دنوں بعد لوگوں نے سارا شہر گِرا کر اُسے دوبارہ تعمیر کیا جو پہلے سے بھی زیادہ خوب صورت شہر بن گیا اور نیپلز اور روم جیسے عالی شان شہروں کا مقابلہ کرنے لگا۔
پمپیائی کے کسی باشندے کو معلوم نہ تھا کہ زلزلہ کیوں آتا ہے۔ ملّاح کہا کرتے تھے کہ زلزلہ آنے کا سبب یہ ہے کہ شہر کے لوگ ملّاحوں کی عزّت نہیں کرتے۔ ملّاح سمندر پار سے اُن کے لیے کھانے پینے کی چیزیں لاتے ہیں اور سمندری ڈاکوؤں سے بھی اُن کو محفوظ رکھتے ہیں۔ مندروں کے پُجاری کہا کرتے تھے کہ زلزلہ آنے کی وجہ آسمانی دیوتاؤں کی ناراضگی ہے کیونکہ لوگوں نے عیش و عشرت میں پڑ کر عبادت کرنی چھوڑ دی ہے اور وہ دیوتاؤں کے لیے قربانیاں بھی نہیں کرتے۔
شہر کے تاجر کہتے تھے کہ باہر سے آنے والے تاجروں کی بے ایمانیوں نے شہر کی زمین کو ناپاک کر دیا ہے اور اِسی لعنت کی وجہ سے زلزلہ آتا ہے۔ غرض، جتنے مُنہ، اتنی باتیں۔ ہر شخص اپنی بات زور زور سے کہتا اور اُسے منوانے کی بھی کوشش کرتا۔
اُس روز بھی دوپہر کو جب ٹیٹو اور بمبو بڑے چوک میں سے گزر رہے تھے، شہر کے لوگ اِسی قسم کی باتیں کر رہے تھے۔ چوک لوگوں سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا اور کان پڑی آواز سُنائی نہ دیتی تھی۔ لیکن ٹیٹو کے کان بڑے تیز تھے۔ ایک جگہ وہ ٹھٹک کر کھڑا ہو گیا۔ دو آدمی آپس میں بحث کر رہے تھے اور اُن کے گرد بھیڑ لگی ہوئی تھی۔ اُن میں سے ایک کی آواز بھاری تھی اور دوسرے کی ہلکی مگر تیز۔ بھاری آواز والا کہہ رہا تھا ’’میں کہتا ہوں اب یہاں کوئی زلزلہ نہیں آئے گا۔ تُم نے سُنا نہیں کہ آسمانی بجلی کی طرح زلزلہ بھی جہاں ایک بار آ جائے، دوبارہ نہیں آیا کرتا۔‘‘
’’تمہارا خیال غلط ہے۔‘‘ ہلکی آواز والے نے کہا۔ ’’تمہیں معلوم نہیں کہ پندرہ برس کے اندر سسلی میں دو مرتبہ زلزلہ آیا تھا؟ بھلا بتاؤ تو ویسوَیس پہاڑ دھواں کیوں اُگلتا رہتا ہے؟ کیا اس کا کوئی مطلب نہیں؟‘‘
یہ سُن کر بھاری آواز والا آدمی قہقہہ مار کر ہنس پڑا اور بولا۔ ’’ارے بھائی! یہ دھواں تو ہمیشہ سے نکلتا ہے اور سچ پُوچھو تو یہ دھواں ہمارے لیے ہے بھی بڑا مفید۔ ہم اس سے موسم اور ہوا کا رُخ پہچان لیتے ہیں۔ اگر دھواں سیدھا آسمان کی طرف جائے تو ہم سمجھ لیتے ہیں کہ موسم صاف رہے گا اور جب اِدھر اُدھر پھیلنے لگے تو اِس مطلب ہوتا ہے کہ آج کُہر پڑے گی۔ اگر دھواں مشرق کی طرف۔۔۔‘‘
’’اچھّا۔ اچھّا۔ بس کرو۔ میں سمجھ گیا جو تم کہنا چاہتے ہو۔‘‘ ہلکی آواز والے نے بات کاٹ کر کہا۔ ’’ہمارے یہاں ایک کہاوت مشہور ہے کہ جو لوگ انسان کی نصیحت پر عمل نہیں کرتے انہیں دیوتا سبق دیتے ہیں۔ اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہوں گا لیکن میں تمہیں ایک تنبیہ ضرور کرتا ہوں کہ جب آتش فشاں پہاڑ کا دھواں آسمان پر گھنے درخت کی صورت اختیار کر لے تو اُس وقت تم لوگ اپنی جان بچانے کی فکر کرنا! یہ کہہ کر وُہ چلا گیا۔
ٹیٹو اُن کی یہ گفتگو سُن کر بُہت حیران ہوا۔ بمبو کتّے کا بھی یہی حال تھا۔ وہ اپنی گردن، ایک طرف جھکائے کچھ سوچ رہا تھا۔ لیکن رات ہوتے ہوتے لوگ یہ باتیں بھول بھال گئے اور اس جشن میں شامل ہو گئے جو روم کے بادشاہ سیزر کی سالگرہ کی خوشی میں منایا جا رہا تھا۔
دوسرے دِن صبح کو بمبو ایک بیکری سے دو میٹھے کیک چرا کر لایا۔ ٹیٹو ابھی تک سو رہا تھا۔ بمبو نے زور زور سے بھونک کر اسے جگایا۔ ٹیٹو نے ناشتا کیا اور پھر سو گیا، کیونکہ رات کو بہت دیر سے سویا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد بمبو نے اُسے پھر اٹھا دیا۔ ٹیٹو نے اٹھ کر جمائی لی تو ایسا لگا جیسے فضا بہت گرم ہے۔ اسے ایک گہری دھند چاروں طرف پھیلتی ہوئی محسوس ہوئی جو سانس کے ذریعے اُس کے پھیپھڑوں میں جا رہی تھی۔ وہ کھانسنے لگا اور سمندر کی ٹھنڈی ہوا میں سانس لینے کے لیے وہاں سے اٹھا لیکن تھوڑی ہی دور جا کر اسے محسوس ہوا کہ ہوا بے حد گرم اور زہریلی ہے۔ اُس کی ناک میں عجیب سی بُو آ رہی تھی۔ بمبو اُس کی قمیص پکڑ کر کھینچ رہا تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے وہ اُسے اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہے۔ لیکن کہاں؟ ٹیٹو یہ نہ سمجھ سکا۔ گرم ہَوا کے جھونکے بار بار اُس کے چہرے سے ٹکراتے تھے۔ اُس نے محسوس کیا کہ یہ ہوا نہیں بلکہ گرم راکھ ہے جو بارش کی طرح چاروں طرف برس رہی ہے۔ یہ راکھ اتنی گرم تھی کہ ٹیٹو کے بدن کی کھال جلی جا رہی تھی۔
اچانک اُس کے کانوں میں عجیب طرح کی ڈراؤنی آوازیں آنے لگیں۔ جیسے ہزار ہا وحشی درندے زمین کے نیچے دبے ہوئے چلّا رہے ہوں۔ پھر بہت سے لوگوں کے رونے اور چیخنے کی آوازیں سنائی دیں۔ اب زمین درخت کے پتّے کی طرح کانپ رہی تھی اور گرج دار آوازوں سے کلیجا بیٹھا جاتا تھا۔ وہ دونوں بے تحاشا ایک طرف کو بھاگنے لگے۔
شہر کی طرف سے آنے والی آوازیں اور ڈراؤنی ہو گئی تھیں۔ پہاڑ گرج رہا تھا، زمین ہل رہی تھی، عمارتیں دھڑا دھڑ گِر رہی تھیں اور لوگ پتّھروں کے تلے دبے چیخیں مار رہے تھے۔ جو بچ گئے تھے وہ بے تحاشا سمندر کی طرف بھاگ رہے تھے تا کہ کشتیوں میں بیٹھ کر کِسی محفوظ مقام پر پہنچ جائیں۔
ٹیٹو اور بمبو بھی ایک طرف کو بھاگے جا رہے تھے۔ ٹیٹو زخموں سے نڈھال ہو چکا تھا۔ آگ کے شعلوں اور راکھ سے اُس کا سارا بدن جھلس گیا تھا۔ بمبو نے منہ میں اُس کی قمیص کا دامن پکڑ رکھا تھا اور اُسے اپنے ساتھ گھسٹتے لیے جا رہا تھا۔ آخر وہ اُسے لوگوں کے ہجوم سے بچاتا ایک محفوظ جگہ پر لے گیا اور یہاں وہ دونوں پتھروں کی آڑ میں بیٹھ گئے۔
دوپہر ہو گئی۔ تکلیف، بھوک اور پیاس کے مارے ٹیٹو کا بہت بُرا حال تھا۔ اس نے بمبو کو پُکارا: ’’بمبو۔۔۔ بمبو۔۔۔!‘‘ لیکن بمبو وہاں نہیں تھا۔ اتنے میں ایک آدمی بھاگتا ہوا ٹیٹو کے پاس سے گزرا۔ اُس نے اندھے لڑکے کو اِس حال میں دیکھا تو اُسے جھپٹ کر گود میں اُٹھا لیا اور ایک کشتی میں جا کر بٹھا دیا۔ ملّاحوں نے پوری قوّت سے چپّو چلانے شروع کر دیے۔ ٹیٹو برابر اپنے کّتے کو آوازیں دیے جا رہا تھا۔ ’’بمبو!۔۔۔ بمبو!۔۔۔ میرے دوست! تم کہاں ہو؟‘‘ آخر روتے روتے اُس کی ہچکی بندھ گئی اور وہ نڈھال ہو کر کشتی میں لیٹ گیا۔
اٹھارہ سو سال بعد۔۔۔ سائنس دانوں کی ایک جماعت پمپیائی کا سراغ لگانے کے لیے اس جگہ پہنچی جہاں صدیوں سے یہ شہر مٹّی کے نیچے دبا ہوا تھا۔ مزدوروں نے زمین کھودی تو اُس کے نیچے سے کھنڈر نکلے۔ سارا شہر برباد ہو چکا تھا۔ بڑے بڑے محل اور عالی شان عمارتیں خاک کا ڈھیر ہو چکی تھیں۔ بازاروں میں قیمتی چیزیں اور سونے چاندی کے زیورات بھرے پڑے تھے۔ انسانوں کے ہزاروں ڈھانچے بھی نظر آئے۔ ایک روز کھدائی کے دوران ایک عجیب چیز بر آمد ہوئی۔ یہ ایک کتّے کا ڈھانچا تھا۔
ایک شخص حیرت سے بولا۔ ’’ارے! اس کتّے کے منہ میں کیا چیز ہے؟‘‘ اور پھر غور سے دیکھا گیا تو وہ ایک روٹی کا ایک بڑا سا ٹکڑا تھا۔
سائنس دانوں نے کہا۔ ’’یہاں ایک نانبائی کی دکان تھی۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ کُتا زلزلے کے وقت روٹی چرانے نکلا تھا مگر بے چارہ دب کر مر گیا۔‘‘
کاش انہیں معلوم ہوتا کہ بے چارہ بمبو کس کے لیے روٹی چرانے گیا تھا!
(از مقبول جہانگیر)