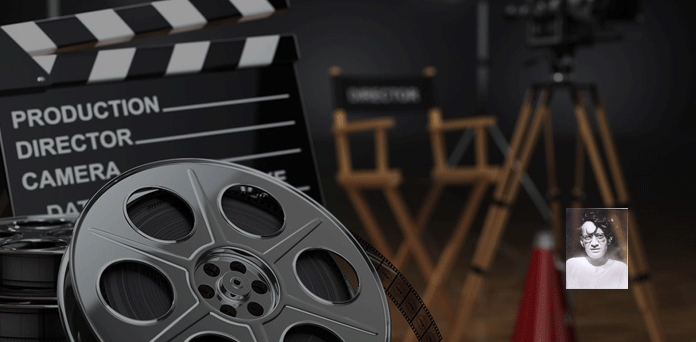انسان نے جب اپنی عقل اور سوجھ بوجھ سے کام لے کر زمین پر اپنے ہی جیسے دوسرے انسانوں سے اپنا مافی الضمیر بیان کرنا چاہا تو ابتداً لکیروں اور مختلف نشانیوں کا سہارا لیا اور پھر تصویریں بنانے لگا پھر تحریر کا سلسلہ شروع ہوا۔ آج اگر ہم بیرونِ ملک جائیں یا ایسے مقام پر ہوں جہاں کوئی ہماری مادری زبان نہ سمجھتا ہو تو اپنی بات اسے سمجھانا کتنا مشکل ہوگا، اس کا اندازہ آپ کر ہی سکتے ہیں۔
اردو ادب اور مشاہیر سے متعلق تحریریں پڑھیں
عطاء اللہ پالوی اردو کے ایک ایسے نثر نگار گزرے ہیں جنھوں نے علمی و ادبی موضوعات پر کئی مضامین اور کتب یادگار چھوڑی ہیں جو مصنف کے فلسفیانہ اور تنقیدی شعور کے ساتھ مذہبی رجحان، قرآن فہمی اور دینی تعلیمات میں غور و فکر کا نمونہ ہیں۔ وہ ایک صاحبِ مطالعہ ادیب تھے اور تاریخ و مذہب، سوانح و ادبی تذکرہ نویسی میں پہچان بنائی۔ وہ 1913 میں پیدا ہوئے تھے اور 1998 میں انتقال کیا۔ انھوں نے اپنی کتاب مشاطہ گانِ ادب میں زبان سے ناواقفیت کا ایک دل چسپ واقعہ رقم کیا ہے جو پاکستان کے ممتاز مصور زین العابدین کے اسپین میں قیام سے متعلق ہے۔ ملاحظہ کیجیے:
نشانوں اور لکیروں نے ہی ترقی کر کے تحریر کی طرف قدم بڑھایا ۔ انسان کی پہلی تحریر بڑی سادہ اور بچوں جیسی تھی۔ اُس نے اپنا مطلب بیان کرنے کے لئے تصویریں بنانی شروع کیں۔ اس کو تصویری خط پکٹوریل (PICTORIAL) یا تصویری زبان ہیروگلی فکس (HIEROGLYPHICS) کہتے ہیں۔ تصویر کشی یا مرقع نویسی، دنیا میں انسان کی سب سے پہلی تحریر یا تصویری زبان ہے۔ اور اس تصویری تحریر یا تصویر کی زبان استعمال کرنے کی منزل سے، اگر چہ انسان، عرصہ دراز گزرا کہ ترقی کر کے بہت آگے بڑھ گیا ہے، مگر یہ تصویری زبان، اب بھی رائج اور کارفرما ہے۔
مسٹر زین العابدین، پاکستان کے دوسرے نامور مصور ہیں۔ انھوں نے اپنے سفرِ اسپین کی روداد، رسالہ ماہِ نو، کراچی کے اگست نمبر1955ء میں شائع کرایا تھا۔ انھوں نے لکھا تھا کہ مجھے ایک اہم ضرورت سے اسپین جانا پڑا۔ ہوٹل میں اوپر سامان رکھنے کے بعد، نیچے کھانے کے لئے گئے۔ ہوٹل کے ویٹر صرف فرانسیسی اور اسپینی زبانیں بولتے تھے اور زین العابدین صاحب ان دونوں زبانوں سے ناواقف تھے۔ اب مصیبت ہو گئی۔ ویٹر ان کے پاس آتے تھے اور اپنی زبان میں سوال کر کے آرڈر لینا چاہتے تھے۔ جواب نہ ملنے پر واپس چلے جاتے تھے۔ زین العابدین صاحب نے لکھا ہے کہ بغل کے ٹیبل پر ایک صاحب مچھلی کھا رہے تھے۔ میں نے سوچا کہ ویٹر کو اس کی شکل دکھا کر مچھلی ہی منگا کے کھا لوں۔
مگر جب تک ویٹر آوے آوے، وہ صاحب مچھلی کا آخری لقمہ بھی منہ میں ڈال چکے تھے۔ ناچار خاموش رہے اور سوچتے رہے کہ اس صورت حال میں تو پاکستان واپس چلا جانا ہو گا۔ کیونکہ یہ دقت ہر جگہ ہو گی اور بالخصوص جب کھانا ہی نہیں مل سکے گا تو یہاں رہا کیسے جا سکتا ہے؟
ایک ذہین معمر ویٹر جب ان کے پاس آرڈر لینے کے لئے آیا اور اس کو سوال کا جواب اسپینی اور فرانسیسی دونوں زبانوں میں نہ ملا تو وہ سمجھ گیا کہ مسافر فرانسیسی اور اسپینی زبانیں نہیں جانتا اور اُس کو کھانا ملنا بھی چاہیے، لہٰذا اس نے منیجر کے پاس جا کر اس کو صورت حال سے آگاہ کیا۔ تجربہ کار منیجر نے ویٹر سے کہا کہ اس مسافر کو باورچی خانہ میں لے جاؤ اور سب کھانے دکھاؤ اور جس جس چیز کو وہ پسند کرے، وہ اس کو دی جائے۔ چنانچہ وہ زین العابدین صاحب کو باورچی خانہ میں لے گیا۔ وہاں سب عورتیں ہی عورتیں تھیں۔ ویٹر کے صورت حال سمجھانے پر وہ سب کھل کھلا کے ہنس پڑیں، جس سے زین العابدین صاحب کو گُونہ خفت محسوس ہوئی مگر اسے برداشت کرنا ہی پڑا۔
آخر کھانے سب دکھائے گئے اور جنہیں انھوں نے پسند کیا وہ ان کے سامنے پیش کیے گئے۔ اُس وقت تو کھانے کا مسئلہ یوں حل ہو گیا، مگر وہ بیچارے پریشان تھے کہ اس طرح کب تک اور کہاں کہاں کام چلے گا؟ بالآخر انہیں یکایک خیال آیا کہ تصویری زبان میں کیوں نہ بات کی جائے؟
چنانچہ اس کے بعد جب وہ کھانے کی میز پر جاتے تو پنسل اور کاغذ ساتھ لے جاتے اور جو جو چیزیں چاہتے تھے، اس کی تصویریں بنا دیتے تھے۔ مثلاً بوائلڈ انڈہ طلب کرنا ہوا تو مرغی کی تصویر بنائی۔ اس کے پاس انڈے کی تصویر بنائی۔ اس کے سامنے چولھا کی تصویر بنائی اور اس پر پانی کو اُبلتے دکھا کے، انڈے کو اس میں کھولتے دکھاتے تھے۔ ویٹر مسکرا کر ان کے لئے ابالے ہوئے انڈے لے آتا تھا، یا گوشت منگوانا ہوا تو خصّی کی ران اور چولھا کی تصویر بنائی اور تیر کے ذریعہ اس کو چولھے کی طرف لے گئے اور دیگچی میں پکتے دکھایا۔ اس تصویری زبان کو دیکھنے اور مزہ لینے کے لئے ہر کھانے کے وقت متعدد ویٹر ان کے پاس اکٹھے ہو جاتے تھے اور دو ایک اور گاہک بھی وہاں پر تماشا دیکھنے آجاتے، اور ان میں سے کوئی نہ کوئی انگریزی زبان جاننے والا اُن کو مل جاتا تھا۔ انہوں نے لکھا ہے کہ مجھے جو کام تھا اور جتنے دن کا کام تھا، میں نے ہر جگہ اسی ’تصویری زبان‘ کو استعمال کیا اور اس موقع سے کوئی نہ کوئی انگریزی داں مجھے مل جاتا تھا۔ یہاں تک کہ میں اپنا کام پورا کر کے کراچی واپس آیا۔ اس طور پر ساری ترقیوں کے باوجود اب بھی تصویری زبان سے انسان کام لے رہا ہے اور یہ زبان اب بھی زندہ ہے اور شاید ہمیشہ زندہ رہے گی۔