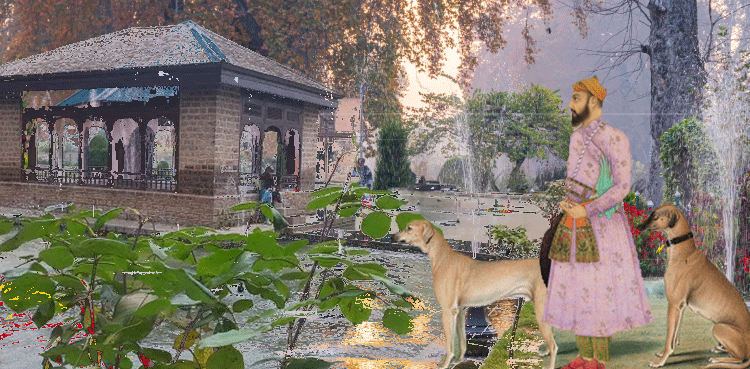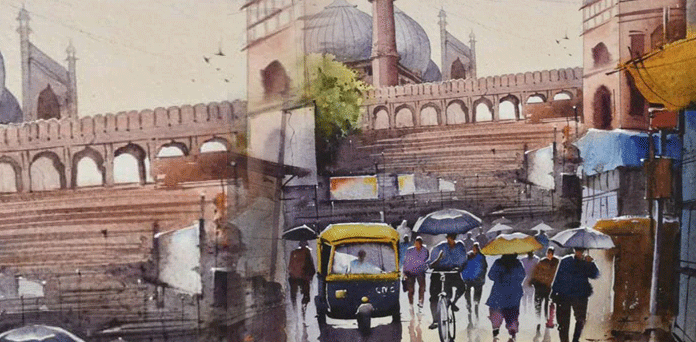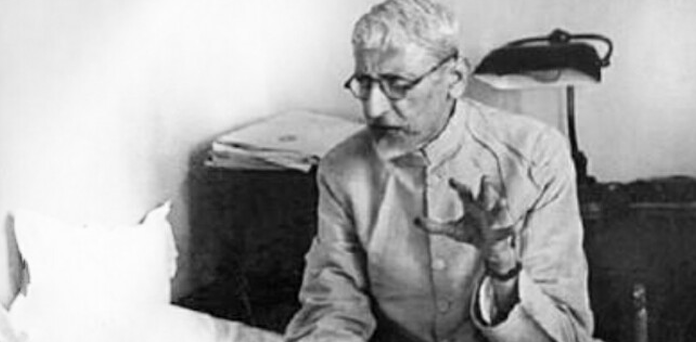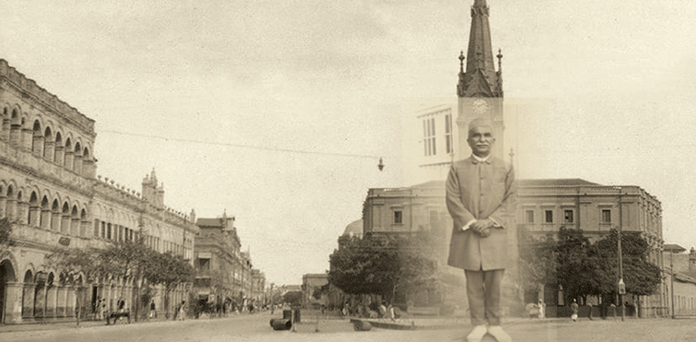بھگت کبیر ہندوستان کے مشہور صوفی بزرگ اور شاعر تھے۔ مسلمان اور ہندو دونوں ان کو روحانی پیشوا تسلیم کرتے ہیں۔ وہ اس دور میں فرسودہ روایات، ذات پات کی وجہ سے تفریق اور چھوت چھات میں پڑے لوگوں کو پیار محبت سے رہنے کا درس دیتے رہے اور توہم پرست معاشرے کی اصلاح کرتے ہوئے عمر گزار دی۔
ہرش کے بعد ساڑھے پانچ سو سال تک ہندوستان سیاسی انتشار کا شکار رہا۔ سلطنت دہلی کے قیام نے اس انتشار کو ختم کر کے شمالی ہند کو ایک سیاسی وحدت کی شکل دی۔ اس نئی سلطنت کے بانی اپنے ساتھ ایک فکر انگیز اور حیات آفرین مذہبی اور معاشرتی نظام لائے تھے۔ اس لئے ہندوستان کی تہذیب کا جزو نہ بن سکے۔ اہلِ ہند انتشار اور پرگندگی کے باوجود پرانی شان دار تہذیبی روایات رکھتے تھے۔
سیاسی شکست کی وجہ سے یہ روایات انہیں جان سے زیادہ عزیز ہوگئی تھیں اور بہر قیمت ان کی حفاظت کرنا چاہتے تھے۔ ان حالات میں نہ تو ہندو مسلمانوں میں جذب ہو سکتے تھے اور نہ مسلمان ہندوؤں میں بلکہ فضا اس حد تک ناسازگار تھی کہ ابتداء میں وہ ایک دوسرے کو متاثر بھی نہ کر سکے۔ اس بیگانگی اور دوئی کو دور کرنے کا سہرا ان صوفیوں کے سر ہے جنہوں نے مذہب کی ظاہری صورت اور طریقِ تجارت کے اختلاف کو نظر انداز کر کے دونوں مذہبوں کے باطنی شعور کو اپنایا اور رواداری، خدمتِ خلق، انسان دوستی اور صلح کل کے مسلک کو عام کر کے مذہبی اور تہذیبی مصالحت کی خوشگوار فضا پیدا کی۔
بھگتی تحریک نے اپنے مخصوص رنگ میں ان روایات کو اور آگے بڑھایا، اور سماجی اور مذہبی زندگی کی ہر سطح پر اتحاد اور ہم آہنگی پیدا کرنے کی وہ مبارک کوشش کی جس سے ہندوستانی تہذیب کو گنگا جمنی روایات کے نشوونما میں بڑی مدد ملی۔
جنوبی ہند میں مسلمانوں کی آمد کے بعد ان کے مذہبی عقائد کی اشاعت جن میں وحدانیت، اخوت اور مساوات کو بڑی اہمیت حاصل ہے، اور بعض دوسرے اسباب کی وجہ سے مذہبی بیداری کی ایک لہر دوڑ گئی اور بھگتی تحریک کا آغاز ہوا۔ گیارھویں صدی میں سری رنگم کی خاک اٹھنے سے والے عظیم مفکر اور مصلح رامانجا اچاریہ نے بھگتی کے عقیدے کو منظم اور مربوط فلسفے کی شکل دی۔ انھیں کے سلسلہ کے پانچویں بزرگ راما نند ہیں جو چودھویں صدی کے آخر اور پندرھویں صدی کی ابتداء میں گزرے ہیں۔ شمالی ہند میں بھگتی کے عقیدے کو انھیں کی وجہ سے فروغ ہوا۔ انھوں نے بڑے جوش و خروش کے ساتھ ذات پات کے نظام کی مخالفت کی اور تمام ذاتوں فرقوں اور مذہبوں کو اشتراک و اتحاد کی دعوت دی۔ ان کے ممتاز چیلوں میں برہمنوں کے علاوہ ایک جاٹ، ایک چمار، ایک نائی اور ایک مسلمان جولاہا بھی تھا۔ یہی مسلمان جولاہا کبیر ہے۔
بھگتی تحریک کے رہنماؤں میں جو شہرت، مقبولیت اور ہر دلعزیزی کبیر کے حصے میں آئی وہ کسی اور کو نصیب نہ ہوئی۔ ان کے دوہے آج بھی ہندوستان بھر میں گھر گھر پڑھے جاتے ہیں اور ہندو مسلمان، عورت مرد، بچے، بوڑھے، امیر غریب درویش اور دنیا دار سب ہی انھیں اپنی اپنی بول چال میں بے تکلفی کے ساتھ استعمال کرتے ہیں۔ لیکن جو کبیر ایسے جانے پہچانے ہیں ان کی زندگی کے حالات کہانیوں، اور روایتوں کے روپ بہروپ میں یوں کھو گئے ہیں کہ ان کے بارے میں ٹھیک ٹھیک کچھ کہنا نہایت مشکل ہے۔ یہاں تک کہ ان کی پیدائش اور موت کی تاریخوں کا بھی صحیح صحیح پتہ نہیں، تاہم عام طور پر یہی مانا جاتا ہے کہ وہ ۱۳۹۸ء میں پیدا ہوئے۔ ایک سو بائیس سال کی عمر پائی اور ۱۵۱۸ء میں انتقال کیا۔
کبیر کی پیدائش کے متعلق مشہور روایت یہ ہے کہ بنارس کا ایک مسلمان جولاہا نبیرو اپنی بیوی نیما (نعیمہ) کے ساتھ تالاب پر سے گزر رہا تھا۔ تالاب کے کنارے اسے ایک نومولود بچہ پڑا ملا، اس کے اپنے اولاد نہ تھی، اس لئے بچہ کو اٹھا لایا اور پرورش کرنے لگا۔ قاضی نے کبیر نام رکھا اور اسی نام سے یہ بچہ مشہور ہوا۔
بعض کہتے ہیں کہ سوامی رامانند نے ان جانے میں ایک بیوہ برہمنی کو دعا دی کہ تجھے بیٹا ہو۔ دعا قبول ہوئی، بیوہ بدنامی کے ڈر سے بچہ کو تالاب کے کنارے پھینک آئی جہاں سے نبیرو اسے اپنے گھر اٹھا لیا۔
جوالاہے نے اس لاوارث بچے کو بڑے پیار سے پالا پوسا، لیکن اس کے گھر تعلیم و تربیت کیا ہو سکتی تھی۔ کبیر ان پڑھ ہی رہے، باپ نے اپنے فن میں طاق کر دیا تھا۔ کبیر بھی کپڑا بنتے اور بازار میں بیچ آتے۔ رامانند کے مرید ہونے کے بعد بھی انھوں نے اپنے پیشے کو نہیں چھوڑا اور دین اور دنیا کو ایک ساتھ نباہتے رہے۔
کہتے ہیں لڑکپن ہی سے وہ حق و صداقت کی طرف مائل ہو گئے تھے۔ ذات بات کا مد بھید، مذہب کا اختلاف، رنگ ونسل کا امتیاز، رسمی عبادت کے طور طریق، رسم و رواج کے بندھن، روایات اور توہمات کی غلامی، انھیں بالکل پسند نہ تھی۔ انہیں یہ دیکھ کر بڑا دکھ ہوتا تھا کہ خدا کے نام پر لوگ جھگڑتے اور مذہب کی دہائی دے کر مرنے مارنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں۔ انسان، انسان سے محبت نہیں کرتا بلکہ اس کو ملچھ اور شودر کا نام دے کر حقیر اور ذلیل کرتا ہے۔ کوئی اینٹ پر پتھر کو پوجتا ہے اور کوئی اپنے پندار کے آگے سر جھکا دیتا ہے۔ خدا اور اس کے بندوں کی کسی کو پروا نہیں، عشق اور خدمت خلق کے جذبے سے سب کے دل محروم ہیں۔
انھیں خیالات کو وہ شعر کا جامہ پہن کر لوگوں کو سناتے اور راہِ راست پر لانے کی کوشش کرتے تھے۔ لیکن لوگ ان کا مذاق اڑاتے اور ان کی بات پر کان نہ دھرتے۔ وہ کہتے تھے کہ بے پیرے کی بات کی کیا اہمیت۔ کبیر کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی اور وہ پیر کی تلاش میں نکل پڑے۔ بہت سے سنتوں اور اہلُ اللہ سے فیض اٹھایا لیکن جس چیز کی انہیں تلاش تھی وہ کہیں نہ ملی۔ بالآخر رامانند جی کے آستانے پر حاضری دی اور من کی مراد مل گئی۔ مسلمان کبیر پنتھیوں کا خیال ہے کہ وہ مانک پور کے شیخ تقی سہروردی کے مرید تھے۔ واقعہ کچھ ہی ہو۔ اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ کبیر کے ہاں ویدانتیوں اور صوفیوں کے عقاید شیر و شکر ہو گئے تھے۔ انھوں نے اسلام سے بھی اکتساب کیا تھا اور ہندومت سے بھی فیض اٹھایا تھا۔ سنت سادھوؤں کے ساتھ بھی دشت و بیابان کی خاک چھانی تھی۔ اور اولیاء اللہ کے حلقے میں بھی بیٹھے تھے۔ رام نام کی جپ بھی کی تھی اور اسمِ اعظم کا ورد بھی کیا تھا۔ اور اس نتیجے پر پہونچے تھے کہ ان میں سے کسی کے درمیان تضاد نہیں بلکہ وہ ایک ہی تصویر کے دو رخ اور ایک ہی حقیقت کے دو نام ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مسلک کے اختلاف کی اہمیت ان کی نظر میں قابلِ اعتنا نہ رہی بلکہ مقصد اور منزل کو وہ سب کچھ جاننے لگے تھے۔
ان کی بیوی کا نام نیرو بتایا جاتا ہے جس کی پیدائش اور مذہب کی کہانی بھی کبیر کی کہانی سے ملتی جلتی ہے۔ کہتے ہیں کہ تیس سال کی عمر میں کبیر گھومتے گھامتے گنگا کے کنارے ایک بن کھنڈی سادھو کی کٹیا پر پہونچے، سادھو مر چکا تھا، اور کٹیا میں ایک نوجوان لڑکی اکیلی رہتی تھی۔ اس لڑکی نے بتایا کہ ایک دن سادھو گنگا ہی میں اشنان کر رہا تھا۔ ایک ٹوکری بہتے بہتے اس کے بدن سے آن لگی۔ سادھو نے اسے کھول کر دیکھا تو اس میں ایک بچہ کپڑوں میں لپٹا ہوا تھا۔ اس نے گھر لا کر بچے کی پرورش کی اور اس کا نام لوئی رکھا۔
کبیر لوئی کو اپنے ساتھ لے آئے۔ اس کے بطن سے کمال اور کمالی پیدا ہوئے۔ کمال سے کبیر خوش نہ تھے اس لئے کہ وہ دنیا دار تھا۔
مرنے سے پہلے کبیر بنارس سے مگہر چلے گئے تھے۔ عوام کا عقیدہ ہے کہ جو کاشی میں مرتا ہے اس کی نجات ہو جاتی ہے، لیکن مگہر میں مرنے والے کا دوسرا جنم گدھے کا ہوتا ہے۔ کبیر توہمات کے خلاف تھے۔ اس لئے انھوں نے بنارس کے بجائے مگہر میں مرنے کو ترجیح دی۔ وہ خود کہتے ہیں: کاشی ہو یا اوسر مگہر مجھے پروا نہیں۔ میرے دل میں رام بسا ہوا ہے۔
ان کی موت کے واقعہ کے گرد بھی روایتوں کا حسین ہالہ ہے۔ کہتے ہیں کہ کبیر مرے ہیں تو ان کے ہندو اور مسلمان پیروؤں میں جھگڑا ہو گیا, ہندو لاش کو جلاتا اور مسلمان دفن کرنا چاہتے تھے۔ ایسے میں کسی کی آواز آئی۔ چادر کے نیچے تو دیکھو، وہاں کیا دھرا ہے، لاش پر سے چادر بنائی گئی تو بس پھولوں کا ایک ڈھیر تھا۔ آدھے پھول مسلمانوں نے مگہر میں دفن کیے اور آدھے پھول ہندو بنارس لے آئے اور انھیں جلایا۔ راکھ جہاں دفن کی گئی تھی۔ وہاں ایک مٹھ بنایا گیا ہے جو کبیر چورے کے نام سے مشہور ہے۔
کبیر نے اپنی تعلیم کو منظم شکل دی اور نہ کوئی علیحدہ فرقہ بنایا۔ اپنے خیالات اور جذبات کو وہ گیتوں اور دوہوں کے ذریعہ عوام تک پہونچاتے تھے۔ جو سینہ یہ سینہ منتقل ہوتے رہے ہیں۔ بعد میں اس کلام کے کئی مجموعے مرتب اور شائع ہوئے بنے ان کی تعداد (۲۱) اور بعضے (۸۲) بتلاتے ہیں۔
(مصنف حسینی شاہد کی کتاب امر جیون سے منتخب کردہ جو ہندوستان کے مشاہیر کے تذکرے پر مشتمل ہے۔ اس کتاب کا اوّلین ایڈیشن 1964 میں شایع ہوا تھا)