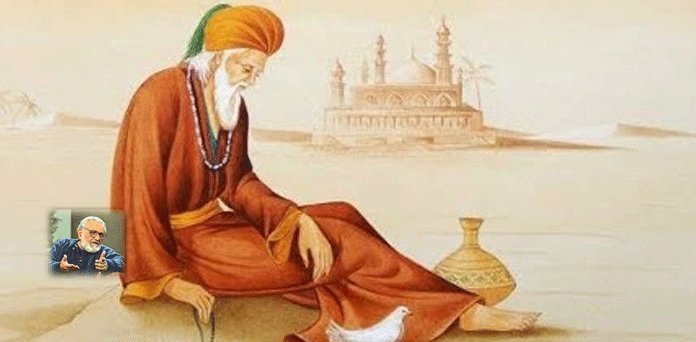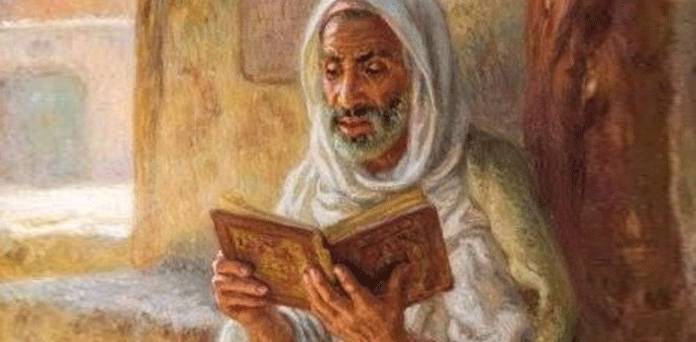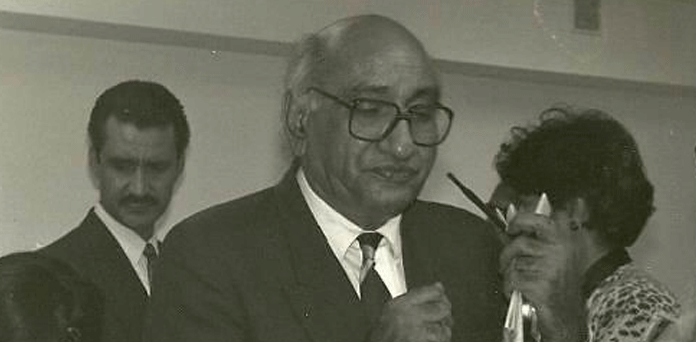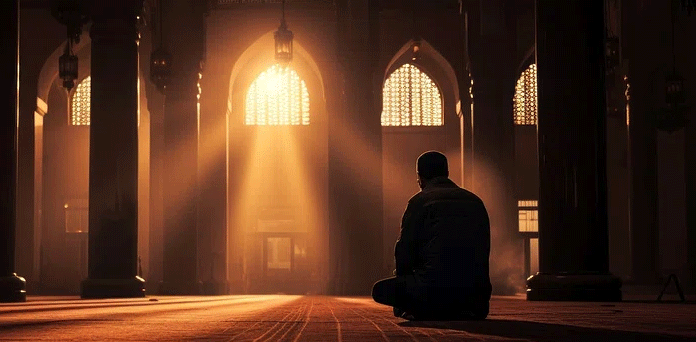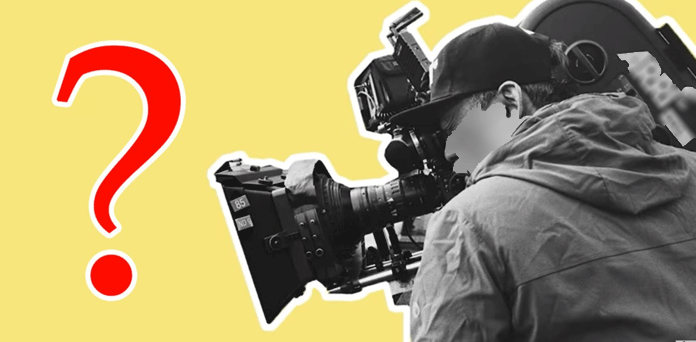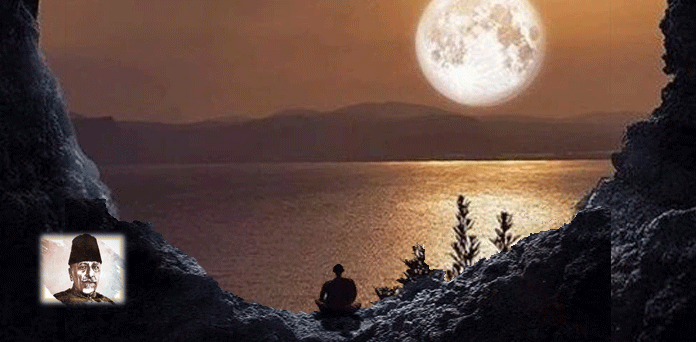عہدِ قدیم کے مؤرخ لکھتے ہیں کہ اگلے زمانہ میں فارس کے شرفا اپنے بچوں کے لئے تین باتوں کی تعلیم میں بڑی کوشش کرتے تھے۔ شہ سواری، تیراندازی اور راست بازی۔
شہ سواری اور تیراندازی تو بے شک سہل آ جاتی ہوگی، مگر کیا اچھی بات ہوتی کہ اگر ہمیں معلوم ہو جاتا کہ راست بازی کن کن طریقوں سے سکھاتے تھے اور وہ کون سی سپر تھی کہ جب دروغ دیو زاد آکر ان کے دلوں پر شیشہ جادو مارتا تھا، تو یہ اس چوٹ سے اس کی اوٹ میں بچ جاتے تھے۔
اس میں شک نہیں کہ دنیا بری جگہ ہے۔ چند روزہ عمر میں بہت سی باتیں پیش آتی ہیں، جو اس مشت خاک کو اس دیو آتش زاد کی اطاعت کے لئے مجبور کرتی ہیں۔ انسان سے اکثر ایسا جرم ہو جاتا ہے کہ اگر قبولے تو مرنا پڑتا ہے، ناچار مکرنا پڑتا ہے۔ کبھی آبلہ فریبی کر کے جاہلوں کو پھنساتا ہے، جب لقمہ رزق کا پاتا ہے۔ اس کے علاوہ بہت مزے دنیا کے ہیں کہ مکر و دغا ان کی چاٹ لگاتی ہے، اور جزوی جزوی خطائیں ہو جاتی ہیں جن سے مکرتے ہی بن آتی ہے۔ غرض بہت کم انسان ہوں گے جن میں یہ حوصلہ و استقلال ہو کہ راستی کے راستے میں ہر دم ثابت قدم ہی رہیں۔
یہ بھی یاد رہے کہ انسان کے سچ بولنے کے لئے سننے والے بھی ضرور ہیں، کیوں کہ خوشامد جس کی دکان میں آج موتی برس رہے ہیں اس سے زیادہ جھوٹ کیا ہوگا اور کون ایسا ہے جو اس قید کا زنجیری نہیں۔ ڈرپوک بیچارا ڈر کا مارا خوشامد کرتا ہے۔ تابع دار امید کا بھوکا آقا کو خوش کرکے پیٹ بھرتا ہے۔ دوست محبت کا بندہ ہے۔ اپنے دوست کے دل میں اسی سے گھر کرتا ہے۔ ایسے بھی ہیں کہ نہ غلام ہیں، نہ ڈرپوک ہیں۔ انہیں باتوں باتوں میں خوش کر دینے ہی کا شوق ہے۔ اسی طرح جب جلسوں میں نمودیے گدھوں کے دعوے بل ڈاگ کی آواز سے کئی میدان آگے نکل جاتے ہیں، تو ان میں وہ لوگ بھی ہوتے ہیں جنہیں کچھ امید، کچھ ڈر، کچھ مروت سے، غرض چار ناچار کبھی ان کے ساتھ ساتھ، کبھی پیچھے پیچھے دوڑنا پڑتا ہے۔
سچ کا عجب حال ہے کہ اتنا تو اچھا ہے، مگر پھر بھی لوگ اسے ہر وقت اچھا نہیں سمجھتے، چنانچہ جب کسی شے پر دل آتا ہے اور سچ اس کے برخلاف ہوتا ہے تو اس وقت سچ سے زیادہ کوئی برا نہیں معلوم ہوتا۔ اصل یہ ہے کہ حضرت انسان کو حقیقت اور واقعیت سے کچھ غرض نہیں۔ جس چیز کو جی نہیں چاہتا، اس کا جاننا بھی نہیں چاہتے۔ جو بات پسند نہیں آتی اس کا ذکر بھی نہیں سنتے، اس کان سنتے ہیں، اس کان سے نکال دیتے ہیں۔ حکیموں نے جھوٹ سے متنفر ہونے کی بہت سی تدبیریں نکالی ہیں اور جس طرح بچوں کو کڑوی دوا مٹھائی میں ملا کر کھلاتے ہیں، اسی طرح انواع و اقسام کے رنگوں میں اس کی نصیحتیں کیں ہیں تاکہ لوگ اسے ہنستے کھیلتے چھوڑ دیں۔
واضح ہوکہ ملکہ صداقت زمانی، سلطان آسمانی کی بیٹی تھی جو کہ ملکہ دانش خاتون کے پیٹ سے پیدا ہوئی تھی۔ جب ملکہ موصوفہ نے ہوش سنبھالا تو اوّل تعلیم و تربیت کے سپرد ہوئی۔ جب انہوں نے اس کی پرورش میں اپنا حق ادا کر لیا تو باپ کے دربار میں سلام کو حاضر ہوئی۔ اسے نیکی اور نیک ذاتی کے ساتھ خوبیوں اور محبوبیوں کے زیور سے آراستہ دیکھ کر سب نے صدق دل سے تعریف کی۔ عزتِ دوام کا تاجِ مرصع سر پر رکھا گیا اور حکم ہوا کہ جاؤ اولادِ آدم میں اپنا نور پھیلاؤ۔ عالم سفلی میں دروغ دیو زاد ایک سفلہ نابکار تھا کہ حمقِ تیرہ دماغ اس کا باپ تھا اور ہوسِ ہوا پرست اس کی ماں تھی۔ اگرچہ اسے دربار میں آنے کی اجازت نہ تھی، مگر جب کسی تفریح کی صحبت میں تمسخر اور ظرافت کے بھانڈ آیا کرتے تھے تو ان کی سنگت میں وہ بھی آ جاتا تھا۔
اتفاقاً اس دن وہ بھی آیا ہوا تھا اور بادشاہ کو ایسا خوش کیا تھا کہ اسے ملبوسِ خاص کا خلعت مل گیا تھا۔ یہ منافق دل میں سلطانِ آسمانی سے سخت عداوت رکھتا تھا۔ ملکہ کی قدر و منزلت دیکھ کر اسے حسد کی آگ نے بھڑکایا۔ چنانچہ وہاں سے چپ چپاتے نکلا اور ملکہ کے عمل میں خلل ڈالنے کو ساتھ ساتھ روانہ ہوا۔ جب یہ دو دعوے دار نئے ملک اور نئی رعیت کے تسخیر کرنے کو اٹھے تو چونکہ بزرگانِ آسمانی کو ان کی دشمنی کی بنیاد ابتدا سے معلوم تھی، سب کی آنکھیں ادھر لگ گئیں کہ دیکھیں ان کی لڑائی کا انجام کیا ہو؟
سچ کے زور و قوت کو کون نہیں جانتا۔ چنانچہ ملکہ صداقت کو بھی حقیقت کے دعوے تھے۔ اٹھی اور اپنے زور میں بھری ہوئی تھی؛ اسی واسطے بلند اٹھی۔ اکیلی آئی اور کسی کی مدد ساتھ نہ لائی۔ ہاں آگے آگے فتح و اقبال نور کا غبار اڑاتے آتے تھے اور پیچھے پیچھے ادراک پری پرواز تھا۔ مگر صاف معلوم ہوتا تھا کہ تابع ہے، شریک نہیں۔ ملکہ کی شان شاہانہ تھی، اور دبدبہ خسروانہ تھا۔ اگرچہ آہستہ آہستہ آتی تھی، مگر استقلال کا رکاب پکڑے تھا۔ اور جو قدم اٹھتا تھا، دس قدم آگے پڑتا نظر آتا تھا۔ ساتھ اس کے جب ایک دفعہ جم جاتا تھا، تو انسان کیا فرشتہ سے بھی نہ ہٹ سکتا تھا۔
دروغ دیو زاد بہروپ بدلنے میں طاق تھا، ملکہ کی ہر بات کی نقل کرتا تھا اور نئے نئے سوانگ بھرتا تو وضع اس کی گھبرائی ہوئی معلوم ہوتی تھی۔ دنیا کی ہوا و ہوس، ہزاروں رسالے اور پلٹنیں اس کے ساتھ لیے تھیں اور چوں کہ یہ ان کی مدد کا محتاج تھا، اسی لالچ کا مارا کمزور تابع داروں کی طرح ان کے حکم اٹھاتا تھا۔ ساری حرکتیں اس کی بے معنی تھیں اور کام بھی الٹ پلٹ، بے اوسان تھے۔ کیونکہ استقلال ادھر نہ تھا۔ اپنی شعبدہ بازی اور نیرنگ سازی سے فتح یاب تو جلد ہو جاتا تھا، مگر تھم نہ سکتا تھا، ہوا و ہوس اس کے یارِ وفادار تھے اور اگر کچھ تھے تو وہی سنبھالتے رہتے تھے۔
کبھی کبھی ایسا بھی ہو جاتا تھا کہ دونوں کا آمنا سامنا ہو کر سخت لڑائی آ پڑتی تھی۔ اس وقت دروغ دیو زاد اپنی دھوم دھام بڑھانے کے لئے سر پر بادل کا دھواں دھار پگڑ لپیٹ لیتا تھا۔ لاف و گزاف کو حکم دیتا کہ شیخی اور نمود کے ساتھ آگے جاکر غل مچانا شروع کر دو۔ ساتھ ہی دغا کو اشارہ کر دیتا تھا کہ گھات لگا کر بیٹھ جاؤ۔ دائیں ہاتھ میں طراری کی تلوار، بائیں ہاتھ میں بے حیائی کی ڈھال ہوتی تھی۔ غلط نما تیروں کا ترکش آویزاں ہوتا تھا۔ ہوا و ہوس دائیں بائیں دوڑتے پھرتے تھے۔ دل کی ہٹ دھرمی، بات کی پچ، پیچھے سے زور لگاتے تھے۔ غرض کبھی مقابلہ کرتا تھا تو ان زوروں کے بھروسے پر کرتا تھا اور باوجود اس کے کہ ہمیشہ یہی چاہتا تھا کہ دور دور سے لڑائی ہو۔ میدان میں آتے ہی تیروں کی بوچھاڑ کر دیتا تھا، مگر وہ بھی بادِ ہوائی، اٹکل پچو، بے ٹھکانے ہوتے تھے۔ خود ایک جگہ پر نہ ٹھہرتا تھا۔ دم بدم جگہ بدلتا تھا کیونکہ حق کی کمان سے جب تیر نظر اس کی طرف سر ہوتا تھا تو جھٹ تاڑ جاتا تھا۔
ملکہ کے ہاتھ میں اگرچہ باپ کی کڑک بجلی کی تلوار نہ تھی، مگر تو بھی چہرہ ہیبت ناک تھا اور رعب خداداد کا خود سر پر دھرا تھا۔ جب معرکہ مار کر ملکہ فتح یاب ہوتی تھی تو یہ شکست نصیب اپنے تیروں کا ترکش پھینک، بے حیائی کی ڈھال منہ پر لئے، ہوا و ہوس کی بھیڑ میں جاکر چھپ جاتا تھا۔ نشان لشکر گر پڑتا تھا اور لوگ پھریرا پکڑے زمین پر گھسیٹتے پھرتے تھے۔ ملکہ صداقت زمانی کبھی کبھی زخمی بھی ہوتی تھی۔ مگر سانچ کو آنچ نہیں، زخم جلد بھر جاتے تھے اور وہ جھوٹا نابکار جب زخم کھاتا تھا تو ایسے سڑتے تھے کہ اوروں میں بھی وبا پھیلا دیتے تھے۔ مگر ذرا انگور بندھے اور پھر میدان میں آن کودا۔
دروغ دیو زاد نے تھوڑے ہی تجربہ میں معلوم کر لیا تھا کہ بڑائی اور دانائی کا پردہ اسی میں ہے کہ ایک جگہ نہ ٹھہروں۔ اس لئے دھوکہ بازی اور شبہ کاری کو حکم دیا کہ ہمارے چلنے پھرنے کے لئے ایک سڑک تیار کرو، مگراس طرح کے ایچ پیچ اور ہیر پھیر دے کر بناؤ کہ شاہراہ صداقت جو خط مستقیم میں ہے اس سے کہیں نہ ٹکرائے۔ چنانچہ جب اس نابکار پر کوئی حملہ کرتا تھا تو اسی رستہ سے جدھر چاہتا تھا، نکل جاتا تھا اور جدھر سے چاہتا تھا پھر آن موجود ہوتا تھا۔
ان رستوں سے اس نے ساری دنیا پر حملے کرنا شروع کر دیے اور بادشاہت اپنی تمام عالم میں پھیلا کر دروغ شاہ دیو زاد کا لقب اختیار کیا۔ جہاں جہاں فتح پاتا تھا، ہوا و ہوس کو اپنا نائب چھوڑتا اور آپ فوراً کھسک جاتا۔ وہ اس فرماں روائی سے بہت خوش ہوتے تھے۔ اور جب ملکہ کا لشکر آتا تھا تو بڑی گھاتوں سے مقابلے کرتے تھے۔ جھوٹی قسموں کی ایک لمبی زنجیر بنائی تھی۔ سب اپنی کمریں اس سے جکڑ لیتے تھے کہ ہرگز ایک دوسرے کا ساتھ نہ چھوڑیں گے۔ مگر سچ کے سامنے جھوٹ کے پاؤں کہاں؟ لڑتے تھے اور متابعت کر کے ہٹتے تھے۔ پھر ادھر ملکہ نے منہ پھیرا، ادھر باغی ہو گئے۔ ملکہ جب آسمان سے نازل ہوئی تھی تو سمجھتی تھی کہ بنی آدم میرے آنے سے خو ش ہوں گے۔ جو بات سنیں گے اسے مانیں گے اور حکومت میری تمام عالم میں پھیل کر مستقل ہو جائے گی۔ مگر یہاں دیکھا کہ گزارہ بھی مشکل ہے۔ لوگ ہٹ دھرمی کے بندے ہیں اور ہوا و ہوس کے غلام ہیں اور اس میں بھی شک نہیں کہ ملکہ کی حکومت آگے بڑھتی تھی مگر بہت تھوڑی تھوڑی۔ اس پر بھی یہ دشواری تھی کہ ذرا اس طرف ہٹی اور پھر بدعملی ہو گئی کیونکہ ہوا و ہوس جھٹ بغاوت کا نقارہ بجا، دشمن کے زیرِ علم جا موجود ہوتے تھے۔
ہر چند ملکہ صداقت زمانی ان باتوں سے کچھ دبتی نہ تھی کیوں کہ اس کا زور کسی کے بس کا نہ تھا، مگر جب بار بار ایسے پاجی کمینے کو اپنے مقابلہ پر دیکھتی تھی اور اس میں سوا مکر و فریب اور کمزوری و بے ہمتی کے اصالت اور شجاعت کا نام نہ پاتی تھی تو گھٹتی تھی اور دل میں پیچ و تاب کھاتی تھی۔
جب سب طرح سے ناامید ہوئی تو غصہ ہوکر اپنے باپ سلطان آسمانی کو لکھا کہ آپ مجھے اپنے پاس بلا لیجئے۔ دنیا کے لوگ اس شیطان کے تابع ہوکر جن بلاؤں میں خوش ہیں ان ہی میں رہا کریں۔ اپنے کئے کی سزا آپ پالیں گے۔ سلطان آسمانی اگرچہ اس عرضی کو پڑھ کر بہت خفا ہوا مگر پھر بھی کوتاہ اندیشوں کے حال پر ترس کھایا اور سمجھا کہ اگر سچ کا قدم دنیا سے اٹھا توجہان اندھیر اور تمام عالم تہ و بالا ہو جائے گا۔ چنانچہ اس خیال سے اس کی عرض نا منظور کی۔ ساتھ اس کے یہ بھی گوارہ نہ ہوا کہ میرے جگر کا ٹکڑا جھوٹے بد اصلوں کے ہاتھوں یوں مصیبت میں گرفتار رہے۔ اسی وقت عالم بالا کے پاک نہادوں کو جمع کر کے ایک انجمن منعقد کی۔ اس میں دو امر تنقیح طلب قرار پائے۔
(۱) کیا سبب ہے کہ ملکہ کی کارروائی اور فرماں فرمائی دنیا میں ہر دل عزیز نہیں۔
(۲) کیا تدبیر ہے جس سے اس کے آئینِ حکومت کو جلد اہلِ عالم میں رسائی ہو اور اسے بھی ان تکلیفوں سے رہائی ہو۔
کمیٹی میں یہ بات کھلی کہ درحقیقت ملکہ کی طبیعت میں ذرا سختی ہے اور کارروائی میں تلخی ہے۔ صدرِ انجمن نے اتفاق رائے کر کے اس قدر زیادہ کہا کہ ملکہ کے دماغ میں اپنی حقیت کے دعوؤں کا دھواں اس قدر بھرا ہوا ہے کہ وہ ہمیشہ ریل گاڑی کی طرح سیدھے خط میں چل کر کامیابی چاہتی ہیں، جس کا زور طبیعتوں کو سخت اور دھواں آنکھوں کو کڑوا معلوم ہوتا ہے۔ بعض اوقات لوگوں کو اس کی راستی سے نقصان اٹھانے پڑتے ہیں۔ کبھی ایسے فساد اٹھ کھڑے ہوتے ہیں جن کا سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے اور یہ زمانہ ایسا ہے کہ دور اندیشی اور صلاح وقت کے بغیر کام نہیں چلتا۔ پس اسے چاہئے کہ جس طرح ہو سکے اپنی سختی اور تلخی کی اصلاح کرے۔ جب تک یہ نہ ہوگا لوگ اس کی حکومت کو رغبت سے قبول نہ کریں گے کیوں دیو دروغ کی حکومت کا ڈھنگ بالکل اس کے خلاف ہے۔ اوّل تو اس میں فارغ البالی بہت ہے اور جو لوگ اس کی رعایا میں داخل ہوجاتے ہیں، انہیں سوا عیش و آرام کے دنیا کی کسی بات سے خبر نہیں ہوتی۔ دوسرے وہ خود بہروپیا ہے۔ جو صورت سب کو بھائے وہی روپ بھر لیتا ہے اور اوروں کی مرضی کا جامہ پہنے رہتا ہے۔
غرض اہل انجمن نے صلاح کر کے ملکہ کی طرزِ لباس بدلنے کی تجویز کی۔ چنانچہ ایک ویسا ہی ڈھیلا ڈھالا جامہ تیار کیا جیسا کہ جھوٹ پہنتا تھا اور وہ پہن کر لوگوں کو جل دیا کرتا تھا۔ اس جامہ کا مصلحت زمانہ نام ہوا۔ چنانچہ اس خلعت کو زیبِ بدن کر کے ملکہ پھر ملک گیری کو اٹھی۔ جس ملک میں پہنچتی اور آگے کو راستہ مانگتی، ہوا و ہوس حاکم وہاں کے اسے دروغ دیو زاد سمجھ کر آتے اور شہر کی کنجیاں نذر گزرانتے۔ ادھر اس کا دخل ہوا ادھر ادراک آیا اور جھٹ وہ جامہ اتار لیا۔ جامہ کے اترتے ہی اس کی اصل روشنی اور ذاتی حسن و جمال پھر چمک کر نکل آیا۔ چنانچہ اب یہی وقت آ گیا ہے، یعنی جھوٹ اپنی سیاہی کو ایسا رنگ آمیزی کر کے پھیلاتا ہے کہ سچ کی روشنی کو لوگ اپنی آنکھوں کے لئے مضر سمجھنے لگے ہیں۔
اگر سچ کہیں پہنچ کر اپنا نور پھیلانا چاہتا ہے تو پہلے جھوٹ سے کچھ زرق برق کے کپڑے مانگ تانگ کر لاتا ہے۔ جب تبدیل لباس کر کے وہاں جا پہنچتا ہے تو وہ لفافہ اتار کر پھینک دیتا ہے۔ پھر اپنا اصلی نور پھیلاتا ہے کہ جھوٹ کی قلعی کھل جاتی ہے۔
(اردو کے صاحبِ طرز ادیب اور انشاء پرداز محمد حسین آزاد کی ایک نہایت متاثر کن تحریر)