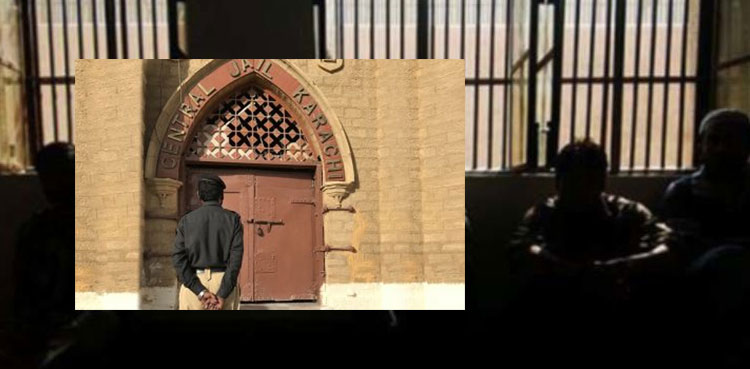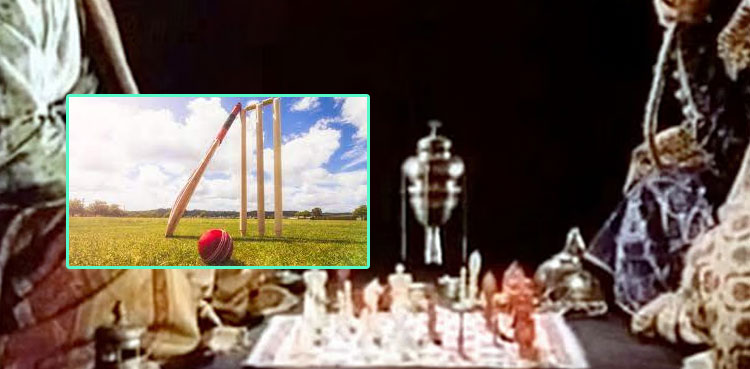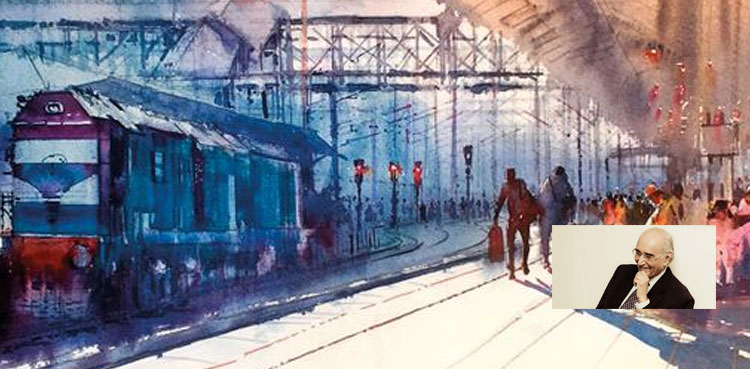طمانیت نہ کہ انبساط’ طمانیت، نفسِ مطمئنہ، ایک اندازِ نظر، ایک اساسی اندازِ نظر جسے اپنا کر عین ممکن ہے آدمی پر کبھی کوئی آنچ نہ آ سکے۔
آدمی اپنا توازن کھو بیٹھتا ہے اور پھر اسے دوبارہ حاصل کر لیتا ہے۔ اسے پتا ہے کہ دنیا اسی کا نام ہے۔ وہ اپنی غلطی سے یا کسی اور کی غلطی سے ٹھوکر کھاتا ہے اور گر جاتا ہے اور پھر خدا یا دنیا کو قصور وار ٹھہرائے بغیر اٹھ کھڑا ہوتا ہے۔
وہ اپنی بدولت یا دوسروں کی وجہ سے دکھ اٹھاتا ہے، لیکن اپنے حال زار پر قابو پا لیتا ہے۔مایوسیوں کو پی جاتا ہے اور زیادتیوں کو برداشت کرتا ہے، معمولی حیثیت کے لوگوں کی معمولی باتوں کا چڑھتا دھارا اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اور وہ اپنے میں ان سب باتوں کی اہلیت طیش میں آئے بغیر دل سخت کئے بغیر پیدا کر لیتا ہے۔
اس طمانیت کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ہر کسی کو اور ہر بات کو شفقت سے کام لے کر معاف کر دیا جائے۔ اس سے یہ مراد بھی نہیں کہ آدمی چپ چاپ مار کھاتا رہے۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ طمانیت اس کے حق میں نہیں کہ آدمی آنکھیں میچ کر بیٹھا رہے۔ اس کے برعکس اس اندازِ نظر کو اپنانے والا آدمی ہر چیز پر نظر رکھتا ہے۔ انسانیت کی طفلانہ غیر اصلاح پذیری اور اس کی غفلت۔ ہولناکیوں کی تہی مغزانہ تکرار اور مدتوں کے گلے سڑے تصورات کے احیا کو تو بالخصوص کبھی اوجھل نہیں ہونے دیتا۔ خود کو کھیل سے الگ تھلگ کیے بغیر ہی وہ اس کی تہ تک پہنچ جاتا ہے، وہ اعتماد کرتا ہے لیکن حزم کو کبھی ہاتھ سے نہیں جانے دیتا۔ وہ محبت کرتا ہے لیکن اس کی ذات کا ایک حصہ دیکھنے بھالنے کی غرض سے آزاد رہتا ہے۔ وہ زیادہ کی توقع نہیں رکھتا اور غیر مترقبہ یافت کو سوغات سمجھتا ہے۔ اس کے دوستانہ رویے میں مسکینی کا شائبہ نہیں ہوتا۔ وہ نہ کسی پر مربیانہ انداز میں دستِ شفقت رکھتا ہے، نہ گھٹنوں کے بل جُھک جانے کے لئے آمادہ رہتا ہے۔ اس کی طمانیت کو خدا رسیدہ اولیاء کے مطمئن توکل اور رنج و غم کے اندر مال سے قطعاً کوئی سروکار نہیں۔ اس طمانیت کا جواز بس اسی دنیا تک ہے اور اسے نہ یہاں کوئی جزا ملے گی نہ اگلے جہاں میں۔ وہ اپنے دوستوں پر اسی طرح بھروسا کرتا ہے جس طرح وہ اس پر بھروسا کرتے ہیں، لیکن کبھی ان کے بھید لینے کی کوشش نہیں کرتا اور نہ کبھی بعض زخموں کے بارے میں کسی قسم کی پوچھ گچھ کرتا ہے، وہ پیچھے پڑ جانے والوں میں سے نہیں۔
اس طمانیت کی بدولت یہ ممکن ہی نہیں رہتا کہ وہ کسی بھی لحاظ سے حتیٰ کہ ایسے دور میں بھی جو اپنی تیغ بکف عدم رواداری اور بھانت بھانت کی دہشت گردیوں کے لئے بدنام ہے، عقائد کے معاملے میں خود رائے ہو سکے۔ اسے کسی قسم کی قوم پرستی کی فرصت نہیں، خواہ وہ دائیں بازو سے تعلق رکھتی ہو یا بائیں سے اور یوں وہ آدمی اپنے سماج بدر ہونے کا اعلان کرتا ہے۔
وہ اپنے زمانے کی تمام نام نہاد، سیاہ و سفید نو و کہن اساطیر کی تہ کو پہنچ جاتا ہے۔ مطمئن آدمی شور نہیں مچاتا۔ وہ خواہ مخواہ بول بول کر خود کو ہلکان کرنے کا قائل نہیں ہوتا۔ علاوہ ازیں وہ ان گیتوں کو گانے میں بھی پس و پیش کرتا ہے جنہیں عوام النّاس گاتے پھر رہے ہوں۔ وہ قدم سے قدم ملا کر چلنے سے بھی انکار کر دیتا ہے۔ ایک بار اس نے ایسا کیا تھا اور بڑا نقصان اٹھایا تھا۔ وہ قدم سے قدم ملا کر جو چلا تو لاشوں سے بھرے ہوئے ایک گڑھے میں جا پہنچنے سے بال بال بچا۔ اسے یوٹو پیاﺅں پر ایمان لانے سے انکار ہے۔ اس کی وجہ یہ نہیں کہ وہ حرارتِ ایمانی سے محروم ہے۔ بات صرف اتنی ہے کہ اسے معلوم ہے کہ انسانیت کس قدر مائل بہ بدی ہے اور وہ اس کی طرف سے بدگمان ہے۔ وہ لمبے چوڑے وعدوں کے جھانسوں میں نہیں آتا۔
اصل نکتہ یہی ہے۔ وہ دھوکا نہیں کھاتا۔ میں مکرر کہتا ہوں جو آدمی طمانیت کے اساسی اندازِ نظر کا حامل ہو، وہ کھیل سے الگ تھلگ رہے بغیر اس کی تہ کو پہنچ جاتا ہے۔ اس پر کوئی فریب کارگر نہیں ہوتا۔ وہ کھیل میں حصّہ لیتا ہے، لیکن اس قدر اندھا دھند طریقے سے نہیں کہ اسی میں مست ہو کر رہ جائے۔ وہ شراکت اور لاتعلقی کے مابین آزادی سے حرکت کرتا رہتا ہے اور ان دونوں کیفیتوں کو جدا رکھنے والی لکیروں کا خود تعین کرتا ہے۔
(والٹر باؤیر، مترجم محمد سلیم الرحمٰن)