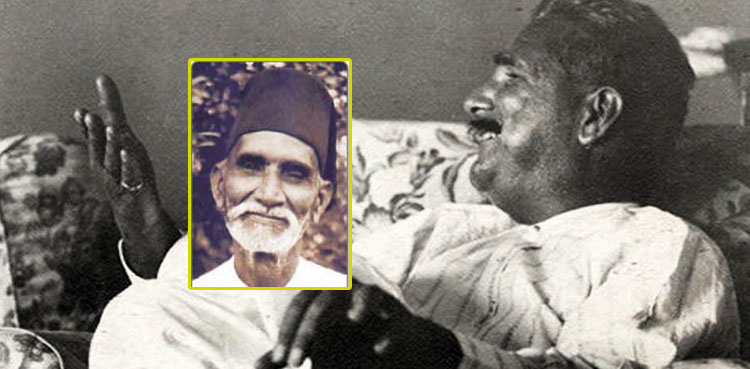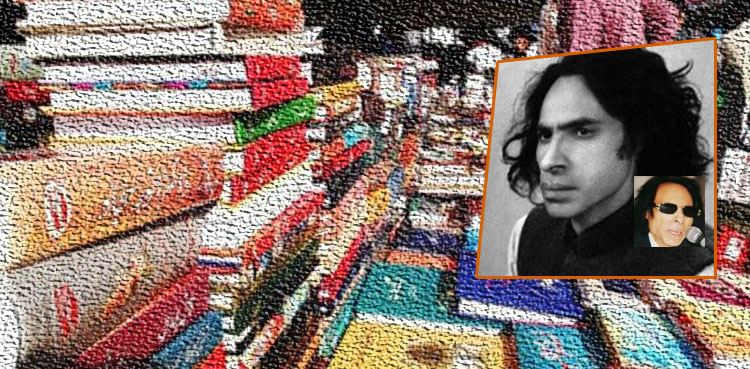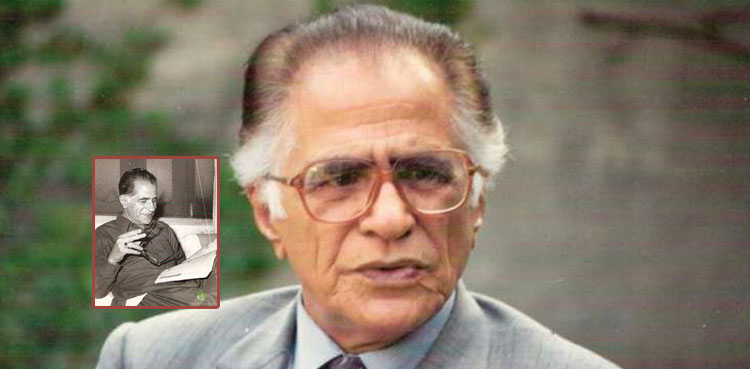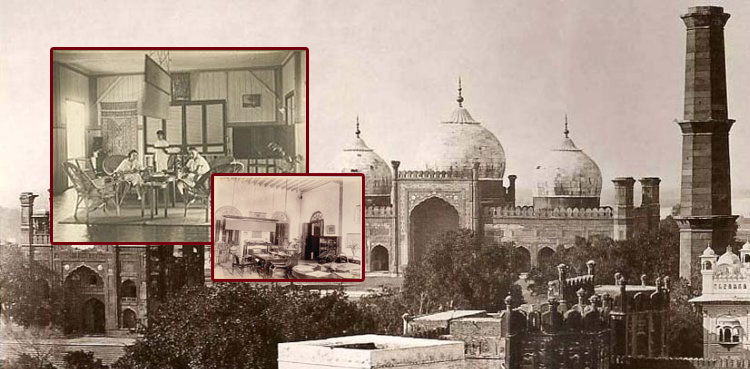ایک دن مرزا غالب نے مومن خاں مومن سے پوچھا، ’’حکیم صاحب! آخر اس درد کی دوا کیا ہے؟‘‘
مومن نے جواب میں کہا، ’’مرزا صاحب! اگر درد سے آپ کا مطلب داڑھ کا درد ہے، تو اس کی کوئی دوانہیں۔ بہتر ہوگا آپ داڑھ نکلوا دیجیے کیوں کہ ولیم شیکسپیر نے کہا ہے‘‘، ’’وہ فلسفی ابھی پیدا نہیں ہوا جو داڑھ کا درد برداشت کر سکے۔‘‘
مرزا غالب نے حکیم صاحب کی سادہ لوحی سے لطف اندوز ہوتے ہوئے فرمایا، ’’میری مراد داڑھ کے درد سے نہیں، آپ کی دعا سے ابھی میری تمام داڑھیں کافی مضبوط ہیں۔‘‘
’’تو پھر شاید آپ کا اشارہ دردِ سر کی طرف ہے، دیکھیے مرزا صاحب! حکما نے دردِ سر کی درجنوں قسمیں گنوائی ہیں۔ مثلاً آدھے سر کا درد، سر کے پچھلے حصے کا درد، سر کے اگلے حصے کا درد، سر کے درمیانی حصے کا درد، ان میں ہر درد کے لیے ایک خاص بیماری ذمہ دار ہوتی ہے۔ مثلاً اگر آپ کے سر کے درمیانی حصہ میں درد ہوتا ہے تو ممکن ہے آپ کے دماغ میں رسولی ہو۔ اگر کنپٹیوں پر ہوتا ہے تو ہو سکتا ہے آپ کی بینائی کمزور ہو گئی ہو۔ دراصل درد سر کو مرض نہیں مرض کی علامت سمجھا جاتا ہے۔‘‘
’’بہرحال چاہے یہ مرض ہے یا مرض کی علامت، مجھے درد کی شکایت نہیں ہے۔‘‘
’’پھر آپ ضرور دردِ جگر میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ آپ نے اپنے کچھ اشعار میں اس کی طرف اشارہ بھی کیا ہے۔
مثلاً؛ یہ خلش کہاں ہوتی جو جگر کے پار ہوتا
یا…..حیراں ہوں روؤں دل کو یا پیٹوں جگر کو میں‘‘
مرزا صاحب، حکما نے اس مرض کے لیے ’’پپیتا‘‘ کو اکسیر قرار دیا ہے۔ کسی تک بند نے کیا خوب کہا ہے۔
جگر کے فعل سے انساں ہے جیتا
اگر ضعفِ جگر ہے کھا پپیتا
’’آپ کا یہ قیاس بھی غلط ہے۔ میرا آ ج تک اس مرض سے واسطے نہیں پڑا۔‘‘
’’تو پھر آپ اس شاعرانہ مرض کے شکار ہو گئے ہیں جسے دردِ دل کہا جاتا ہے اور جس میں ہونے کے بعد میر کو کہنا پڑا تھا،
الٹی ہو گئیں سب تدبیریں، کچھ نہ دوا نے کام کیا
دیکھا اس بیماریٔ دل نے آخر کام تمام کیا
’’معلوم ہوتا ہے اس ڈومنی نے جس پر مرنے کا آپ نے اپنے ایک خط میں ذکر کیا ہے آپ کو کہیں کا نہیں رکھا۔‘‘
’’واہ حکیم صاحب! آپ بھی دوسروں کی طرح میری باتوں میں آ گئے۔ اجی قبلہ کیسی ڈومنی اور کہاں کی ڈومنی وہ تو میں نے یونہی مذاق کیا تھا۔ کیا آپ واقعی مجھے اتنا سادہ لوح سمجھتے ہیں کہ مغل زادہ ہو کر میں ایک ڈومنی کی محبت کا دم بھروں گا۔ دلّی میں مغل زادیوں کی کمی نہیں۔ ایک سے ایک حسین و جمیل ہے۔ انہیں چھوڑ کر ڈومنی کی طرف رجوع کرنا بالکل ایسا ہے جیسا کہ آپ نے اپنے شعر میں بیان کیا ہے؛
اللہ رے گمرہی! بت و بت خانہ چھوڑ کر
مومن چلا ہے کعبہ کو اک پارسا کے ساتھ
’’خدا نخواستہ کہیں آپ کو جوڑوں کا درد تو نہیں۔ دائمی زکام کی طرح یہ مرض بھی اتنا ڈھیٹ ہے کہ مریض کی ساری عمر جان نہیں چھوڑتا، بلکہ کچھ مریض تو مرنے کے بعد بھی قبر میں اس کی شکایت کرتے سنے گئے ہیں۔ عموماً یہ مرض جسم میں تیزابی مادّہ کے زیادہ ہو جانے سے ہوتا ہے۔‘‘
’’تیزابی مادہ کو ختم کرنے کے لیے ہی تو میں ہر روز تیزاب یعنی شراب پیتا ہوں۔ ہومیو پیتھی کا اصول ہے کہ زہر کا علاج زہر سے کیا جانا چاہیے۔ خدا جانے یہ سچ ہے یا جھوٹ، لیکن یہ حقیقت ہے کہ شراب نے مجھے اب تک جوڑوں کے درد سے محفوظ رکھا ہے۔‘‘
’’پھر آپ یقینا دردِ گردہ میں مبتلا ہیں۔ یہ درد اتنا ظالم ہوتا ہے کہ مریض تڑپ تڑ کر بے حال ہو جاتا ہے۔‘‘
’’میرے گردے ابھی تک سلامت ہیں شاید اس لیے کہ میں بڑے دل گردے کا انسان ہوں۔‘‘
’’اگر یہ بات ہے تو پھر آپ کو محض وہم ہو گیا ہے کہ آپ کو درد کی شکایت ہے اور وہم کی دوا نہ لقمان حکیم کے پاس تھی نہ حکیم مومن خاں مومنؔ کے پاس ہے۔‘‘
’’قبلہ میں اس درد کا ذکر کر رہاہوں جسے عرفِ عام میں ’’زندگی‘‘ کہتے ہیں۔‘‘
’’اچھا، زندگی! اس کا علاج تو بڑا آسان ہے ، ابھی عرض کیے دیتا ہوں۔‘‘
’’ارشاد۔ ‘‘
’’کسی شخص کو بچھو نے کاٹ کھایا۔ درد سے بلبلاتے ہوئے اس نے ایک بزرگ سے پوچھا، اس درد کا بھی کوئی علاج ہے، بزرگ نے فرمایا، ’’ہاں ہے اور یہ کہ تین دن چیختے اور چلاتے رہو۔ چوتھے دن درد خود بخود کافور ہو جائے گا۔‘‘
’’سبحان اللہ! حکیم صاحب، آپ نے تو گویا میرے شعر کی تفسیر کر دی۔‘‘
’’کون سے شعر کی قبلہ؟‘‘
’’اس شعر کی قبلہ…
غمِ ہستی کا اسد کس سے ہو جز مرگ علاج
شمع ہر رنگ میں جلتی ہے سحر ہونے تک
نیند کیوں رات بھر…..
ایک مرتبہ مرزا غالب نے شیخ ابراہیم ذوقؔ سے کہا، ’’شیخ صاحب! نیند کیوں رات بھر نہیں آتی؟‘‘ ذوق نے مسکراکر فرمایا۔ ظاہر ہے جس کمرے میں آپ سوتے ہیں ، وہاں اتنے مچھر ہیں کہ وہ رات بھر آپ کو کاٹتے رہتے ہیں۔ اس حالت میں نیند آئے بھی تو کیسے؟
معلوم ہوتا ہے یا توٓپ کے پاس مسہری نہیں اور اگر ہے تو اتنی بوسیدہ کہ اس میں مچھر اندر گھس آتے ہیں۔ میری مانیے تو آج ایک نئی مسہری خرید لیجیے۔‘‘
غالب نے ذوقؔ کی ذہانت میں حسبِ معمول اعتماد نہ رکھتے ہوئے جواب دیا، ’’دیکھیے صاحب! آخر ہم مغل زادے ہیں، اب اتنے گئے گزرے بھی نہیں کہ ہمارے پاس ایک ثابت و سالم مسہری بھی نہ ہو اور جہاں تک کمرے میں مچھروں کے ہونے کا سوال ہے۔ ہم دعویٰ سے کہ سکتے ہیں، جب سے ڈی ڈی ٹی چھڑکوائی ہے ایک مچھر بھی نظر نہیں آتا۔ بلکہ اب تو مچھروں کی گنگناہٹ سننے کے لیے ہمسائے کے ہاں جانا پڑتا ہے۔‘‘
’’تو پھر آپ کے پلنگ میں کھٹمل ہوں گے۔‘‘
’’کھٹملوں کے مارنے کے لیے ہم پلنگ پر گرم پانی انڈیلتے ہیں، بستر پر کھٹمل پاؤڈر چھڑکتے ہیں۔ اگر پھر بھی کوئی کھٹمل بچ جائے تو وہ ہمیں اس لیے نہیں کاٹتا ہے کہ ہمارے جسم میں اب لہو کتنا رہ گیا ہے۔ خدا جانے پھر نیند کیوں نہیں آتی۔‘‘
’’معلوم ہوتا ہے آپ کے دماغ میں کوئی الجھن ہے۔‘‘
’’بظاہر کوئی الجھن نظر نہیں آتی۔ آپ ہی کہیے بھلا مجھے کون سی الجھن ہو سکتی ہے۔‘‘ گستاخی معاف! سنا ہے آپ ایک ڈومنی پر مرتے ہیں، اور آپ کو ہماری بھابی اس لیے پسند نہیں کیوں کہ اسے آپ کے طور طریقے نا پسند ہیں۔ ممکن ہے آپ کے تحت الشعور میں یہ مسئلہ چٹکیاں لیتا رہتا ہو۔ ’’آیا امراؤ بیگم کو طلاق دی جائے یا ڈومنی سے قطع تعلق کر لیا جائے۔‘‘
’’واللہ! شیخ صاحب آپ کو بڑی دور کی سوجھی! ڈومنی سے ہمیں ایک شاعرانہ قسم کا لگاؤ ضرور ہے لیکن جہاں تک حسن کا تعلق ہے وہ امراؤ بیگم کی گرد کو نہیں پہنچتی۔‘‘
’’تو پھر یہ بات ہو سکتی ہے آپ محکمہ انکم ٹیکس سے اپنی اصلی آمدنی چھپا رہے ہیں اور آپ کو یہ فکر کھائے جاتا ہے۔ کسی دن آپ کے گھر چھاپہ پڑ گیا تو ان اشرفیوں کا کیا ہوگا جو آپ نے زمین میں دفن کر رکھی ہیں اور جن کا پتہ ایک خاص قسم کے آلہ سے لگایا جا سکتا ہے۔‘‘
’’اجی شیخ صاحب! کیسی اشرفیاں! یہاں زہر کھانے کو پیسہ نہیں شراب تو قرض کی پیتے ہیں اور اسی خود فریبی میں مبتلا رہتے ہیں کہ ہماری فاقہ کشی رنگ لائے گی۔ اگر ہمارے گھر چھاپہ پڑا تو شراب کی خالی بوتلوں اور آم کی گٹھلیوں کے علاوہ کوئی چیز نہیں ملےگی۔‘‘
’’اچھا وہ جو آپ کبھی کبھی اپنے گھر کو ایک اچھے خاصے قمار خانہ میں تبدیل کر دیتے ہیں، اس کے متعلق کیا خیال ہے۔‘‘
’’واہ شیخ صاحب! آپ عجیب باتیں کرتے ہیں، تھوڑا بہت جوا تو ہر مہذب شخص کھیلتا ہی ہے اور پھر ہر کلب میں بڑے بڑے لوگ ہر شام کو ’’برج‘‘ وغیرہ کھیلتے ہیں۔ جوا آخر جوا ہے چاہے وہ گھر پر کھیلا جائے یا کلب میں۔‘‘
’’اگر یہ بات نہیں تو پھر آپ کو کسی سے حسد ہے۔ آپ ساری رات حسد کی آگ میں جلتے رہتے ہیں اور میر کے اس شعر کو گنگناتے ہیں؛
اندوہ سے ہوئی نہ رہائی تمام شب
مجھ دل زدہ کو نیند نہ آئی تمام شب‘‘
’’بخدا شیخ صاحب! ہم کسی شاعر کو اپنا مد مقابل ہی نہیں سمجھتے کہ اس سے حسد کریں۔ معاف کیجیے، آپ حالانکہ استادِ شاہ ہیں۔ لیکن ہم نے آپ کے متعلق بھی کہا تھا۔ ذوق کی شاعری بانگ دہل ہے اور ہماری نغمۂ چنگ۔‘‘
’’مرزا صاحب! یہ تو صریحاً زیادتی ہے۔ میں نے ایسے شعر بھی کہے ہیں جن پر آپ کو بھی سر دھننا پڑا ہے۔‘‘
’’لیکن ایسے اشعار کی تعداد آٹے میں نمک کے برابر ہے۔‘‘
’’یہ ہے آپ کی سخن فہمی کا عالم اور کہا تھا آپ نے،
ہم سخن فہم ہیں غالب کے طرف دار نہیں‘‘
’’اگر ہم سخن فہم نہ ہوتے تو آپ کے کلام پر صحیح تبصرہ نہ کر سکتے۔ خیر چھوڑیے بات تو نیند نہ آنے کی ہو رہی تھی۔‘‘
’’کسی ڈاکٹر سے اپنا بلڈ پریشر چیک کرائیے۔ ہو سکتا ہے وہ بڑھ گیا ہو۔‘‘
’’قبلہ! جب بدن میں بلڈ ہی نہیں رہا تو پریشر کے ہونے یا بڑھنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔‘‘
’’پھر ہر رات سونے سے پہلے کسی ایسی گولی کا سہارا لیجیے جس کے کھانے سے نیند آجائے۔ آج کل بازار میں ایسی گولیاں عام بک رہی ہیں۔‘‘
’’انہیں بھی استعمال کر چکے ہیں۔ نیند تو انہیں کھا کر کیا آتی البتہ بے چینی اور بھی بڑھ گئی۔ اس لیے انہیں ترک کرنے میں ہی عافیت سمجھی۔‘‘
’’کسی ماہرِ نفسیات سے مشورہ کیجیے شاید وہ کچھ۔‘‘
’’وہ بھی کر چکے ہیں۔‘‘
’’تو کیا تشخیص کی اس نے؟‘‘
’’کہنے لگا، آپ کے تحت الشعور میں کسی ڈرنے مستقبل طور پر ڈیرا ڈال رکھا ہے۔ اس سے نجات حاصل کیجیے۔ آپ کو نیند آنے لگے گی۔‘‘
’’یہ تو بڑا آسان ہے، آپ اس ڈر سے نجات حاصل کیوں نہیں کر لیتے۔‘‘
’’لیکن ہمیں پتہ بھی تو چلے وہ کون سا ڈر ہے۔‘‘
’’اسی سے پوچھ لیا ہوتا۔‘‘
’’پوچھا تھا۔ اس نے جواب دیا، اس ڈر کا پتہ مریض کے سوا کوئی نہیں لگا سکتا۔‘‘
’’کسی لائق ایلو پیتھک ڈاکٹر سے ملیے، شاید وہ۔۔۔‘‘
’’اس سے بھی مل چکے ہیں۔ خون، پیشاب، تھوک، پھیپھڑے، دل اور آنکھیں ٹیسٹ کرنے کے بعد کہنے لگا، ان میں تو کوئی نقص نہیں معلوم ہوتا ہے۔ آپ کو نیند سے الرجی ہو گئی ہے۔‘‘
’’علاج کیا بتایا؟‘‘
’’کوئی علاج نہیں بتایا۔ دلیل یہ دی کہ الرجی ایک لاعلاج مرض ہے۔‘‘
’’آپ اگر اجازت دیں تو خاکسار جو کہ نہ حکیم ہے نہ ڈاکٹر بلکہ محض ایک شاعر آپ کے مرض کا علاج کر سکتا ہے۔‘‘
’’ضرور کیجیے۔‘‘
’’دیکھیے! اگر آپ کو نیند رات بھر نہیں آتی تو آپ رات کے بجائے دن میں سویا کیجیے۔ یعنی رات کو دن اور دن کو رات سمجھا کیجیے۔‘‘
’’سبحان اللہ! کیا نکتہ پیدا کیا ہے۔ تعجب ہے ہمیں یہ آج تک کیوں نہیں سوجھا۔‘‘
’’سوجھتا کیسے‘‘، آپ تو اس وہم میں مبتلا ہیں؛
آج مجھ سا نہیں زمانے میں
شاعرِ نغر گوئے خوش گفتار
’’شیخ صاحب آپ نے خوب یاد دلایا۔ بخدا ہمارا یہ دعویٰ تعلی نہیں حقیقت پر مبنی ہے۔‘‘
’’چلیے یوں ہی سہی۔ جب تک آپ استاد شاہ نہیں ہیں مجھے آپ سے کوئی خطرہ نہیں۔‘‘
’’یہ اعزاز آپ کو ہی مبارک ہو۔ ہمیں تو پینے کو ’’اولڈ ٹام‘‘ اور کھانے کو ’’آم‘‘ ملتے رہیں۔ ہم خدا کا شکر بجا لائیں گے۔‘‘
دراصل شراب پی پی کر آپ نے اپنا اعصابی نظام اتنا کمزور کر لیا ہے کہ آپ کو بے خوابی کی شکایت لاحق ہو گئی۔ اس پر ستم یہ کہ توبہ کرنے کی بجائے آپ فخر سے کہا کرتے ہیں۔ ’’ہر شب پیا ہی کرتے ہیں، مے جس قدر ملے۔‘‘
’’بس بس شیخ صاحب رہنے دیجیے، ورنہ مجھے آپ کو چپ کرانے کے لیے آپ کا ہی شعر پڑھنا پڑے گا۔‘‘
’’کون سا شعر قبلہ؟‘‘
’’رندِ خراب حال کو زاہد نہ چھیڑ تُو
تجھ کو پرائی کیا پڑی اپنی نبیڑ تو‘‘
(اردو ادب کے معروف طنز و مزاح نگار کنہیا لال کپور کے قلم کی شوخیاں)