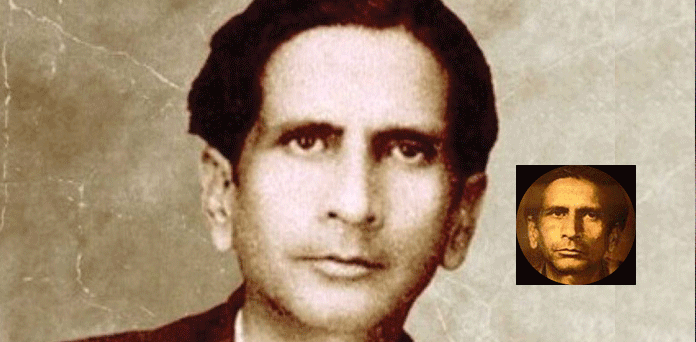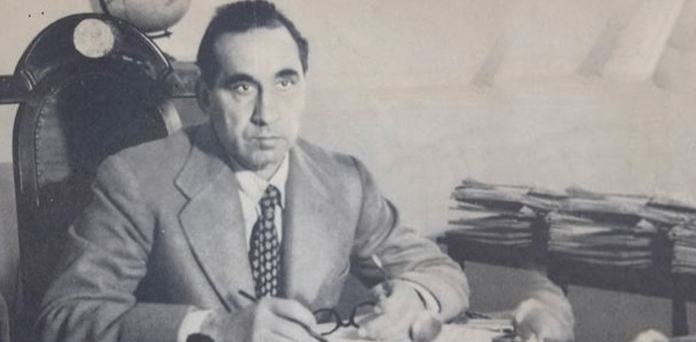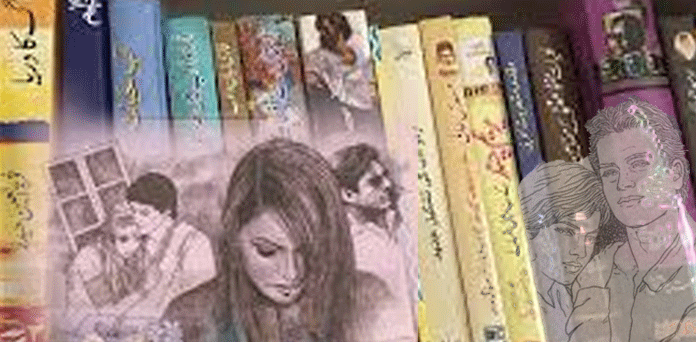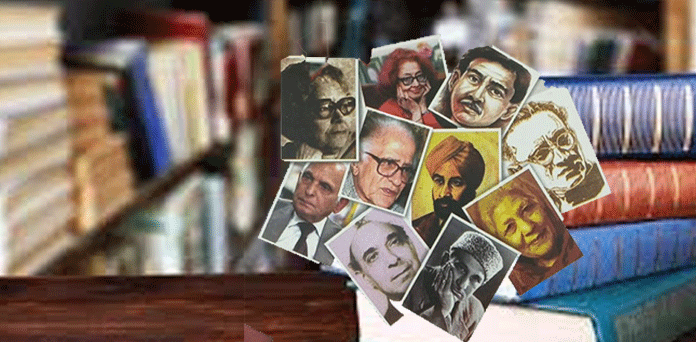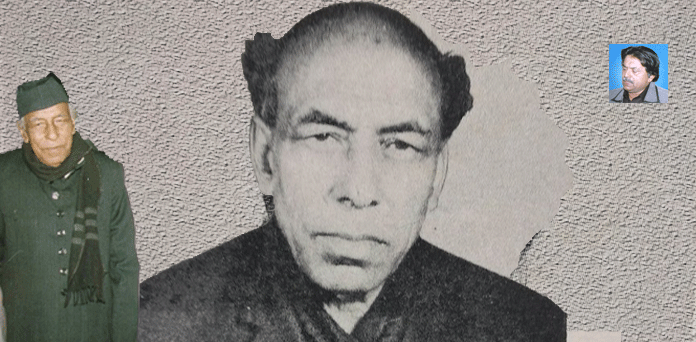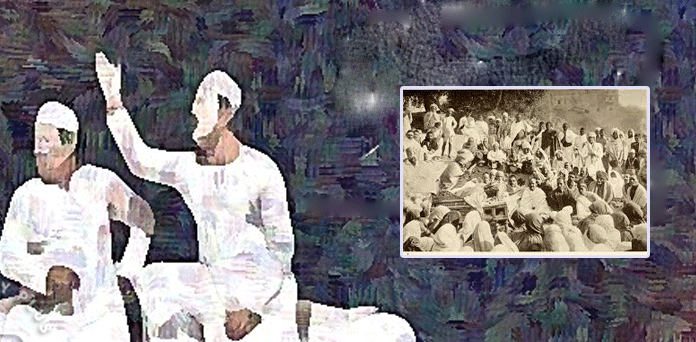ایک بادشاہ نے ایک ملکہ کے حسن و جمال کا شہرہ سنا اور اس پر عاشق ہو گیا۔ پھر وہ تخت و تاج چھوڑ کر اس اجنبی ملک کی طرف اس ملکہ کا دیدار کرنے چلا۔ مگر اس بادشاہ سے زیادہ کمال شہزادہ جانِ عالم نے دکھایا جو ایک توتے کی باتوں میں آکر انجمن آرا کا نادیدہ عاشق ہو گیا اور دربدر خاک بسر پھرا۔ مگر ایک شہزادہ وہ بھی تو تھا جس نے خواب میں ایک صورت دیکھی تھی اور صبح ہونے پر اس نے باپ سے کہا کہ ایسا اس کا ناک نقشہ ہے اور ایسی اس کی چھب ہے، شادی کروں گا تو اسی سے کروں گا، نہیں تو ڈوب مروں گا۔ اور ایک وہ شہزادہ تھا جس نے جوتی دیکھی اور کہا کہ جوتی ایسی ہے تو جوتی والی کیسی ہوگی اور جوتی والی پر مر مٹا۔
شہزادوں پر منحصر نہیں۔ اُن دنوں سب عشق کرتے تھے اور اسی طور کرتے تھے۔ کوئی نوجوان لکڑہارا درخت کاٹتے کاٹتے کوئی شیریں آواز سنتا وہ آواز اسے لے اڑتی۔ آواز ایسی ہے تو آواز والی کیسی ہوگی۔ پھر جب وہ درخت آہستہ آہستہ کاٹ چکتا تو کوئی پری چہرہ برآمد ہوتی اور وہ اس پر مہربان ہو جاتی۔ مہربان کا لفظ میں نے جان کر استعمال کیا ہے۔ عورت مہربان ہی ہو سکتی ہے، عشق نہیں کر سکتی، عشق مردوں کا پیشہ رہا ہے۔ عورت اس پیشے میں شریک ہو جائے تو یہ اس کی عنایت ہے، نہ ہو تو اس کی شکایت نہ کرنا چاہیے اور جب دونوں ہی گریجویٹ ہوں تو پھر تو شکایت بالکل زیب نہیں دیتی۔
خیر تو ذکر یہ تھا کہ عشق ان دنوں سچ مچ اندھا تھا۔ دیدار شربتِ وصل کا مرتبہ رکھتا تھا۔ مگر دیدار ہوتا کہاں تھا۔ محبوب کی خوشبو چہار سو پھیلی ہوتی تھی مگر اس کا جلوہ نہیں ہوتا تھا۔ مگر یہ بات شاید شاعرانہ ہو گئی۔ نثر میں بات یوں ہے کہ ان دنوں مرد اندھا تھا اور عورت تاریک براعظم تھی۔ تاریک براعظم مرد کو پکارتا بھی تھا، ڈراتا بھی تھا۔ اس بلاوے اور ڈراوے سے مہموں اور معرکوں اور واردات نے جنم لیا اور اندھا عشق عہد کی بینائی بن گیا اور اس کی روشنی میں لوگ چلتے تھے اور اپنے کام کرتے تھے۔ اس روشنی میں خودکشیاں ہوئیں، سفر کئے گئے، لڑائیاں لڑی گئیں۔ کبھی ہار کبھی جیت۔
یہ وہ زمانہ تھا جب جذبے پر آدمی کا ایمان قائم تھا۔ اپنے جذبے کے واسطے سے بروئے کار ہونے میں اسے کسی صورت عار نہ تھی۔ سری کرشن جی حکیم عصر بھی تھے اور عاشق پیشہ بھی تھے۔ جذبے پر ایمان ہی ایکلیز کو کھینچ کر لڑائی کے محاذ پر لے گیا اور جذبے پر ایمان ہی نے اسے اس معرکے سے بیزار کیا۔ وہ روٹھ گیا۔ اس نے ہتھیار کھول کر رکھ دیے اور کہا کہ بھاڑ میں جائے یونان کی غربت۔ میری محبوبہ کو ایگمنان لے گیا ہے۔ اب میں نہیں لڑوں گا۔
جنگیں طرزِ احساس کو بناتی اور بگاڑتی ہیں۔ جیسا معرکہ پڑتا ہے ویسا ہی ذہن پیدا ہوتا ہے۔ لڑائی کے محاصرے کی داستان نے ہومر کو پیدا کیا۔ جذبے کے معنی ہونے پر ہومر کا ایمان تھا۔ اس حد تک ایمان کہ اس کے لئے اس واسطے سے پڑنے والا معرکہ ایسی جامعیت رکھتا ہے کہ اسے بیان کر کے شاعر اپنے عہد کے جذبات، احساسات اور عقائد و افکار کی تفسیر کر سکتا ہے۔ مگر دوسری جنگِ عظیم نے کامیو کو پیدا کیا۔ اس نے ایک تو OUTSIDER لکھا، اوپر سے یہ کہا کہ ہر ادیب اپنے عہد کے جذبات کو ایک شکل عطا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ کل کا جذبہ محبت کا تھا۔ آج اتحاد اور آزادی کے جذبات نے دنیا میں ہنگامہ پیدا کر رکھا ہے۔ کل تک یہ ہوتا تھا کہ محبت کے پیچھے آدمی خودکشی کر لیتا تھا، آج اجتماعی جذبات عالمگیر تباہی کا سامان پیدا کرتے ہیں۔
کامیو صاحب محبت کو آج کا جذبہ نہیں مانتے مگر آدمی بامروت ہیں۔ انہوں نے ہمیں تمہیں یہ اجازت دی ہے کہ ضروری کاموں سے وقت اگر بچے تو وقتاً فوقتاً عشق کر لینے میں کوئی مضائقہ نہیں۔ ویسے اگر ضروری کاموں سے وقت بچنے ہی کا معاملہ ہے تو بہتر ہے کہ عشق طالب علمی کے زمانے میں کر لیا جائے۔ اس وقت آدمی کو ضروری کام نہیں ہوتے۔ بات یہ ہے کہ اگر اسمگلنگ یا چور بازاری یا اس قسم کی اور کوئی حرکت کرکے ہم نے جذباتی خودکشی نہیں کر لی ہے، تو یہ لہو کی بوند جو ہمارے اندر ہے کسی نہ کسی وقت ضرور ہنگامہ آرا ہو گی۔ طالب علمی ہی کے زمانے میں وہ ہنگامہ آرا ہو جائے تو اچھا ہے۔ زیادہ سے زیادہ ایک سال امتحان نہیں دیں گے۔
پرانی دنیا میں عشق جز وقتی مشغلہ نہیں تھا۔ اس کی حیثیت ضمنی اور غیرضروری کام کی نہیں تھی۔ عشق کے آغاز کے ساتھ سارے ضروری کام معطل ہو جاتے تھے اور آدمی کی پوری ذات اس کی لپیٹ میں آ جاتی تھی۔ یہ صنعتی عہد کا کارنامہ ہے کہ عشق کو ذات کی واردات اور زندگی کا نمائندہ جذبہ ماننے سے انکار کیا گیا اور یورپ کا معاملہ یہ ہے کہ صنعتی عہد کے ساتھ وہاں سے انسانی حوالے غائب ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ یورپ نے بیسویں صدی میں دو بڑی جنگیں لڑیں اور دونوں بغیر کسی انسانی حوالے کے۔ بیسویں صدی کا یورپ کسی ہیلن کی خاطر جنگ کرنے کا جگر پیدا نہ کر سکا۔ لہو کی بوند ہنگامہ آرا تو ہوئی مگر کسی جیتی جاگتی ہستی کے حوالے سے نہیں، کسی کھرے اور سچے جذبے کے واسطے سے نہیں۔ کیا ہٹلر اور کیا اس کے حریف، دونوں کے پیشِ نظر کچھ غیرانسانی مجرد قسم کے حوالے تھے، کچھ سامراجی مقاصد تھے۔
قوموں کو جنگیں تباہ نہیں کرتیں۔ قومیں اس وقت تباہ ہوتی ہیں جب جنگ کے مقاصد بدل جاتے ہیں۔ یورپ کے اخلاقی زوال کی ذمہ داری اس واقعے پر ہے کہ اس نے جذبے کو فراموش کیا اور غیرانسانی حوالوں سے دو لڑائیاں لڑیں۔ سو پھر الیڈ اور اوڈیسی کہاں سے پیدا ہو جاتیں۔ ’آوٹ سائڈر‘ ہی لکھا جانا تھا۔ جہاں سب انسانی رشتے اپنے معنی کھو چکے ہیں۔
رہے ہم، تو ہمارا مغربی سامراج نے ۱۸۵۷ء ہی میں پٹرا کر دیا تھا۔ سن ستاون کے بعد مولانا حالی آئے اور بے چاروں نے سیدھا سچا اعتراف کر لیا کہ،
کچھ دل سے ہیں ڈرے ہوئے کچھ آسماں سے ہم
آسمان سے ڈر کر ہم نے انگریزوں کی اطاعت قبول کی اور دل سے ڈر کر ملکہ وکٹوریہ کے زمانے والی انگریزی اخلاقیات میں پناہ لی۔ تب نیچرل اور قومی شاعری کی بدعت شروع ہوئی اور واردات عشق کے واسطے سے ہونے والی شاعری ملعون ٹھہری اور مولانا حالیؔ نے بیان جاری کیا کہ،
بھائیو! دل نہ لگانا، نہ لگانا ہرگز
جیتے جی موت کے تم منہ میں نہ جانا ہرگز
یوں تو اس سے بہت پہلے میر صاحب یہ کہہ چکے تھے کہ،
وصیت میر نے مجھ کو یہی کی
کہ سب کچھ ہونا تو عاشق نہ ہونا
مگر دونوں آوازوں میں بڑا بنیادی فرق ہے۔ حالیؔ کی آواز ایک سہمے ہوئے آدمی کی آواز ہے، اس آدمی کی جو عشق سے خائف ہے۔ میر کی آواز ایک خوار و خستہ عاشق کا مشورہ ہے۔ اس شخص کا جو پوری واردات سے گزرا ہے۔ ویسے ایک طرح سے یہ اسی قسم کا مشورہ ہے جو تجربے سے ناآشنا نوخیز شہزادوں کو دیا جاتا تھا کہ سب کھونٹ جانا، چوتھے کھونٹ مت جانا، یا سب دروازے کھولنا پر ساتواں درمت کھولنا، مگر یہ مشورہ تھوڑا ہی تھا۔ یہ تو چیلنج ہوتا تھا کہ اگر جگر ہے تو ساتواں در کھولو، ور نہ شریف آدمی بن کر بیٹھے رہو۔ لہو کی بوند ان دنوں مستقل ہنگامہ آرا رہتی تھی۔ سو شہزادے چیلنج کو قبول کرتے تھے اور ساتواں در کھول کر اپنے سر خرابی لاتے تھے۔ خرابی ان کے خون کے اندر تھی۔
برہمن جنم پتری بناتے تھے اور بتاتے تھے کہ جنون کے آثار ہیں، خرابی کی علامات ہیں، بارہ برس تک آسمان مت دیکھنے دو اور چاندنی میں مت سونے دو۔ مگر خون کا فساد ادبدا کر تاریخ کا گھپلا ڈالتا تھا۔ بارہویں برس کی آخری شب شہزادہ آسمان دیکھ لیتا تھا اور کوئی پری اسے اڑا لے جاتی تھی۔ مگر وہ شخص جو شہزادہ نہیں تھا، شاعر تھا، اس کے لئے عمر کی ہر رات بارہویں برس کی آخری شب بنی اور چاند میں پری نظر آکر خور و خواب میں خلل ڈالتی رہی۔ اس کا نام میر تقی تھا۔ اسے باپ نے نصیحت کی تھی کہ فرزند عشق کیا کر، سعادت مند بیٹے نے صوفی صافی باپ کی نصیحت گرہ میں باندھی۔ عشق کیا، دیوانہ ہوا اور غزل کہی۔
ایک زمانے کے بعد مولانا حالی آئے۔ اب وقت اور تھا۔ دل کا خوف الگ، آسمان کا خوف الگ، مولانا حالی نہ سید علی متقی بن سکتے تھے، نہ میر تقی بن سکتے تھے۔ عاشقوں اور صوفیوں کا دور گزر چکا تھا۔ یہ مصلحین کا دور تھا۔ واردات کی جگہ وعظ نے لے لی۔ مولانا حالی نے غزل سے کنارہ کیا اور اصلاحی شاعری پر آ رہے۔ فرزندان قوم کو نصیحت کی کہ عشق سے پرہیز کرو اور انگریزی پڑھو۔ فرزندان قوم نے نصیحت قبول کی۔ انگریزی پڑھی اور اصلاحی ادب پیدا کیا۔ عشق کا تقاضا ہوا تو جواب دیا کہ، مجھ سے پہلی سی محبت مرے محبوب نہ مانگ۔ یعنی ویسی محبت جس میں رکتے رکتے جنون ہو جاتا تھا اور گریبان کے چاک اور دامن کے چاک میں فاصلہ ختم ہو جاتا تھا۔ مگر محبت کسی قسم کی بھی ہو بہرحال محبت ہوگی۔ نئے شاعر کی بصیرت نے یہ نکتہ پیدا کیا۔
اور بھی غم ہیں زمانے میں محبت کے سوا
راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا
ترے ماتھے پہ یہ آنچل بہت ہی خوب ہے لیکن
تو اس آنچل سے اک پرچم بنا لیتی تو اچھا تھا
یہ اردو کی مخرب الاخلاق شاعری ہے۔ بات یہ ہے کہ اخلاقی ادب اور مخرب الاخلاق ادب کے بارے میں بہت سی باتیں مولویوں نے کہی ہیں۔ کچھ باتیں مولانا حالی اور ڈپٹی نذیر احمد نے کہیں۔ مگر ایک بات ڈی ایچ لارنس نے بھی کہی ہے۔ مگر ٹھہریے! اس سے پہلے ۳۶ء کے ادیبوں کا ایک اخلاقی محاکمہ سن لیجیے۔ جب ان کی مختلف نظموں اور افسانوں پر فحاشی کا الزام لگا تو انہوں نے بیان صفائی یوں دیا کہ جنس کے بیان میں اگر لذت کی کیفیت پیدا ہو جائے تو وہ فحاشی ہے مگر ہمارے افسانوں اور نظموں میں جنس ایک گھناؤنے پن کے ساتھ پیش ہوتی ہے، اس میں لذت کا رنگ ہوتا ہی نہیں، اس لئے اسے فحاشی نہیں کہا جا سکتا۔ مطلب اس کا یہ ہوا کہ جذبہ ایک گھناؤنی چیز ہے، اس سے بیزار رہنا ہی بھلا ہے۔ اور اب لارنس کی بات سنئے۔ وہ بات یہ ہے کہ جب لکھنے والا ترازو میں اپنا انگوٹھا اڑا دے اور پلڑے کو اپنے مطلب کے موافق جھکانے کی کوشش کرے تو یہ مخرب الاخلاق بات ہے۔
اور فیض صاحب نے ایک مخرب الاخلاق بات تو یہ کی کہ ترازو کے ایک پلڑے کو ڈنڈی پہ انگوٹھا رکھ کر جھکا دیا اور دوسری مخرب الاخلاق بات انہوں نے یہ کی کہ زندگی کے دکھوں میں تقسیم پیدا کر دی۔ دکھ بٹے ہوئے نہیں ہیں، سب دکھ اکٹھے ہیں۔ ایک دکھ دوسرے دکھ میں اور دوسرا دکھ تیسرے دکھ میں بندھا ہوا ہے۔ وہ سب ایک وحدت میں ڈھل کر زندگی کے غم کی صورت میں منور ہوتے ہیں۔ اگر آپ اس بات کو نہیں مانتے تو نتیجہ یہی ہوگا کہ یا تو آپ میر کو ایک فراری شاعر کہہ کر رد کر دیں گے، یا اس کے کلیات سے چند دوسرے بلکہ تیسرے درجہ کے شعر نکال کر یہ ثابت کریں گے کہ میر کو اپنے عہد کے مصائب کا بھی احساس تھا اور وہ سیاسی شعور بھی رکھتا تھا۔ مگر میر کے یہاں تو فرد کے دکھ اور عہد کے دکھ گھل مل کر میر کا غم بنے ہیں۔ سب دکھ ایک وحدت میں ڈھلے تو غم عشق بن گیا۔ اب آپ ایک دکھ کو دوسرے دکھ سے کیسے تمیز کریں۔
دل کی ویرانی کا کیا مذکور ہے
یہ نگر سو مرتبہ لوٹا گیا
اس شعر میں عہد کے غم اور ذات کے غم کو کیسے علاحدہ کریں گے اور غالب کے اس شعر کو آپ کس خانے میں ڈالیں گے،
اس چمن میں آگ برسے گی کہ آئے گی بہار
اک لہو کی بوند کیوں ہنگامہ آرا دل میں ہے
سیاسی شاعری کے خانے میں یا؟ عشقیہ شاعری کے خانے میں؟
قصہ اصل میں یہ ہے کہ باقی غم بھی تو عشق کے غم ہی کے واسطے سے سمجھ میں آتے ہیں،
پہنچا جو آپ تک تو وہ پہنچا خدا تئیں
معلوم اب ہوا کہ بہت میں بھی دور تھا
خدا تئیں اور عہد تئیں، اور اب پھر میں لارنس سے رجوع کرتا ہوں جس نے کہا تھا کہ انسانی معاملات میں سب سے بڑا رشتہ ہمیشہ مرد اور عورت والا رشتہ رہے گا۔ مرد اور مرد کا رشتہ، عورت اور عورت کا رشتہ، والدین اور اولاد کا رشتہ یہ سب ثانوی رشتے ہیں اور مرد اور عورت کا رشتہ ہر آن، ہر گھڑی بدلے گا اور ہر صورت انسانی زندگی کے لئے نئی کلید بنے گا۔ اور اہم نہ تو مرد ہے نہ عورت ہے اور نہ ان کے رشتے سے پیدا ہونے والے بچے ہیں۔ بلکہ خود یہ رشتہ اہم ہے۔۔۔ تو غزل اور داستان نے اس رشتے کو انسانی زندگی کی کلید جانا اور عشق کی واردات کے راستے سب انسانی رشتوں کو سمجھا اور حاصل یہ نکلا کہ بندہ بشر ہے اور آدمی کا شیطان آدمی ہے اور بھلا ہوا کہ تری سب برائیاں دیکھیں۔ پس، اے برے آ میں تجھ سے پیار کروں۔
یہ آخری بیان فراق کا ہے۔ مگر یہ وہ بصیرت ہے جو اسے کلاسیکی غزل سے ورثے میں ملی ہے اور اس عہد میں عاشق نے بہت گریباں چاک کئے اور صحراؤں کی خاک اڑائی اور دیواروں سے سر پھوڑے مگر کچھ حاصل نہ ہوا۔ باپوں نے بیٹوں کو نصیحت کی کہ بیٹا عشق کیا کرو اور بیٹوں نے عشق کیا۔ ان بیٹوں نے بھی جنہوں نے واحد صداقت جذبے کو جانا اور ان بیٹوں نے بھی جنہوں نے عقل و دانش کو سر پر چڑھایا۔ ہاں ایک بصیرت حاصل ہوئی۔ آدمی کے بارے میں ایک بصیرت۔ پچھلی غزل اور داستان کا سرمایہ یہی بصیرت ہے۔ اصلاحی دور اور ترقی پسند دور کے ادب کا سرمایہ درس ہے۔ آج کے لکھنے والے کے لئے یہ دونوں رستے کھلے ہیں۔ وہ چاہے تو درس والا رویہ اپنا لے، اس واسطے سے اسے ادب پیدا کرنے کے مقبول عام نسخے میسر آ جائیں گے اور ادب پیدا کرنے کا کام آسان ہو جائے گا اور چاہے تو وہ اول الذکر رستے کو اپنا لے۔ مگر وہ رستہ کٹھن ہے۔ واردات کے رستے بصیرت کی منزل تک پہنچنے کا عمل ہے۔
(ممتاز فکشن رائٹر اور انتظار حسین کی تحریر)