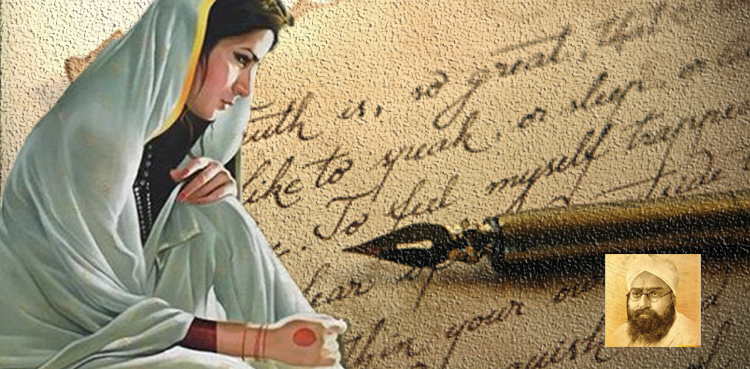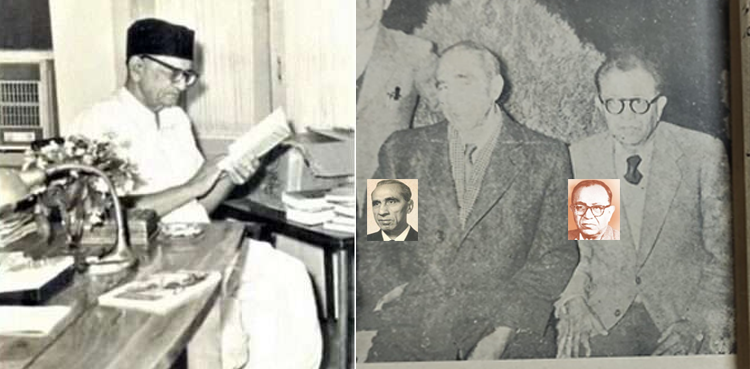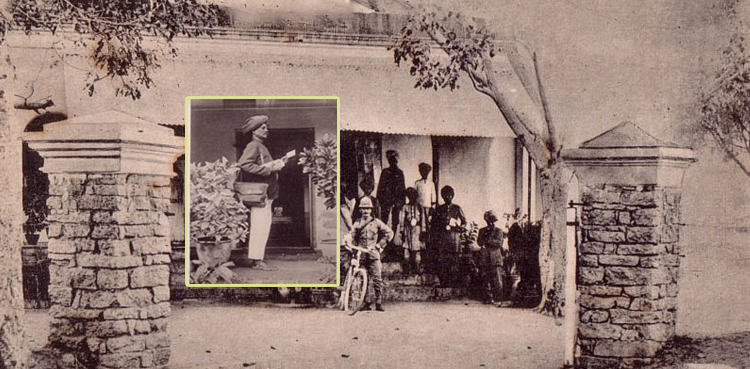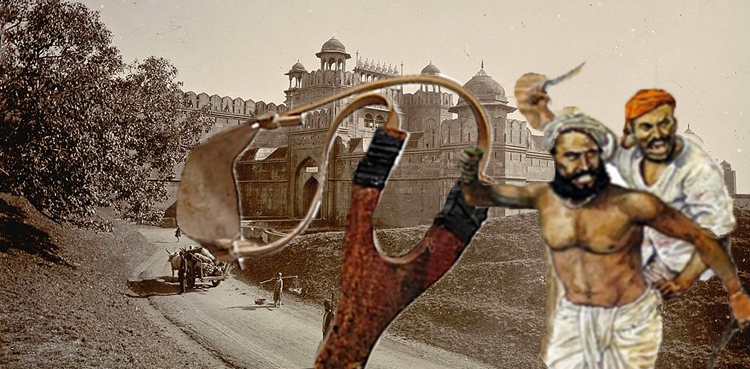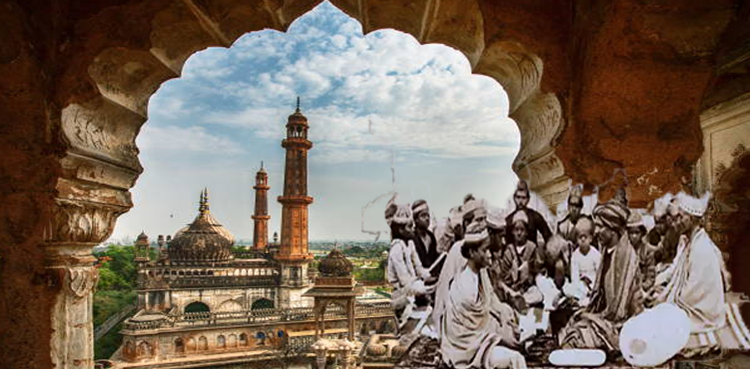انگریزوں کے متعلق یہ مشہور ہے کہ وہ طبعاً کم گو واقع ہوئے ہیں۔
میرا خیال ہے کہ وہ فقط کھانے اور دانت اکھڑوانے کے لیے منھ کھولتے ہیں۔ بلکہ یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ اگر انگلستان کا موسم اتنا واہیات نہ ہوتا تو انگریز بولنا بھی نہ سیکھتے اور انگریزی زبان میں کوئی گالی نہ ہوتی۔ کم و بیش یہی حال ہم اہلیانِ کراچی کا ہے۔ میں اپنے شہر کی برائی کرنے میں کوئی بڑائی محسوس نہیں کرتا۔ لیکن میرا خیال ہے جو شخص کبھی اپنے شہر کی برائی نہیں کرتا وہ یا تو غیر ملکی جاسوس ہے یا میونسپلٹی کا بڑا افسر! یوں بھی موسم، معشوق اور حکومت کا گلہ ہمیشہ سے ہمارا قومی تفریحی مشغلہ (INDOOR PASTIME) رہا ہے۔ ہر آن بدلتے ہوئے موسم سے جس درجہ شغف ہمیں ہے اس کا اندازہ یوں لگائیے کہ یہاں بہت سے نجومی ہاتھ دیکھ کر آئندہ چوبیس گھنٹوں کے موسم کی پیش گوئی کرتے ہیں اور الغاروں کماتے ہیں۔
اب سے چند مہینے پہلے تک بعض گرم و سرد چشیدہ سیاست دان خرابیِ موسم کو آئے دن وزارتی رد و بدل کا ذمہ دار ٹھیراتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ کراچی کا موسم بھی انگریز ہی کی ایک چال ہے۔ لیکن موسم گزیدہ عوام کو یقین ہو چلا تھا کہ در حقیقت وزارتی رد و بدل کے سبب یہاں کا موسم خراب ہو گیا ہے۔ نظرِ انصاف سے دیکھا جائے تو موسم کی برائی تہذیب اخلاق کا ایک مؤثر ذریعہ ہے۔ اس لیے کہ اگر موسم کو برا بھلا کہہ کر دل کا غبار نکالنا شہری آداب میں داخل نہ ہوتا تو لوگ مجبوراً ایک دوسرے کو گالیاں دینے لگتے۔
اس میں شک نہیں کہ ریڈیو کی گڑگڑاہٹ ہو یا دمہ، گنج ہو یا پاؤں کی موچ، ناف ٹلے یا نکسیر پھوٹے، ہمیں یہاں ہر چیز میں موسم کی کارفرمائی نظر آتی ہے۔ بلغمی مزاج والا سیٹھ ہو یا سودائی فن کار، ہر شخص اسی بت ہزار شیوہ کا قتیل ہے۔ کوئی خرابی ایسی نہیں جس کا ذمہ دار آب و ہوا کو نہ ٹھیرایا جاتا ہو (حالانکہ اکثریت ایسے لوگوں کی ہے جن کو خرابیٔ صحت کی وجہ سے موسم خراب لگتا ہے۔)
ایک صاحب کو جانتا ہوں جنہیں عرصہ سے بنولے کے سٹہ کا ہوکا ہے۔ وہ بھی کراچی کی مرطوب آب و ہوا ہی کو اپنے تین دوالوں کا ذمہ دارقرار دیتے ہیں۔ ایک اور بزرگ کا دعویٰ ہے کہ میں اپنی بتیسی اسی نامعقول آب و ہوا کی نذر کر چکا ہوں۔ دیکھنےمیں یہ بات عجیب ضرور لگتی ہے مگر اپنے مشاہدے کی بناپر کہتا ہوں کہ اس قسم کی آب و ہوا میں چائے اور سٹہ کے بغیر تندرستی قائم نہیں رہ سکتی۔ اور تو اور چالان ہونے کے بعد اکثر پنساری اپنی بے ایمانی کو ایمائے قدرت پر محمول کرتے ہوئے اپنی صفائی میں کہتے ہیں کہ ’’حضور! ہم موسم کی خرابی کی وجہ سے کم تولتے ہیں۔ سیلن سے جنس اور دالوں کا وزن دگنا ہو جاتا ہے اور زنگ کھا کھا کر باٹ آدھے رہ جاتے ہیں۔ نتیجہ میں گاہک کو ۱/۴سودا ملتا ہے! ہم بالکل بے قصور ہیں۔‘‘
ایک اور ایک کفایت شعار خاتون (جنھوں نے پچھلے ہفتہ اپنی 32 ویں سالگرہ پر 23 موم بتیاں روشن کی تھیں) اکثر کہتی ہیں کہ دس سال پہلے میں گھنٹوں آئینے کے سامنے کھڑی رہتی تھی۔ لیکن یہاں کی آب و ہوا اتنی واہیات ہے کہ اب بے خبری میں آئینے پر نظر پڑ جاتی ہے تو اس کی ’’کوالٹی‘‘ پر شبہ ہونے لگتا ہے۔
لیکن غصہ ان حضرات پر آتا ہے جو بے سوچے سمجھے یہاں کے موسم پر نکتہ چینی کرتے ہیں اور اس کی وضاحت نہیں فرماتے کہ انہیں کون سا موسم ناپسند ہے۔
یہ تو آپ جانتے ہیں کہ کراچی میں موسم ہر لحظہ روئی کے بھاؤ کی طرح بدلتا رہتا ہے۔ ہم نے تو یہاں تک دیکھا ہے کہ ایک ہی عمارت کے کرایہ دار ایک منزل سے دوسری منزل پر تبدیل آب و ہوا کی غرض سے جاتے ہیں۔ یہاں آپ دسمبر میں ململ کا کرتہ یا جون میں گرم پتلون پہن کر نکل جائیں تو کسی کو ترس نہیں آئے گا۔ اہلِ کراچی اس واللہ اعلم بالصواب قسم کے موسم کے اس قدر عادی ہوگئے ہیں کہ اگر یہ دو تین گھنٹے تبدیل نہ ہو تو وحشت ہونے لگتی ہے اور بڑی بوڑھیاں اس کو قربِ قیامت کی نشانی سمجھتی ہیں۔
ہوتا یہ ہے کہ اچھے خاصے لحاف اوڑھ کر سوئے اور صبح پنکھا جھلتے ہوئے اٹھے۔ یا محکمہ موسمیات کی پیش گوئی کو ملحوظ رکھتے ہوئے صبح برساتی لے کر گھر سے نکلے اور دوپہر تک لو لگنے کے سبب بالا ہی بالا اسپتال میں داخل کرا دیے گئے۔ کہاں تو رات کو ایسی شفاف چاندنی چھٹکی ہوئی تھی کہ چارپائی کی چولوں کے کھٹمل گن لیجیے۔ اور کہاں صبح دس بجے کہرے کا یہ عالم کہ ہر بس ہیڈ لائٹ جلائے اور اوس سے بھیگی سڑک پر خربوزے کی پھانک کی طرح پھسل رہی ہے۔ بعض اوقات تو یہ کہرا اتنا گہرا ہوتا ہے کہ نوواردوں کو کراچی کا اصل موسم نظر نہیں آتا۔ موسم کے تلون کی یہ کیفیت ہے کہ دن بھر کے تھکے ہارے پھیری والے شام کو گھر لوٹتے ہیں تو بغیر استخارہ کیے یہ فیصلہ نہیں کرسکتے کہ صبح اٹھ کر بھول بل کی بھنی گرما گرم مونگ پھلی بیچیں یا آئس کریم!
کراچی کے باشندوں کو غیر ملکی سیر و سیاحت پر اکسانے میں آب و ہوا کو بڑا دخل ہے۔ یہ ایک تاریخی حقیقیت ہے کہ انگلستان کا موسم اگر اتنا ظالم نہ ہوتا تو انگریز دوسرے ملکوں کو فتح کرنے ہرگز نہ نکلتے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ محض میری صحت دیکھ کر یہاں کی آب و ہوا سے بدظن ہو جائیں۔ لیکن اطلاعاً اتنا ضرور عرض کروں گا کہ مقامی چڑیا گھر میں جو بھی نیا جانور آتا ہے، کچھ دن یہاں کی بہارِ جاں فزا دیکھ کر میونسپل کارپوریشن کو پیارا ہوجاتا ہے اور جو جانور بچ جاتے ہیں، ان کا تعلق اس مخلوق سے ہے جس کو طبعی موت مرتے کم از کم میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ مثلاً مگرمچھ، ہاتھی، میونسپلٹی کا عملہ!
(ممتاز مزاح نگار مشتاق یوسفی کی ایک تحریر سے چند پارے)