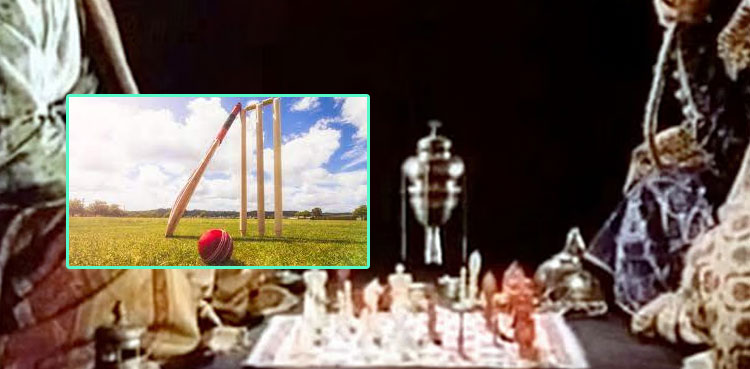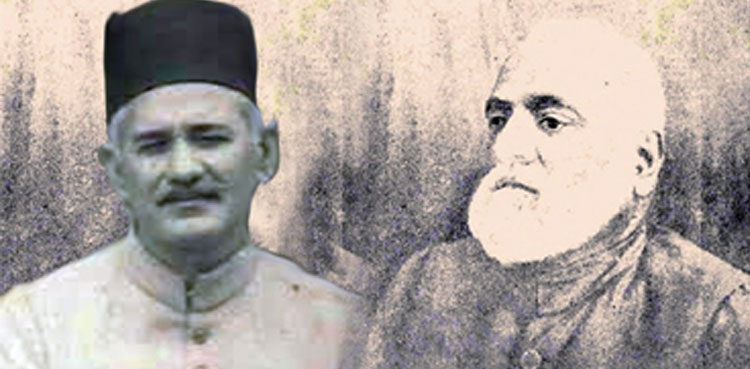محبت فطری و بنیادی چیز ہے۔ نفرت… انقطاعِ محبت کا نام ہے، جو کسی حادثہ و تصادم کا نتیجہ ہوتی ہے۔
محبت تمام نیکیوں کا سرچشمہ اور تمام جذباتِ عالیہ کی خالق ہے، اسی سے آواز میں لوچ، بات میں شیرینی، چہرے پر حُسن، رفتار میں انکسار اور کردار میں وسعت آتی ہے۔
دوسری طرف غصہ، نفرت، انتقام اور حسد دنیائے دل کو ویران اور چہرے کو بے نور اور خوف ناک بنا دیتے ہیں۔ حاسد اور سازشی کی رفتار تک نا ہموار ہو جاتی ہے، وہ ہر طرف نفرت پھیلاتا ہے۔ اہلِ محبّت، نفرت کا جواب محبت سے دیتے ہیں۔ وہ اس حقیقت کو جانتے ہیں: ”دنیا سے بہترین سلوک کرو اور جواباً تم سے بہترین سلوک کیا جائے گا۔“
جن لوگوں کے دل میں اللہ بس جاتا ہے ان کی پہچان ہی یہی ہے کہ وہ ہر شخص سے محبت کرتے ہیں۔ خطا کاروں کی خطائیں بخشتے ہیں اور گالیوں کے جواب میں دعائیں دیتے ہیں۔ کسی مفکر کا قول ہے: ”نفرت سے نفرت ختم نہیں ہو سکتی، اس پر محبت سے غلبہ حاصل کرو، دنیا کو محبت کرنا سکھاؤ اور جنت اپنی تمام رنگینیوں اور رعنائیوں کے ساتھ یہیں وارد ہو جائے گی۔ ترکِ محبت موت ہے، جو شخص سب سے محبت کرتا ہے اس کی زندگی بھرپور اور کامل ہے اور اس کی زیبائی و توانائی میں سدا اضافہ ہوتا رہے گا۔“
محبت کا سب بڑا وصف انکسار ہے۔ دوسروں سے نفرت کرنے والے کرخت، مغرور، تند مزاج اور بدمزاج ہوتے ہیں اور اہلِ محبت بول میں میٹھے، چال میں دھیمے اور مزاج کے نرم ہوتے ہیں۔ اس میں قطعاً کوئی کلام نہیں کہ غرور حماقت ہے اور تواضع بہت بڑی دانش۔
کسی دانا کا قول ہے: ”اگر دانش حاصل کرنا چاہتے ہو تو انکسار پیدا کرو اور اگر حاصل کر چکے تو زیادہ خاکسار بنو۔“
(’مَن کی دنیا‘ از ڈاکٹر غلام جیلانی برق سے اقتباس)