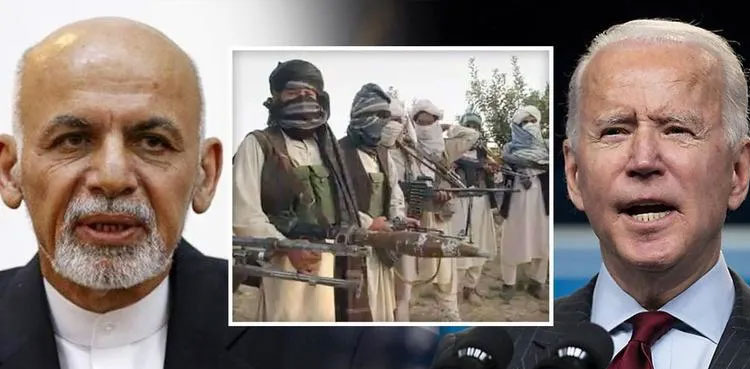بارش، جو کبھی خوشحالی اور زرخیزی کی علامت سمجھی جاتی تھی، اب تباہی، سیلاب اور انسانی المیوں کو جنم دے رہی ہے۔ دنیا کے مختلف خطوں میں معمول سے ہٹ کر ہونے والی شدید بارشیں ایک نئے اور غیر متوقع مظہر کی صورت اختیار کر چکی ہیں، جسے سائنسدان موسمیاتی تبدیلی کا براہِ راست نتیجہ قرار دے رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا واقعی بارشوں کے اس بگڑتے ہوئے انداز کا تعلق عالمی درجۂ حرارت میں اضافے سے ہے؟ اور اگر ہاں، تو کیا ہم اس کے لیے تیار ہیں؟
ماہرین کے مطابق زمین کا ماحولیاتی نظام نہایت متوازن اور حساس ہے۔ جب فضا میں کاربن ڈائی آکسائیڈ، میتھین اور دیگر گرین ہاؤس گیسوں کی مقدار بڑھتی ہے، تو نہ صرف درجۂ حرارت میں اضافہ ہوتا ہے بلکہ فضائی نمی میں بھی غیر معمولی تبدیلی آتی ہے۔ نیشنل اوشینک اینڈ ایٹموسفیرک ایڈمنسٹریشن (NOAA) کے مطابق، ہر ایک ڈگری سیلسیئس درجۂ حرارت کے اضافے کے ساتھ فضا میں 7 فیصد زیادہ نمی جذب ہو سکتی ہے، جو مستقبل میں شدید بارشوں اور طوفانی موسم کی شدت کو بڑھا سکتی ہے۔
بین الحکومتی پینل برائے موسمیاتی تبدیلی کی جانب سے جاری کردہ رپورٹ (2023) میں خبردار کیا گیا کہ ہر گزرتے عشرے کے ساتھ دنیا میں بارش کے پیٹرن میں شدت، طوالت اور بے ترتیبی بڑھ رہی ہے جس کے نتیجے میں جنوبی ایشیا، وسطی افریقہ اور لاطینی امریکہ سب سے زیادہ متاثر ہو رہے ہیں۔ عالمی موسمیاتی تنظیم کی 2024 کی رپورٹ میں بتایا گیا کہ عالمی درجۂ حرارت 1.5 ڈگری کے قریب پہنچ چکا ہے، اور اس کی وجہ سے بارش کے سائیکل میں غیر معمولی تبدیلی آئی ہے۔ کہیں طوفانی بارشیں ہیں، تو کہیں مکمل خشک سالی۔
اقوام متحدہ کے ماحولیاتی پروگرام کی 2025 کی رپورٹ میں کہا گیا کہ پاکستان جنوبی ایشیا کے ان پانچ ممالک میں شامل ہے جو شدید بارشوں اور اس کے نتیجے میں ہونے والے اربن فلڈنگ، مٹی کے تودے گرنے اور زرعی تباہی کے سب سے زیادہ خطرات سے دوچار ہیں جب کہ اقوام متحدہ کے ماحولیاتی پروگرام اور آئی ایم ایف کی 2024 کی مشترکہ تحقیق میں بتایا گیا کہ غیر متوقع بارشیں ترقی پذیر ممالک کی معیشت کو ہر سال اوسطاً 235 ارب ڈالر کا نقصان پہنچا رہی ہیں، جن میں زراعت، انفراسٹرکچر اور انسانی جان و مال شامل ہے۔
رواں اور گذشتہ سال کے چند بڑے واقعات کا ذکر کیا جائے تو رواں سال میں برازیل کے جنوبی علاقہ (ریو گراندے دو سل) مئی میں مسلسل دو ہفتے کی طوفانی بارشوں سے 170 افراد ہلاک اور 6000 سے زائد مکانات تباہ ہوئے جب کہ تقریباً 3.4 ارب ڈالر کا نقصان ہوا۔ چین کے صوبہ ہنان میں جولائی کے آغاز میں آنے والی صرف 5 دن کی بارش نے 12 اضلاع کو ڈبو دیا۔ نقصان کا اندازہ 2 ارب ڈالر کے قریب لگایا گیا، 200,000 افراد بے گھر ہوئے۔ 2024 میں پاکستان کے صوبے بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں شدید بارشیں ہوئیں، مارچ تا جون غیر متوقع بارشوں اور ژالہ باری سے فصلیں تباہ ہوئیں اور معاشی نقصان کا تخمینہ تقریباً 180 ارب روپے (تقریباً 630 ملین ڈالر) لگایا گیا۔ جرمنی اور بیلجیم میں دریائے رائن کے کنارے شدید بارشوں سے صنعتی علاقے متاثر ہوئے۔ نقصان کا اندازہ 1.2 ارب یورو۔
رواں سال مون سون سیزن کے دوران پاکستان شدید بارشوں اور سیلابی صورتحال کا سامنا کر رہا ہے۔ این ڈی ایم اے اور مختلف میڈیا رپورٹس کے مطابق اب تک 279 افراد جاں بحق اور 676 زخمی ہو چکے ہیں۔ پنجاب سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے جہاں 151 افراد ہلاک اور سیکڑوں زخمی ہوئے، جب کہ خیبر پختونخوا میں 64، بلوچستان میں 20، سندھ میں 25، گلگت بلتستان میں 9، اسلام آباد میں 8 اور آزاد کشمیر میں 2 اموات رپورٹ ہوئی ہیں۔ شدید بارشوں نے نہ صرف انسانی جانیں لیں بلکہ 1,500 سے زائد مکانات کو تباہ کر دیا یا ان کو نقصان پہنچایا، 370 کے قریب مویشی ہلاک ہوئے اور کئی اہم انفراسٹرکچر، سڑکیں اور پل منہدم ہو گئے۔
جولائی کے وسط تک ملک میں ہونے والی بارشیں گزشتہ برس کے مقابلے میں 82 فیصد زیادہ ریکارڈ کی گئیں، جب کہ پہاڑی علاقوں میں شدید گرمی کے باعث گلیشیئر کے پگھلنے سے بھی فلش فلڈز اور گلیشیئر لیک آؤٹ برسٹ فلڈز (GLOFs) کے واقعات میں اضافہ ہوا۔ ماہرین کے مطابق ملک کے شمالی علاقوں میں مزید شدید بارشوں اور لینڈ سلائیڈنگ کے خطرات موجود ہیں، جو آنے والے ہفتوں میں صورتحال کو مزید پیچیدہ بنا سکتے ہیں۔
ورلڈ میٹررو لوجیکل آرگنائزیشن (WMO) کی 2025 کی رپورٹ کے مطابق شدید بارشوں کے بڑھتے ہوئے واقعات کا براہِ راست تعلق ماحولیاتی تبدیلی سے ہے۔ موجودہ صدی کے وسط تک ایسے واقعات کی شدت دو گنا ہونے کا امکان ہے۔ رواں سال اقوام متحدہ کے ماحولیاتی پروگرام کی رپورٹ میں کہا گیا کہ پاکستان جنوبی ایشیا کے ان پانچ ممالک میں شامل ہے جو شدید بارشوں اور اس کے نتیجے میں ہونے والے اربن فلڈنگ، مٹی کے تودے گرنے اور زرعی تباہی کے سب سے زیادہ خطرات سے دوچار ہیں۔ فوڈ اینڈ ایگری کلچر آرگنائزیشن کے مطابق، 2025 میں صرف پاکستان اور بھارت میں زرعی پیداوار میں 11% کمی کا اندیشہ ہے۔ اقوام متحدہ کے مطابق، موسمیاتی تبدیلی سے پیدا ہونے والے سیلاب اور بارشوں کے باعث 2024 میں تقریباً 33 ملین افراد نے اندرونِ ملک نقل مکانی کی۔
یہ صورتِ حال شہری نظام پر مزید دباؤ بڑھا رہی ہے جس کے نتیجے میں ایک نیا بحران جنم لے رہا ہے۔ پاکستان کے بڑے شہر پہلے ہی ماحولیاتی دباؤ، بے ہنگم آبادی، ناقص منصوبہ بندی اور بنیادی ڈھانچے کی خستہ حالی کا شکار ہیں۔ جب اچانک موسلا دھار بارش ہوتی ہے تو نکاسی آب کا نظام بیٹھ جاتا ہے، کرنٹ لگنے کے حادثات ہوتے ہیں، بجلی، مواصلات اور آمدورفت کا نظام درہم برہم ہو جاتا ہے، کچی بستیوں میں مکانات گرنے اور اموات کے واقعات بڑھ جاتے ہیں۔
بدلتے موسموں کے نتیجے میں پیدا ہونے والی اس صورتحال سے نپٹنے کے لیے جو ملکی معیشت کو ناقابل تلافی نقصان پہنچانے کا سبب بن چکی ہے۔ ہمارے پالیسی سازوں کو جنگی بنیادوں پر حکمت عملی اپناتے ہوئے اقدامات کرنے ہوں گے جیسے شہری سیلابی نقشے (Urban Flood Maps) بنانا ہوں گے جو ہر بڑے شہر کے لیے خطرے کے زون کی نشاندہی کریں۔ اس کے علاوہ نالوں کی صفائی کے ساتھ ان پر قائم تجاوزات کا خاتمہ، بارش کے پانی کا ذخیرہ، اور مقامی وارننگ سسٹمز کی تنصیب، شجر کاری و سبز انفراسٹرکچر، شہروں میں پارکس، کھلی زمین اور قدرتی نالے کو محفوظ کرنا ہو گا تاکہ پانی جذب ہو سکے۔ موسمیاتی تبدیلی سے متعلق ڈیزاسٹر مینجمنٹ بلز کو نافذ کیا جائے اور اور اس حوالے سے فنڈنگ یقینی بنائی جائے۔
بارشوں کا تیز اور غیر متوقع انداز موسمیاتی تبدیلی کی زندہ مثال ہے۔ اگرچہ بارش ایک قدرتی عمل ہے، مگر اس بات میں اب کوئی دو رائے نہیں رہی کہ اس کی شدت، وقت، مقام اور اثرات میں جو تبدیلی آ رہی ہے وہ واضح طور پر انسانی سرگرمیوں سے جڑی ہے جس کے نتیجے میں موسمیاتی تبدیلی رونما ہوئی۔ پاکستان جیسے ممالک، جہاں وسائل کم اور خطرات زیادہ ہیں، وہاں مؤثر منصوبہ بندی، سائنسی حکمتِ عملی اور مقامی سطح پر عوام کی شرکت ہی ہمیں ان بارشوں کو ”رحمت” بنائے رکھنے میں مدد دے سکتی ہے۔ ورنہ یہ ”عذاب” بن کر ہمارے دروازے پر دستک دے رہی ہیں۔


 دنیا بھر میں اس وقت یہ ویب سیریز دیکھی جارہی ہے اور اس نے مقبولیت کے نئے ریکارڈ قائم کیے ہیں۔ 80 کی دہائی میں اسی کہانی پر ایک مختصر ڈراما سیریز بنی تھی، جس کو پاکستان ٹیلی وژن پر بھی قسط وار دکھایا گیا تھا۔ سترہویں صدی کے جاپان پر مبنی امریکی ویب سیریز کا اردو میں یہ واحد مفصل تجزیہ اور باریک بینی سے کیا گیا تبصرہ پیشِ خدمت ہے۔
دنیا بھر میں اس وقت یہ ویب سیریز دیکھی جارہی ہے اور اس نے مقبولیت کے نئے ریکارڈ قائم کیے ہیں۔ 80 کی دہائی میں اسی کہانی پر ایک مختصر ڈراما سیریز بنی تھی، جس کو پاکستان ٹیلی وژن پر بھی قسط وار دکھایا گیا تھا۔ سترہویں صدی کے جاپان پر مبنی امریکی ویب سیریز کا اردو میں یہ واحد مفصل تجزیہ اور باریک بینی سے کیا گیا تبصرہ پیشِ خدمت ہے۔


 اداکاری
اداکاری