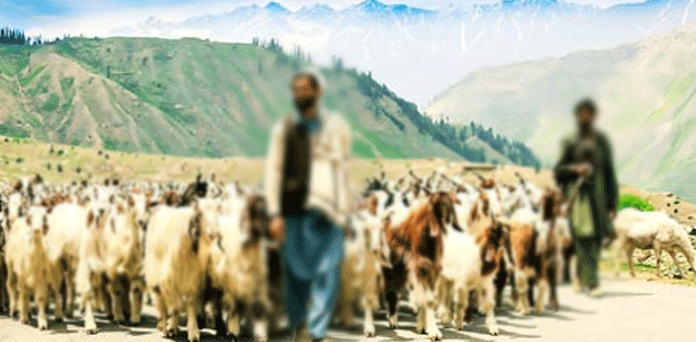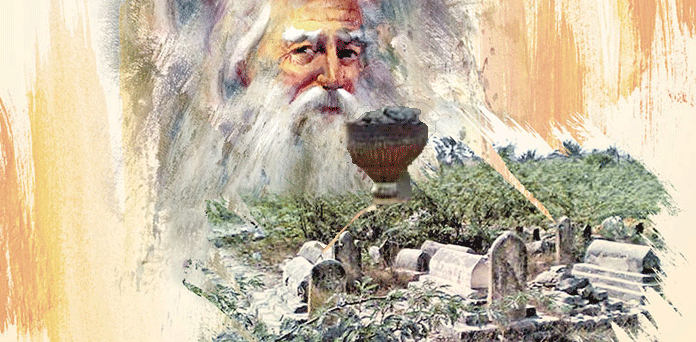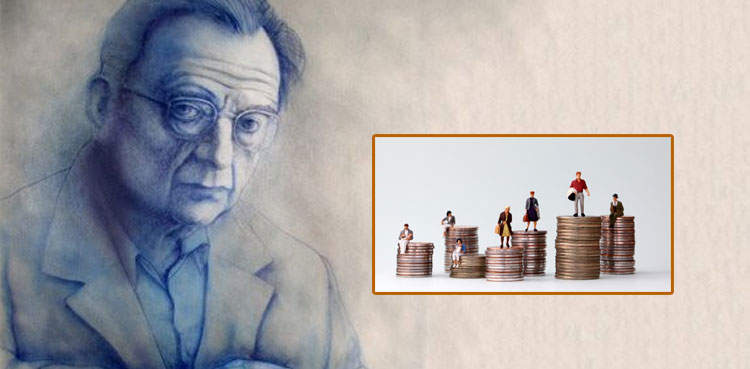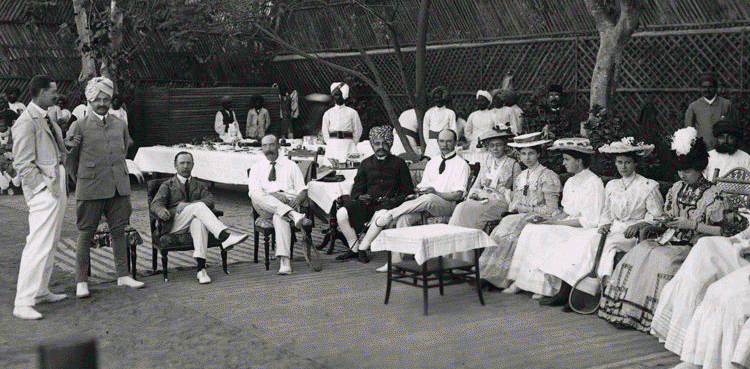اردو ادب کی بے مثال اور لاجواب تحریروں اور حکمت و دانائی، فلسفہ و فکر کے موتیوں سے بھرے ہوئے مضامین میں انشائیہ نگاری کو امتیازی حیثیت حاصل ہے۔ اردو ادب میں ڈاکٹر وزیر آغا کو دانش ور اور باکمال انشائیہ نگار کے طور پر دیکھا جاتا ہے اور یہ انہی کا ایک خوب صورت انشائیہ ہے۔
چرواہے کی چھڑی دراصل ہوا کا ایک جھونکا ہے اور ہوا کے جھونکے کو مٹھی میں بند کرنا ممکن نہیں۔ اسے تو دیکھنا بھی ممکن نہیں۔
البتہ جب وہ آپ کے بدن کو مَس کرتے ہوئے گزرتا ہے تو آپ اس کے وجود سے آگاہ ہو جاتے ہیں۔ وجود ہی سے نہیں آپ اس کی صفات سے بھی آگاہ ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ بنیادی طور پر ہر جھونکا ایک پیغام بر ہے۔ وہ ایک جگہ کی خوشبو کو دوسری جگہ پہنچاتا ہے۔ یہی کام چرواہے کا بھی ہے۔ تمام لوگ گیت چرواہوں کے ہونٹوں پر لرزتے ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرتے رہے ہیں۔ کہا گیا ہے کہ بہت قدیم زمانے میں قبائل نے جو نقل مکانی کی، اس کے بارے میں تاریخی کوائف ناپید ہیں، البتہ جن راستوں سے یہ قبیلے گزرے اور جن خطوں میں چند روز ٹھہرے وہاں انہوں نے اپنے نقوش پا چھوڑ دیے جنہیں آج بھی ’’پڑھا‘‘ جا سکتا ہے۔ یہ نقوشِ پا وہ منورّ الفاظ ہی ہیں جو ان کے ہونٹوں سے ٹپکے اور پھر راستوں اور خطّوں میں بولی جانے والی زبانوں کے دامن پر کہیں نہ کہیں موتیوں کی طرح اٹک کر رہ گئے اور صدیوں تک اپنے بولنے والوں کے سفر کی داستان سناتے رہے… مگر لوک گیتوں کا قصّہ دوسری نوعیت کا ہے۔
لوک گیت قبیلوں کے نہیں بلکہ چرواہوں کے نقوشِ پا ہیں۔ ان سے پتہ چلتا ہے کہ کسی خطّے کا چرواہا کہاں کہاں پہنچا کیونکہ وہ جہاں کہیں گیا اپنے ساتھ گیت کی لَے اور خوشبو اور تمازت بھی لے گیا۔ پھر وہ خود تو وقت کی دست بُرد سے محفوظ نہ رہ سکا اور مآلِ کار زمین کا رزق بن گیا مگر اس کا گیت ایک لالۂ خود رو کی طرح عہد بہ عہد اس خطّے کی زمین سے برآمد ہوتا اور خوشبو پھیلاتا رہا۔ بس یہی چروا ہے کا وصفِ خاص ہے کہ وہ جگہ جگہ گیتوں کے بیج بکھیرتا پھرتا ہے… بیج جو اس کے نقوشِ پا ہیں، جنہیں وقت کا بڑے سے بڑا سیلاب بھی نابود نہیں کر سکتا۔
ویسے عجیب بات ہے کہ چرواہے کے مسلک کو آج تک پوری طرح سمجھا ہی نہیں گیا، مثلاً اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ گلّے کا رکھوالا بھی ہے اور پولیس مین بھی! یعنی وہ اپنی چھڑی کی مدد سے ہر اُس زمینی یا آسمانی بلا پر ٹوٹ پڑتا ہے جو اس کے گلّے کو نظر بد سے دیکھتی ہے اور اسی چھڑی سے وہ گلّے سے بھٹکی ہوئی ہر بھیڑ کو راہِ راست پر لانے کی کوشش بھی کرتا ہے۔ مگر کیا چرواہے کا مقصدِ حیات صرف یہی ہے؟…غالباً نہیں! وجہ یہ کہ جب چرواہا گلّے کو لے کر روانہ ہوتا ہے تو اُسے مجبوراً اِسے سیدھی لکیر پر چلانا پڑتا ہے تا کہ ریوڑ بحفاظت منزلِ مقصود تک پہنچ جائے۔ واپسی پر بھی اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اپنی تمام بھیڑوں کو سمیٹ کر یک مُشت کر دے تا کہ وہ بغیر کسی حادثے کے اپنے گھر پہنچ جائیں۔ مگر یہ تو سفر کے بالکل عارضی سے مراحل ہیں۔ اصل اور دیرپا مرحلہ وہ ہے جب چرواہا اپنے گلّے کو کسی سر سبز و شاداب میدان، جھاڑیوں سے اٹے ہوئے صحرایا کسی پہاڑ کی ڈھلان پر لا کر آزاد کر دیتا ہے۔ جس طرح تسبیح کا دھاگا ٹوٹ جائے تو منکے فرشِ خاک پر گرتے ہی لڑھکنے اور بکھرنے لگتے ہیں، بالکل اسی طرح جب گڈریا اپنے ریوڑ کو آزاد کر تا ہے تو وہ دانہ دانہ ہو کر بکھر جاتا ہے۔ معاً ہر بھیڑ کی ایک اپنی منفرد شخصیت وجود میں آ جاتی ہے۔ گلّے کے شکنجے سے آزاد ہوتے ہی ہر بھیڑ محسوس کرتی ہے کہ بے کنار آسمان اور لامحدود زمین کے عین درمیان وہ اب یکہ و تنہا کھڑی مرکزِ دو عالم بن گئی ہے۔ مگر بات محض بھیڑوں ہی کی نہیں۔
خود چرواہے کو بھی محسوس ہوتا ہے کہ وہ اپنے بدن کے حصار سے باہر آکر چاروں طرف بکھرنے لگا ہے، جیسے اس کے ہاتھ یکایک اتنے لمبے ہو گئے ہیں کہ وہ اپنی جگہ سے جنبش کیے بغیر ہی درخت کی پھُننگ، پہاڑ کی چوٹی اور ابر پارے کی جھالر کو چھو سکتا ہے بلکہ پتھّروں، پودوں اور پرندوں حتیٰ کہ رنگوں اور روشنیوں سے بھی ہم کلام ہو سکتا ہے۔ کسان بے چارے کو تو زمین نے جکڑ رکھا ہے اور بنیے کو زر نے، مگر چرواہا ایک مردِ آزاد ہے، وہ اپنے گلّے کا بھی مطیع نہیں۔ وہ میدان یا پہاڑ کی ڈھلوان پر پہنچتے ہی اپنی مٹھی کھول دیتا ہے اور سارا گلاّ اس کی انگلیوں کی جھریوں سے دانہ دانہ ہو کر ہر طرف بکھر جاتا ہے، اس کے بعد وہ خود بھی بکھرنے لگتا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے خاک و افلاک پر ایک ردا سی بن کر چھا جاتا ہے، مگر چرواہا آخر چرواہا ہے، اس کا کام محض بکھرنا ہی نہیں سمٹنا بھی ہے۔
چنانچہ شام ہوتے ہی وہ پہلے اپنی چھڑی کو جسم عطا کرتا ہے، پھر خود کو تنکا تنکا جمع کرتا ہے۔ مجتمع ہونے، بکھرنے اور دوبارہ جڑ جانے کا یہ عمل جس سے چرواہا ہر روز گزرتا ہے، پوری کائنات کے طرزِ عمل سے مشابہ ہے، مگر یہ دوسرا قِصّہ ہے۔ چرواہے کئی طرح کے ہیں۔ ایسے چرواہے بھی ہیں جو محض مزدوری کرتے ہیں۔ سارا دن مویشیوں کو ہانکنے کے بعد رات کو تھکے ہارے واپس آتے ہیں اور کھاٹ پر گرتے ہی بے سُدھ ہو جاتے ہیں۔ ایسے چرواہوں کو چرواہا کہنا بھی زیادتی ہے۔ پھر ایسے چرواہے بھی ہیں جو چناب کنار بھینسوں یا گائیوں کو چراتے پھرتے ہیں مگر یہ لوگ بھی چرواہے کم اور پریمی زیادہ ہیں۔ گائیوں بھینسوں سے ان کا سارا لگاؤ محض ایک بہانہ ہے۔ وہ دراصل ان کی وساطت سے زیادہ نازک اور خوبصورت گائیوں بھینسوں تک رسائی پانے کے آرزو مند ہوتے ہیں، چنانچہ جب عشق کے انتہائی مراحل میں ان کے گرد جو اپنوں یا خوشیوں کا حلقہ تنگ ہو جاتا ہے تو انہیں یاد بھی نہیں رہتا کہ ان کی اصل گائیں بھینسیں نجانے کب سے ان کی راہ تک رہی ہیں… میں اس قسم کے چرواہوں کا ذکر کر کے آپ کا قیمتی وقت ضائع کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا، میں تو صرف ان چرواہوں کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جو مویشیوں کے ریوڑ چراتے چراتے ایک روز انسانوں کے ریوڑ چرانے لگتے ہیں۔ تب ان کی چھڑی عصا میں بدل جاتی ہے۔ ہونٹوں پر اسمِ اعظم تھرکنے لگتا ہے۔ وہ انسانی ریوڑوں کو پہاڑ کی چوٹی پر لا کر یا صحرا کے سینے میں اتار کر یا دریا کے کناروں پر بکھیر کر اس بات کا انتظار کرتے ہیں کہ یہ ریوڑ اپنی کہنگی اور یبوست کو گندی اُون کی طرح اپنے جسموں سے اتار پھینکیں۔ پھر جب وہ دیکھتے ہیں کہ ایسا ہو گیا ہے تو وہ انہیں واپس ان کے گھروں تک لے آتے ہیں۔ اس کے بعد وہ خود تسبیح کے دانوں کی طرح پوری کائنات میں بکھر جاتے ہیں۔
یہ جو بساطِ فلک پر ہر رات کروڑوں ستارے سے چمکتے ہیں، کیا آپ کو معلوم ہے کہ یہ سب اُسی تسبیح کے ٹوٹے ہوئے دانے ہیں؟
(ممتاز ادیب، نقّاد، شاعر اور مشہور انشائیہ نگار ڈاکٹر وزیر آغا کے انشائیے’’ چرواہے‘‘ سے اقتباس)