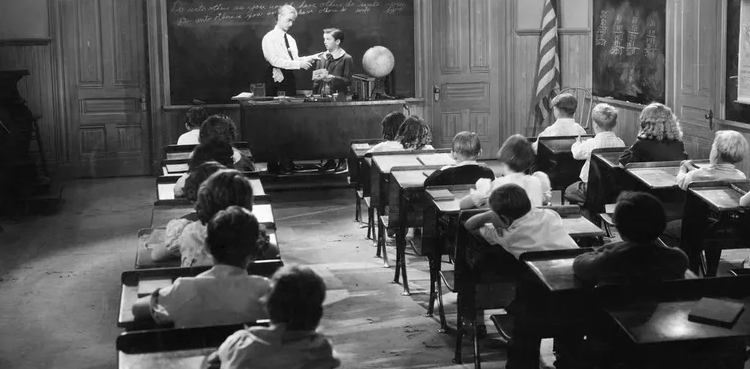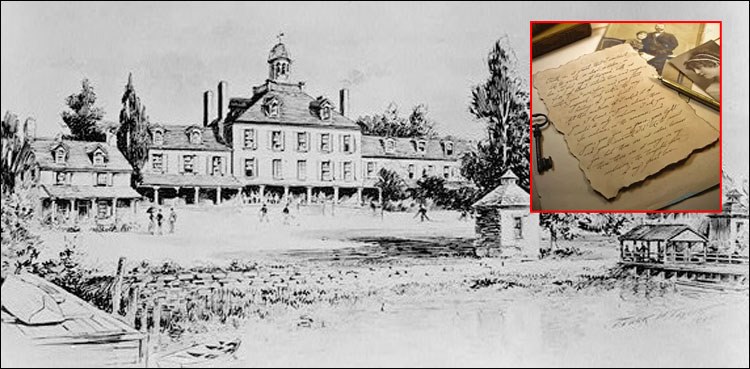میرے ڈاک والے بکسے میں ایک موٹا لفافہ میرا منتظر تھا۔ میں نے اسے کھولا اور رقم گنی۔ یہ پوری تھی۔ اس میں ایک رقعہ بھی تھا جس پر آدمی کا نام اور تفصیل کہ وہ مجھے کہاں مل سکتا تھا۔ اس میں، اس کی ایک پاسپورٹ سائز تصویر بھی تھی۔ میں نے خود پر لعنت بھیجی۔مجھے نہیں معلوم کہ مجھ سے ایسا کیوں ہوا۔ میں پیشہ ور ہوں اور ایک پیشہ ور کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، لیکن یہ بس منہ پر آ ہی گئی۔
مجھے بندے کا نام پڑھنے کی ضرورت پیش نہ آئی، میں نے تصویر سے ہی اس بندے کو پہچان لیا تھا۔ گریس۔ پیٹرک گریس، یہ امن کا نوبل انعام یافتہ ایک اچھا آدمی تھا۔ واحد اچھا بندہ جسے میں جانتا تھا۔ اور اگر اچھے بندوں کی بات کی جائے تو دنیا میں شاید ہی کوئی اور ہو، جو اس کا مقابلہ کر سکے۔
میں پیٹرک سے صرف ایک بار ہی ملا تھا۔ اور یہ ملاقات اٹلانٹا کے ایک یتیم خانے میں ہوئی جہاں وہ ہم سے جانوروں جیسا سلوک کرتے تھے۔ ہم سارا سال گندگی اور غلاظت میں گزارتے اور وہ ہمیں پیٹ بھر کھانا بھی نہ دیتے۔ اور اگر کوئی احتجاج میں اپنا منہ کھولتا تو وہ ہماری پٹائی چمڑے کی پیٹی سے کرتے۔ اکثر تو وہ یہ تکلیف بھی گوارا نہ کرتے کہ اس پیٹی کا بکسوا الگ کر دیں۔ لیکن جب وہاں گریس آیا تو انہوں نے یہ بات یقینی بنائی کہ ہم سب صاف ستھرے ہوں۔۔۔ ہم اور وہ موتری بھی، جسے وہ یتیم خانہ کہتے تھے۔ اس کے آنے سے پہلے، ڈائریکٹر نے ہمیں تنبیہہ کی کہ اگر کسی نے بھی منہ کھولا تو اسے اس کا نتیجہ بھگتنا پڑنا تھا۔ اس کی تقریر سے ہم سب کو اچھی طرح معلوم ہو گیا کہ وہ جو کہہ رہا تھا، وہ اس نے کرکے بھی دکھانا تھا۔
گریس، جب، ہمارے کمرے میں داخل ہوا تو ہم چوہوں کی طرح خاموش اور دبکے ہوئے تھے۔ اس نے ہم سے بات کرنے کی کوشش کی لیکن ہم آگے سے کچھ بھی نہ بو لے۔ ہر لڑکے نے اس سے تحفہ وصول کیا، اس کا شکریہ ادا کیا اور واپس اپنے بستر پر چلا گیا۔ مجھے ایک ڈارٹ بورڈ ملا۔ میں نے جب اس کا شکریہ ادا کیا تو وہ میرے قریب ہوا۔ میں دبک گیا۔ میں نے سوچا تھا کہ وہ شاید مجھے مارنے لگا تھا۔ گریس نے پیار سے میرے بالوں کو سہلایا اور بغیر کچھ بولے، میری قمیض اوپر اٹھائی۔ میں ان دنوں میں خاصی بکواس کیا کرتا تھا۔ گریس نے میری کمر پر نظر ڈال کر اس کا اندازہ کر لیا تھا۔ اس نے پہلے تو کچھ نہ کہا، لیکن پھر اس کے منہ سے مسیح کا نام تین چار بار نکلا۔ بالآخر اس نے میری قمیض چھوڑی اور مجھے گلے لگا لیا۔ اور جب اس نے مجھے گلے لگایا تو اس نے یقین دلایا کہ آئندہ کسی نے بھی مجھے ہاتھ نہیں لگانا تھا۔ یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ میں نے اس کی بات پر یقین نہ کیا۔ لوگ بلا جواز آپ کے ساتھ اچھی طرح سے پیش نہیں آتے۔ مجھے لگا کہ یہ ایک طرح کا مکر تھا؛ اس نے کسی بھی لمحے اپنی پیٹی اتارنی تھی اور مجھے پیٹنا تھا۔ جتنی دیر اس نے مجھے گلے لگائے رکھا، میں یہ خواہش کرتا رہا کہ وہ وہاں سے چلا جائے۔ وہ چلا گیا اور اسی شام ہمارے یتیم خانے کا سارا عملہ بدل دیا گیا اور ہمیں ایک نیا ڈائریکٹر بھی مل گیا۔ اور تب سے کسی نے بھی مجھے دوبارہ ہاتھ نہ لگایا، سوائے اس سیاہ فام کے، جسے میں نے’جیکسن وِل‘ میں مار بھگایا تھا۔ کیا یہ ایک ایسا کام تھا جسے میں نے بغیر کسی معاوضے کے کیا تھا؟ اس کے بعد تو کسی کی بھی جرأت نہ ہوئی کہ میری طرف انگلی بھی اٹھا سکے۔
میں اس کے بعد پیٹرک گریس سےکبھی نہ مل پایا۔ لیکن میں اس کے بارے میں اخبارات میں بہت کچھ پڑھتا رہا۔ ان لوگوں کے بارے میں، جن کی اس نے مدد کی اور ان سارے اچھے کاموں کے بارے میں، جو وہ کرتا تھا۔ وہ ایک اچھا آدمی تھا۔ میرا خیال تھا کہ اس سے اچھا انسان کہیں اور نہ تھا۔ وہ اس بد رنگ اور مکروہ دنیا میں واحد آدمی تھا، جس کا میں دین دار تھا۔ اور اب دو گھنٹے بعد ہی مجھے اس سے دوبارہ ملنا ہے۔ اور دو گھنٹے بعد ہی مجھے اس کے سَر میں ایک گولی داغنی ہے۔
میں اکتیس برس کا ہوں۔ میں جب سے اس کام میں پڑا ہوں، مجھے اب تک انتیس ٹھیکے مل چکے ہیں۔ ان میں سے چھبیس کو تو میں ایک ہی ہلّے میں پار کر گیا تھا۔ میں جن کو قتل کرتا ہوں، انہیں جاننے کی کبھی کوشش نہیں کرتا۔ اور نہ ہی یہ جاننے کی کوشش کرتا ہوں کہ میں انہیں کیوں مار رہا ہوں۔ دھندا، دھندا ہوتا ہے اور جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ میں ایک پیشہ ور قاتل ہوں۔ اور کام میں میری ساکھ بہت اچھی ہے۔ اور ایسے پیشے میں، جیسا کہ میرا ہے، اچھی ساکھ ہی اہم ہوتی ہے۔ آپ اخبار میں اشتہار نہیں دیتے یا ایسے لوگوں کے لیے خصوصی بھاﺅ نہیں لگاتے جن کے پاس اچھی مالیت والے کریڈٹ کارڈ ہوں۔ اس دھندے میں آپ تبھی کامیاب ہوتے ہیں جب لوگوں کو آپ پر اعتماد ہو کہ آپ ان کا کام کر دیں گے۔ اسی لیے میری یہ پالیسی ہے کہ میں، اپنے معاہدے سے کبھی نہیں پھرتا۔ جب بھی کوئی بندہ میرا ریکارڈ دیکھتا ہے تو اسے سوائے مطمئن گاہکوں کے اور کچھ نہیں ملتا؛ مطمئن گاہگ اور سخت گیر کھرا پن۔
میں نے کیفے کے بالکل سامنے گلی میں ایک کمرہ کرایے پر لیا اور اس کے مالک کو دو ماہ کا کرایہ پیشگی دیتے ہوئے بتایا کہ میرا باقی کا سامان پیر وار کو پہنچنا تھا۔ میرا اندازہ تھا کہ اسے وہاں پہنچنے میں لگ بھگ آدھا گھنٹہ لگنا تھا، مطلب قتل کرنے میں ابھی آدھ گھنٹہ باقی تھا۔ میں نے اپنی بندوق جوڑی اور اس کی انفرا۔ ریڈ روشنی میں اس کا نشانہ بٹھایا۔ چھبیس منٹ ابھی باقی تھے۔ سگریٹ سلگا کر میں اس کوشش میں تھا کہ کسی شے کے بارے میں کچھ نہ سوچوں۔ میں نے سگریٹ پی کر اس کا بچا ہوا ٹکڑا کمرے کے ایک کونے میں پھینکا۔ اس جیسے بندے کو کون مارنا چاہے گا؟ وہ یا تو کوئی جانور ہو سکتا ہے یا کوئی ایسا بندہ جو مکمل طور پر پاگل ہو چکا ہو۔ میں گریس کو جانتا ہوں۔ اس نے مجھے تب گلے لگایا تھا جب میں ابھی بچہ تھا۔ لیکن دھندا تو دھندا ہے۔ ایک بار جب آپ احساسات کو در آنے دیتے ہیں تو سمجھیں دھندے میں آپ کا انت ہو گیا۔ اس کونے سے جہاں سگریٹ کا ٹکڑا گرا، قالین سے دھواں اٹھنے لگا۔ میں بستر سے اٹھا اور سگریٹ کے ٹکڑے کو مسلا۔ ابھی اٹھارہ منٹ باقی تھے۔ اٹھارہ منٹ اور، اور پھر یہ کام ختم ہو جانا تھا۔ مجھے فٹ بال کے بارے میں خیال آیا، ڈین مارینو۔۔۔ 42 ویں اسٹریٹ کی وہ طوائف بھی جو مجھے کار کی اگلی سیٹ پر بٹھا کر فلیتو کرنے لگتی ہے۔۔۔ میں نے کوشش کی کہ میں کسی بھی شے کے بارے میں نہ سوچوں۔
وہ بالکل وقت پر آیا۔ اس کی اچھل اچھل کر چلنے والی چال اور کندھوں تک لمبے بالوں نے مجھے اس کو پہچاننے میں مدد دی۔ وہ کیفے کے باہر ایک انتہائی روشن جگہ پر پڑی میز کے پاس ایسے بیٹھا کہ اس کا چہرہ بالکل میرے سامنے تھا۔ یہ درمیانی دوری والے نشانہ کے حوالے سے ایک کامل زاویہ تھا۔ اور میں اسے آنکھیں بند کرکے بھی لگا سکتا تھا۔ انفرا۔ ریڈ کا نقطہ اس کے سر کے ایک طرف بائیں سے تھوڑا آگے تھا۔ میں اسے دائیں طرف اس وقت تک موڑتا رہا جب تک وہ بالکل وسط میں نہ پہنچ گیا اور تب میں نے اپنی سانس روک لی۔
اور جب، میرے لیے سب کچھ تیار تھا، ایک بوڑھا آدمی دو تھیلوں میں اپنا متاعِ حیات لیے، گھومتا گھماتا وہاں پہنچا۔۔۔ ایک عام بے گھر بندہ، جن سے یہ شہر بھرا پڑا ہے۔ جیسے ہی وہ کیفے کے سامنے پہنچا، اس کے تھیلوں میں ایک کا دستہ ٹوٹا اور تھیلا نیچے گر گیا اور اس میں موجود سارا کاٹھ کباڑ باہر نکلنے لگا۔ مجھے نظر آیا کہ گریس کے جسم میں ایک تناﺅ آیا اور اس کے منہ کے ایک کونے میں اینٹھن پیدا ہوئی، اور وہ ساتھ ہی بوڑھے کی مدد کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ فٹ پاتھ پر گھٹنوں کے بل جھکا اور ردی اخبار اور ٹین کے خالی ڈبے اکٹھے کرتے ہوئے تھیلے میں واپس رکھنے لگا۔ میری شِست اس پر بندھی ہوئی تھی اور اس کا چہرہ اب میرا تھا۔ لال نقطہ اب اس کے ماتھے کے وسط میں یوں چمک رہا تھا جیسے کسی انڈین کے ماتھے پر روغنی ٹیکا لگا ہو۔ یہ چہرہ جو کہ اب میرا تھا، بوڑھے کو دیکھ کر مسکرایا تو اس پر ایک چمک آئی۔ ایسی چمک جو کسی گرجا گھر میں دیوار پر ٹنگی مقدس مذہبی پیشواﺅں کی پینٹنگز میں ان کے چہروں پر ہوتی ہے۔
میں نے شِست سے نظر ہٹائی اور اپنی انگلی کو غور سے دیکھا۔ یہ ٹریگر کی پکڑ پر کانپ رہی تھی۔ یہ نہ صرف باہر بلکہ سُن بھی تھی۔ میں اس انگلی کے ساتھ کام پورا نہیں کر سکتا تھا۔ خود کو دھوکہ دینے کی ضرورت نہیں ، مجھ سے یہ کام ہونا ہی نہ تھا۔ میں نے سیفٹی کیچ لگایا، بولٹ کو واپس دھکیلا اور گولی اپنے چیمبر میں واپس چلی گئی۔
میں بندوق کو اس کے بکسے میں رکھا اور اسے ساتھ لیے کیفے کی طرف بڑھا۔ اب یہ بندوق نہیں تھی، یہ اس کے پانچ بے ضرر حصے تھے۔ میں گیا اور گریس کی میز پر اس کی طرف منہ کرکے بیٹھ گیا اور ایک کافی منگوائی۔ اس نے مجھے فوراً پہچان لیا۔ اس نے مجھے پچھلی بار تب دیکھا تھا جب میں فقط گیارہ برس کا لڑکا تھا لیکن اسے، مجھے پہچاننے میں کوئی دِقت نہ ہوئی۔ اسے میرا نام تک یاد تھا۔ نوٹوں سے بھرا لفافہ میز پر رکھ کر میں نے اسے بتایا کہ کسی نے، اسے قتل کرنے کے لیے میری خدمات کرایے پر لیں تھیں۔ میری کوشش تھی کہ خود کو ٹھنڈا رکھوں اور ایسا ظاہر کروں کہ جیسے میں نے یہ کام کرنے کے بارے میں کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ گریس مسکرایا اور اس نے کہا کہ اسے یہ پتہ تھا۔ اور یہ کہ یہ بندہ وہ خود ہی تھا جس نے لفافے میں مجھے پیسے بھجوائے تھے کیونکہ وہ مرنا چاہتا تھا۔ مجھے یہ ماننے میں کوئی تامل نہیں ہے کہ میں اس سے اس جواب کی توقع نہیں کر رہا تھا۔ میں ہکلایا اور پوچھا کہ کیوں؟ کیا اسے کوئی مہلک بیماری لاحق تھی؟ ”بیماری؟“ ،اس نے قہقہہ لگایا۔ ” ہاں، ایک طرح سے۔ تم یہ کہہ سکتے ہو۔“ اس کے منہ کے ایک کونے میں پھر سے اینٹھن ابھری، ویسی ہی جیسی میں کھڑکی میں سے، پہلے بھی دیکھ چکا تھا، اور پھر اس نے بولنا شروع کیا؛
”میں جب بچّہ ہی تھا، یہ بیماری تب سے مجھے لاحق ہے۔ اس کی نشانیاں بہت واضح تھیں، لیکن کسی نے بھی اس کا علاج کرانے کی کوشش نہ کی۔ میں ہمیشہ اپنے کھلونے دوسرے بچّوں کو دے دیتا تھا۔ میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا تھا، میں نے کبھی کوئی شے چرائی نہ تھی۔ مجھے کبھی یہ خیال نہ آیا تھا کہ اسکول میں لڑائی کے دوران جوابی حملہ کروں۔ مجھے ہر بار یہ پتہ ہوتا کہ میں نے اپنا دوسرا گال ہی آگے کرنا تھا۔ میرے دل کی اچھائی ایک مجبوری کی طرح دن بدن بڑھتی گئی لیکن کوئی بھی اس پر توجہ دینے کے لیے تیار نہ تھا۔ اس کے برعکس اگر میں اندر سے برا ہوتا تو وہ مجھے کسی نہ کسی طور اسے کم کرنے پر مائل کرتے یا کچھ اور کرتے۔ وہ اسے ختم کرنے کی بھی کوشش کرتے۔ لیکن جب آپ اچھے ہوتے ہیں ؟۔۔۔ تو ہمارے سماج میں لوگوں کو یہ بات زیادہ راس آتی ہے کہ وہ جو چاہتے ہیں اسے وصول کرتے رہیں۔۔۔ اور جواب میں خوشی کا اظہار کرتے ہوئے چند تعریفی کلمات کہتے رہیں۔ یوں میری حالت مزید بگڑتی گئی۔ یہ اس حد تک بگڑ گئی کہ میں تسلی سے کھانا بھی نہیں کھا سکتا اور میں ہر نوالہ چبانے کے بعد رُک جاتا اور ڈھونڈتا کہ مجھ سے زیادہ بھوکا کہیں کوئی اور تو نہیں۔۔۔ تاکہ میں اپنا کھانا اس سے بانٹ کر کھا سکوں۔ اور تو اور راتوں میں میرا سونا حرام ہو گیا۔ خود ہی سوچو کہ ایک بندہ، نیو یارک میں رہتے ہوئے سونے کے بارے میں کیسے سوچ سکتا ہے، جبکہ اس کے گھر سے ساٹھ فٹ کے فاصلے پر پارک میں، بینچوں پر بیٹھے لوگ سردی سے ٹھٹھر رہے ہوں؟
اس کے منہ کے کونے پر اینٹھن پھر سے چھائی اور اس کا سارا بدن لرز اٹھا۔ ”میں اس طرح زندہ نہیں رہ سکتا، نیند کے بغیر، کھانے کے بغیر، محبت کے بغیر، زندگی کیسے گزر سکتی ہے۔ ایسا بندہ جس کے پاس محبتیں لٹانے کے لیے وقت ہے، جب کہ اس کے گردا گرد بے تحاشہ تکلیفیں ہیں، زبوں حالی ہے؟ یہ ایک برا خواب ہے۔ میرے نقطۂ نظر سے دیکھنے کی کوشش کرو۔ میں نے تو ایسا کبھی نہیں چاہا تھا۔ یہ تو ایک طرح کا ’ ڈائی بُک‘ ہے، فرق بس اتنا ہے کہ شیطان کی جگہ آپ میں ایک فرشتہ گھس جائے۔ لعنت ہے۔ اگر شیطان مجھ میں گھسا ہوتا تو کسی نہ کسی نے مجھے کب کا ختم کر دینا تھا۔ لیکن یہ فرشتہ پن؟“ گریس نے ہولے سے آہ بھری اور اپنی آنکھیں بند کیں۔
” سنو۔“ ، وہ پھر سے بولنے لگا، ” یہ ساری رقم لو۔ جاﺅ اور کسی چھت یا بالکنی میں جا کر اپنی جگہ سنبھالو اور اپنا کام ختم کرو۔ ظاہر ہے کہ میں یہ کام خود نہیں کر سکتا۔ اور میرے لیے زندہ رہنا ہر آنے والے دن کے ساتھ مشکل سے مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ مہربانی کرو، اوپر کسی چھت پر جاﺅ اور یہ کام کر دو۔ میں تم سے التجا کرتا ہوں۔“ میں نے اس کی طرف دیکھا۔ یہ ایک اذیت بھرا چہرہ تھا، ویسے ہی جیسے صلیب پر لٹکے ہوئے مسیح کا ہو۔۔۔۔ بالکل مسیح جیسا۔ میں نے کوئی جواب نہ دیا۔ مجھے پتہ ہی نہ تھا کہ میں کیا کہوں۔ میں، جس کے پاس ہمیشہ جواب ہوتا تھا، اقرار لینے والے پادری کے لیے، مئے خانے میں بیٹھی ایک طوائف کے لیے یا کسی وفاقی پلسیے کے لیے، لیکن اس کے لیے؟ میں اس کے سامنے یتیم خانے والا وہی ایک ننھا، ڈرا ہوا بچّہ تھا، جو ہر غیر متوقع حرکت پر دبک جاتا تھا۔ اور وہ ایک اچھا بندہ تھا اور میں اسے کبھی بھی کھونا نہیں چاہتا تھا۔ میں تو اسے مارنے کی کوشش بھی نہیں کر سکتا تھا۔ میری انگلی نے تو ٹریگر کے گرد لپٹنا ہی نہیں تھا۔
”مسٹر گریس، میں معذرت خواہ ہوں۔“ میں کافی دیر بعد ہولے سے بولا، ” میں یہ نہیں۔۔۔“
” تم مجھے مار بھی نہیں سکتے۔“ ، وہ مسکرایا ، ” چلو ٹھیک ہے۔ تمہیں پتہ ہے کہ تم پہلے نہیں ہو۔ تم سے پہلے بھی دو بندے اور تھے جنہوں نے مجھے لفافہ لوٹا دیا تھا۔ میرا خیال ہے کہ یہ سب بد دعا کا حصہ ہے۔ تم، یتیم خانہ اور سب۔۔۔ “، اس نے کندھے اچکائے، ” اور میں روز بروز کمزور ہوتا جا رہا ہوں۔ ایسے ہی مجھے خیال آیا تھا کہ شاید تم میری بھلائی کا بدلہ چکا دو گے۔“
”مسٹر گریس، میں معذرت خواہ ہوں۔“ میں نے پھر سے سرگوشی کی۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے، ” کاش کہ میں ایسا کر سکتا۔۔۔“
”اس کا ملال مت کرو۔“ اس نے کہا، ” میں سمجھتا ہوں۔ کچھ نہیں بگڑا۔ چھوڑو دفع کرو۔“، اور جب اس نے مجھے کافی کا بل اٹھاتے دیکھا تو وہ منہ ہی منہ میں مسکرایا۔ ” کافی میرے کھاتے میں، اور میں اس پر اصرار کرتا ہوں، تمہیں پتہ ہی ہے کہ ایسا کرنا ہی تو میری بیماری ہے۔“ مڑا تڑا نوٹ جیب میں واپس رکھتے ہوئے، میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور وہاں سے چل دیا۔ جب میں چند قدم آگے بڑھ گیا تو اس نے مجھے آواز دی۔ میں اپنی بندوق وہیں بھول گیا تھا۔
میں، دل ہی دل میں خود پر لعنت بھیجتا، اسے لینے واپس گیا اور مجھے لگا جیسے میں اس پیشے میں نووارد ہوں۔
تین دن بعد، ڈیلس میں کوئی سینیٹر میرے ہاتھوں مرا۔ یہ مشکل کام تھا۔ دو سو گز کی دوری، آدھا چھپا آدھا نظر آتا بندہ، اوپر سے ایک طرف کو کھینچتا ہوا کا دباﺅ، پھر بھی وہ فرش پر گرنے سے پہلے مر چکا تھا۔
(ایٹگر کریٹ کا عبرانی افسانہ جس کا ترجمہ قیصر نذیر خاورؔ نے کیا ہے)