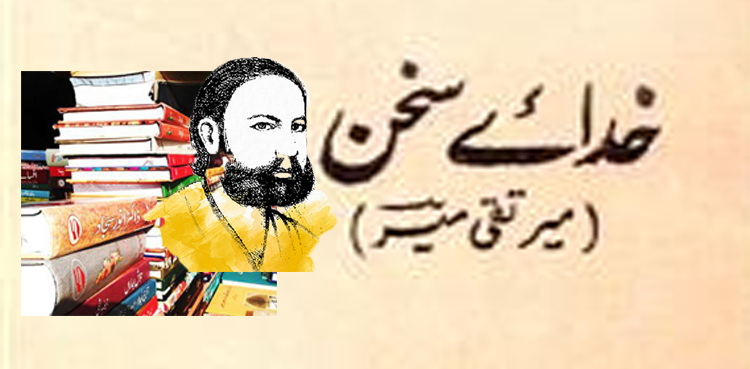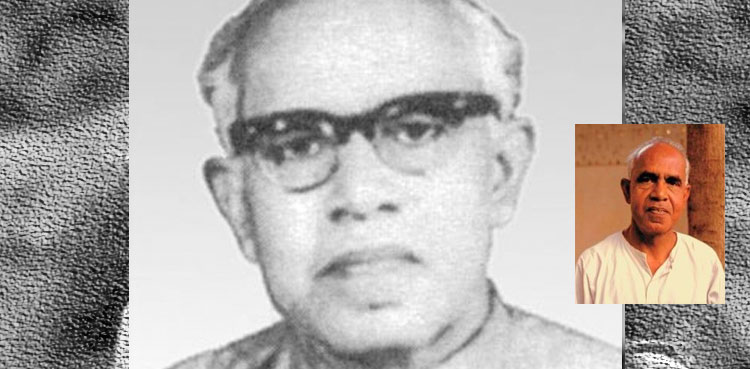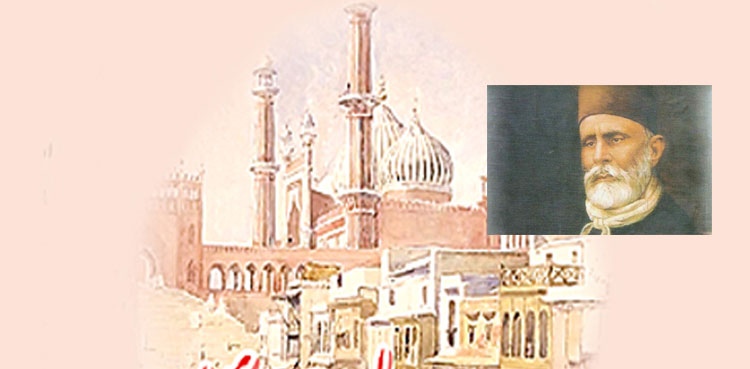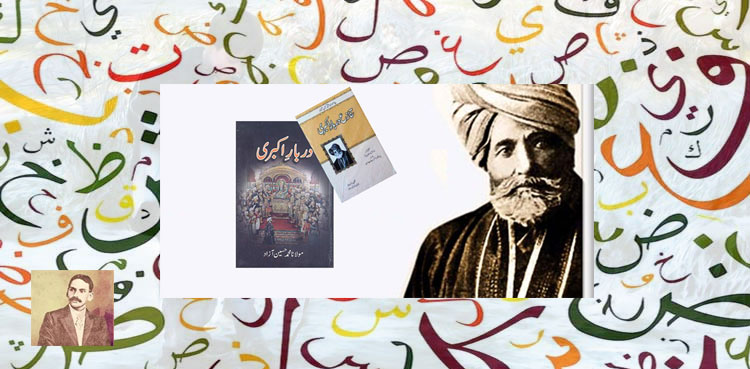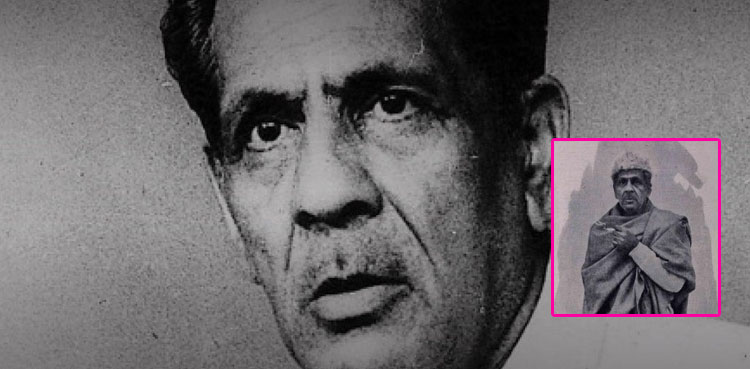میر کے ساتھ ہماری تنقید کا کیا رویہ ہے؟ زمانے بدلتے رہے مگر اردو تنقید افسوس ناک حد تک آہستہ رو رہی ہے۔
میر کبھی گم نامی کا شکار نہیں ہوئے۔ ان کی قبر پر ریل چل گئی تو کیا ہوا، تمام اردو شعراء نے اپنی دھڑکنوں میں ہمیشہ میر کو جگہ دی۔ ان کی کلیات بھی چھپتی رہی مگر وقفے وقفے سے۔ پھر بھی میر کے پرستاروں کو شکایت رہی کہ ان کی پذیرائی کم ہوئی۔ مجھے اثر لکھنوی اور ڈاکٹر سید عبداللہ سے یہ شکایت نہیں ہے کہ وہ میر کو ہر دل عزیز بنانے میں ناکام رہے ہیں، اس لیے کہ ان بزرگوں نے اپنی ساری ذہانت کو میر کے مطالعے میں صرف کر دیا ہے مگر برا ہو اردو تنقید کا جو شاعری میں افکار اور احساسات و جذبات کو الگ الگ خانوں میں دیکھنے کی عادی ہے۔
ناصر کاظمی ایسا فہیم شاعر بھی میر پر مضمون لکھتے ہوئے قدم قدم پر جھجھکتا ہے اور آخر میں میر اور اقبال کے یہاں مماثلت تلاش کرنے پر مجبور نظر آتا ہے۔
وارث علوی کی زبان میں ’’معنی کس چٹان پر بیٹھا ہے‘‘ یعنی شاعری میں اقدار و افکار کی جستجو، جذبات اور احساسات سے الگ چہ معنی دارد؟ غالب ایسا عظیم شاعر بھی میر کی استادی کو اس طرح تسلیم کرتا ہے کہ میر کے انداز یعنی سہلِ ممتنع میں شاعری کی کوشش کرتا رہتا تھا۔ میر کے کلام میں بے پناہ تاثیر، زبان میں ندرت، جذبات کے اظہار میں شائستگی اور شعری صداقت، ساری نزاکتوں کا ایک آئینہ در آئینہ سلسلہ ملتا ہے۔
میری رائے میں 1857ء کے تباہ کن اثرات سے ہم بے طرح گھبرا گئے تھے۔ حالی نے غیرشعوری طور سے اس روایت کو مجروح کر دیا جس سے ہم میر سے منسلک تھے۔ میں حالی پر الزم نہیں لگاتا، اس لیے کہ انگریز حکومت کے مہلک اثرات کی وجہ سے ہم آج تک اپنی ثقافتی تفہیم کرنے سے قاصر رہے ہیں۔ کبھی ہم ماضی میں پناہ ڈھونڈتے ہیں بنیاد پرستوں کی طرح اور کبھی مغرب زدہ لوگوں کی بنائی ہوئی ’’جنت‘‘ کو اپنا مستقبل سمجھتے ہیں۔ یہ نہیں جانتے کہ ہمارا ماحول کیا تھا اور اب کیا ہے؟ نہ جانے کس نے ہمیں یہ سمجھا دیا تھا کہ ’’وقت کی آواز‘‘ عشقیہ شاعری کے خلاف ہے جب کہ میر کی شاعری کار زارِ حیات کی سب سے دل کش آواز تھی۔ اسی وقت سے ہماری تنقید نے میر فہمی کی راہ کھول دی تھی۔ حسن عسکری نے ایک مضمون میں لکھا تھا: ’’اگر لوگ میر کے اس شعر کی جدلیات کو سمجھ لیں تو جو انقلاب رونما ہوگا وہ مارکس کے انقلاب سے کہیں بڑا ہوگا۔‘‘ (حوالہ: انسان اور آدمی)
ظاہر ہے کہ یہ جملہ صرف ’’ترقی پسندوں‘‘ کو چھیڑنے کے لیے لکھا گیا تھا۔ میر کا شعر ہے،
وجہِ بے گانگی نہیں معلوم
تم جہاں کے ہو واں کے ہم بھی ہیں
اس شعر میں جو نکتہ قابلِ غور ہے وہ علیحدگی، بےگانگی (Alienation) کو جنم دیتا ہے اور ہم صنعتی نظام میں داخل ہوئے تھے کہ اس کا شکار ہو گئے۔ اب ہماری بیگانگی دشمنی میں بدلتی جارہی ہے۔ اردو کی سب سے جان دار روایت عشقیہ شاعری کی تھی۔ عشق ہی تصوف اور بھکتی تحریروں کی جان تھا۔ ہماری مشترکہ تہذیب کی بنیاد تھا (قرۃ العین حیدر کے نئے ناول ’’گردش رنگ چمن‘‘ میں اس دور کے چند مناظر اور کردار دیکھے جاسکتے ہیں ) ہم نے انجانی اصلاحی اقدار کے فریب میں آکر اپنی ’جڑوں ‘سے خود کو کاٹ لیا ہے اور آج ہم زندگی کی سزا پا رہے ہیں اور ادب میں خون ناحق کو بہتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اور حیران و ششدر ہیں۔ ہم خود اپنے جرائم کی سزا پا رہے ہیں، کم از کم بقول میر ہمارے سینے تو سوزِ عشق سے منور ہوتے،
اعجازِ عشق سے ہم جیتے رہے وگرنہ
کیا حوصلہ کہ جس میں آزار یہ سمائے
آج ہمارے پاس عشق کا سوزِ دروں ہے نہ عمل کی لگن۔ ہم۔ سب۔ ایک معنی میں ایلیٹ کے ’’کھوکھلے آدمی‘‘ بن کر رہ گئے ہیں!
میرتقی میر بنیادی طور سے رومانی کرب کے شاعر تھے مگر یہ کرب صرف جنسی تشنگی اور دیوانگی کی دین نہیں تھا، اس میں آئندہ مستقبل کے خواب کی پنہاں آرزوئیں بھی شامل ہو گئی تھیں۔ یہی نہیں اپنے ماحول کی ساری تہذیبی شکست و ریخت بھی شامل تھی۔ اطالوی ناقد ماریو پراز (Mario Praz) نے یوروپی شاعری (اٹھارہویں صدی) کو اسی اصطلاح سے جانچنے کی کوشش کی تھی۔ اٹھارہویں صدی کا یورپ بھی ہنگاموں اور انقلابوں کا مرکز تھا۔ انقلابِ فرانس نے یورپ کو پہلی بار انسانیت کو مساوات، اخوت اور آزادی کا پیغام دیا تھا۔ اس دور کے شاعر بھی اسی جانکاہ درد و غم سے سرشار تھے جس سے کہ رومانی کرب کی پہچان ہوتی ہے۔
روسو کے اعترافات (دوجلدیں ) کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ فطرت سے انسانی دوری کتنی مہلک ہوگی۔ ماریو پراز کا خیال تھا کہ مسرت کی جستجو ہی درد و غم کی راہ سے گزرتی ہے اور درد ہی مسرت کی جستجو کی منزل ہے۔ اس طرح خوشی اور غم کی جذباتی کشمکش حزنیہ لب و لہجے کو جنم دیتی ہے جو رومانی کرب کی نشان دہی کرتا تھا۔ میر کی شاعری میں جو گھلاوٹ، نرمی اور سپردگی ہے، وہ اسی غم کی قبولیت کی وجہ سے کہ درد ہی مسرت کی جان ہے اور مسلسل کرب ہی جہدِ حیات ہے۔
انگریزی رومانی شعرا سے میر کا تقابل پروفیسر احمد علی نے بھی کیا تھا۔ احمد علی نے اپنی کتاب سنہری روایت (The Golden Tradition) میں میر کی عظمت کا اعتراف کیا ہے، یہ کتاب آج بھی مطالعے کے قابل ہے، گو کہ اس کو شائع ہوئے پندررہ برس گزر چکے ہیں (مطبوعہ کولمبیا یونیورسٹی امریکہ ۱۹۷۳ء) میر تقی میر کی شاعری کو ان کی کشادہ شخصیت، بے پناہ تخلیقی قوت اور فکر خیز تخیل (Imagination) کی رہینِ منت ٹھہرایا ہے۔ یہی نہیں ان کی (احمدعلی) رائے میں میر کے پائے کا شاعر انگریزی رومانی شعرا میں کوئی نہیں تھا۔ فراق اردو میں یہی بات کہہ چکے ہیں۔ وہ میر کی شاعری میں ’دل‘ کے استعارے کو مرکزی حیثیت دیتے ہیں۔ مجنوں گورکھپوری یہ بات اپنے مضمون میں کہہ چکے ہیں (سردار جعفری ایک عرصے تک مجنوں سے اس لیے خفا رہے کہ مرحوم نے کئی شعر ایسے لکھے تھے جو میر کے نہیں ہیں۔ خیر) احمد علی کا خیال ہے کہ میر کے ذہن کی جستجو ہمیں ان اشعار سے کرنی چاہیے جو میر نے دل کو محور بنا کر کہے تھے، اس لیے کہ دل ہی عشق اور زندگی کا سرچشمہ ہے اور یہ اشعار بھی پیش کیے ہیں،
جا کے پوچھا جو میں یہ کارگہِ مینا میں
دل کی صورت کا بھی اے شیشہ گراں ہے شیشہ
کہنے لاگے کہ کدھر پھرتا ہے بہکا اے مست
ہر طرح کا جو تو دیکھے ہے کہ یاں ہے شیشہ
دل ہی سارے تھے یہ اک وقت میں جو کر کے گداز
شکل شیشے کی بنائے ہیں کہاں سے شیشہ
یہی نہیں، احمد علی کا خیال ہے کہ ایک معنی میں میر ایک وجودی شاعر تھے اور سارتر کا بیان نقل کرتے ہیں :Existence Precedes Essence یعنی وجود روح سے پہلے ہے۔ میر کا خیال ہے، ’’مقدور سے زیادہ مقدور ہے ہمارا‘‘ کی مثال بھی دیتے ہیں۔ میر پر انگریزی میں جو چند مضامین اور کتابیں میری نظر سے گزری ہیں ان میں یہ کتاب زیادہ ’’شہرت‘‘ کی مستحق تھی، اس لیے کہ اس کتاب میں میر کے اچھے خاصے ترجمے بھی شامل ہیں۔
اور ایک سوال میر ے ذہن میں آتا ہے کہ میر کی عشقیہ شاعری کے ساتھ کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ کیا اب یہ عہد پارینہ کی ایک شعری داستان ہے اور بس۔۔؟ سرمایہ دارانہ سماج میں ہر شے فروخت ہو سکتی ہے۔ اب عشق یا تو محض جنسی شے (بدن کی تہذیب کہاں؟) یا تفریح کا سامان۔ ایک ایسے دور میں جب ہم میر کی شاعری کا مطالعہ کرتے ہیں تو حیرت اور معصومیت سے نئی لذت کے ساتھ دوچار ہوتے ہیں یا یہ جانتے ہوئے بھی کہ اب وہ ’’رومانی کرب‘‘ اپنی جاذبیت بڑی حد تک کھو چکا ہے مگر کسی حد تک معصومیت حسن کی اور عشق کی کشمکش کو بڑی حد تک برقرار رکھے ہوئے ہے۔
عشق میں ہم ہوئے نہ دیوانے
قیس کی آبرو کا پاس رہا
عشق کا گھر ہے میر سے آباد
ایسے پھر خانماں خراب کہاں
رات مجلس میں تری ہم بھی کھڑے تھے چپکے
جیسے تصویر لگا دے کوئی دیوار کے ساتھ
دور بیٹھا غبار میر ان سے
عشق بن یہ ادب نہیں آتا
یہ خود کلامی کا ’’جادو‘‘ بھی رکھتی ہے۔ پروفیسر مسعود حسین ادیب نے میر کی شاعری کو ’’عشق کی زبان‘‘ سے تعبیر کیا تھا۔ مجھے اکثر یہ احساس ہوا ہے کہ میر کے آنسو’’پارس پتھر‘‘ تھے، جس لفظ کو چھو لیتے تھے کندن بن جاتا تھا۔ اس طرح جسمانی حسن کا بیان بھی ساری لطافتیں لیے ہوئے ہے،
ساتھ اس حسن کے دیتا تھا دکھائی وہ بدن
جیسے جھمکے ہے پڑا گوہرِ تر پانی میں
حسن کی بالیدگی کا یہ عالم شاید ہی کسی اردو شاعر نے کبھی سوچا اور بیان کیا ہو گا۔ میر کی عشقیہ شاعری ایک جمالیات کی نئی دستاویز تھی جس میں انبساط کے کم رنگ تھے مگر زرد رنگ سب سے نمایاں تھا جیسے ڈچ مصور وان گاف کی مصوری! آج میر کی عشقیہ شاعری ایک ایسی ’’فردوسِ گمشدہ‘‘ کی یاد دلاتی ہے جس میں دوزخ کو سیر کرنے کے لیے ملا دیا گیا ہو۔
(ممتاز نقاد اور روایت شکن قلم کار باقر مہدی کے مضمون کا ایک حصّہ ہند و پاک سمینار جامعہ ملیہ (نئی دہلی) میں ۱۹۸۳ء میں پڑھا گیا تھا)