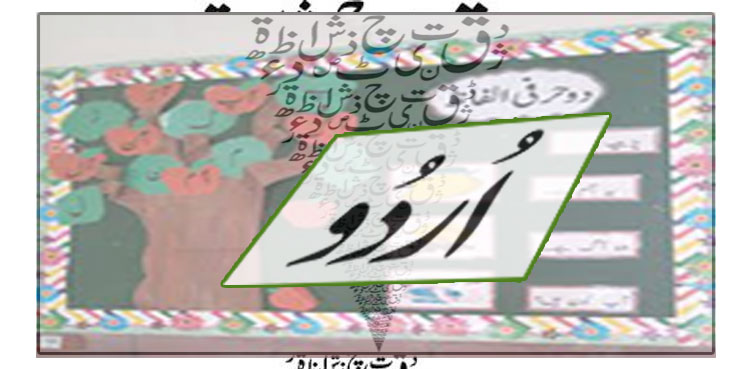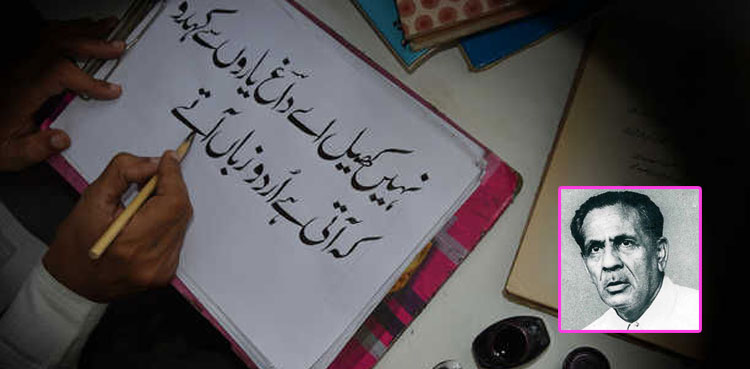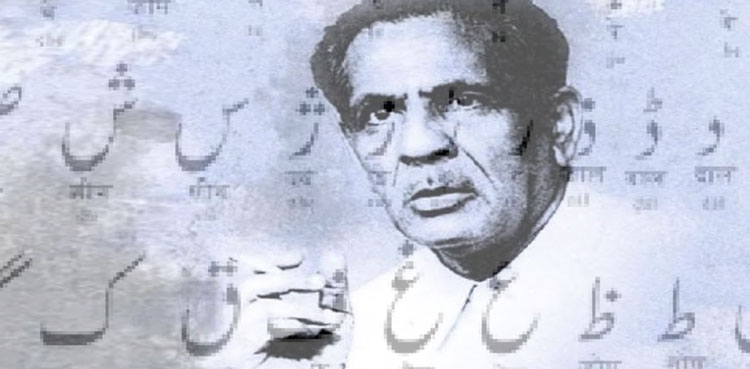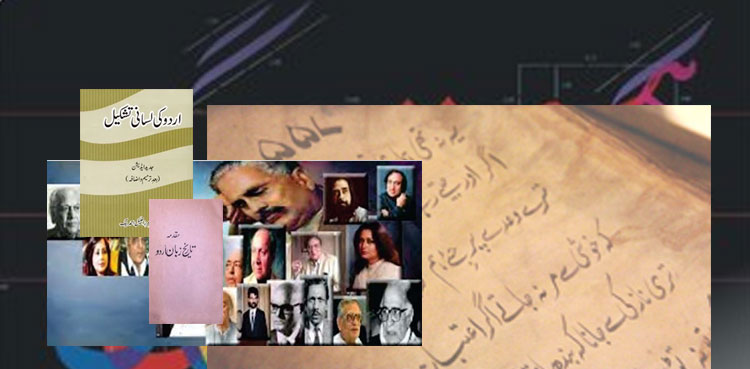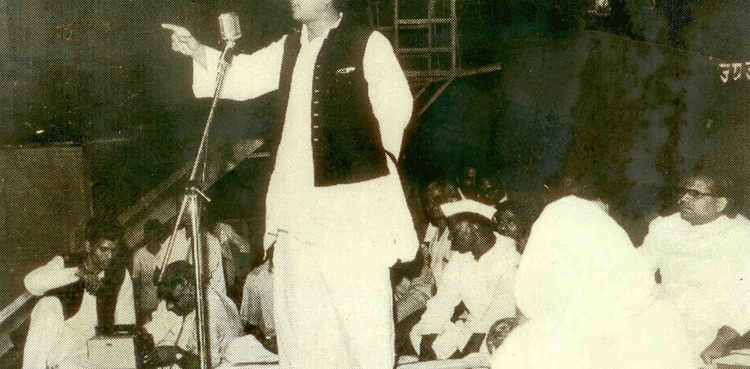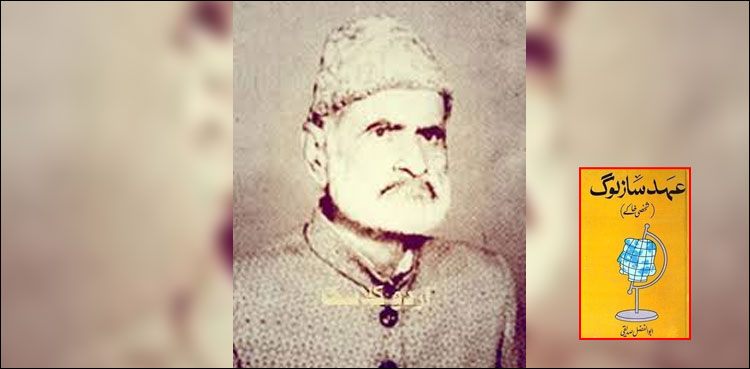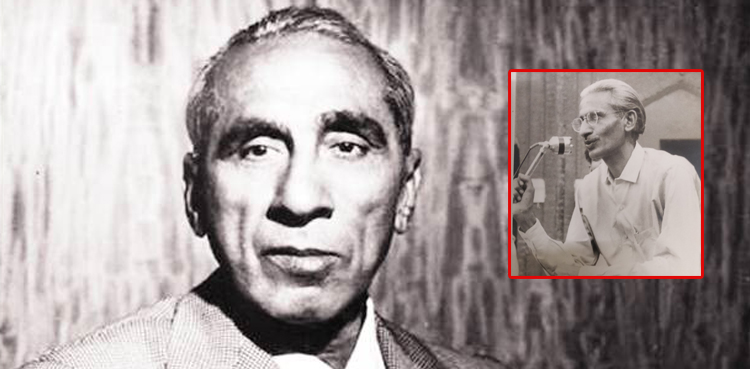ہندوستانی فلموں پر ہونے والی گفتگو اردو زبان اور اس کی تہذیب کے ذکر کے بغیر مکمل نہیں ہوسکتی۔ ہندوستانی فلموں نے اردو کی آغوش میں آنکھیں کھولیں اور اردو زبان کو اپنے اظہار کا ذریعہ بنایا۔
پہلی ہندوستانی فلم ’عالم آرا‘ پر غور کیا جائے تو یہ بات وثوق سے کہی جاسکتی ہے کہ اس کی کہانی، مکالمے، نغمے، برتاؤ وغیرہ سب کے سب اردو کے رنگ میں ہیں۔ اس فلم کے مکالمے کی زبان اردو تھی جسے عوامی سطح پر بے حد مقبولیت حاصل تھی۔ اس فلم کے ہِٹ ہونے میں مکالمے کا اہم رول رہا۔ اس پہلی متکلم فلم ’عالم آرا‘ کے مکالمے منشی ظہیر نے لکھے تھے جو اردو میں تھے۔
عالم آرا سے لے کر اب تک کی تمام ہندوستانی فلمیں اگر کام یابی سے ہم کنار ہوئیں تو اس میں مکالمے کا رول اہم رہا ہے۔ ابتدا میں موسیقی سے لبریز فلمیں شائقین کے لیے لطف اندوزی کا ذریعہ تھیں، مگر سنیما صنعت کی ترقی کے ساتھ رواں دواں زندگی کی پیش کاری کے لیے جہاں کئی ذرائع اظہار استعمال کیے گئے، وہیں جذبات و احساسات کے حسین اور پُر اثر اظہار کے لیے مکالمے کو بہترین آلۂ کار مانا گیا۔ بولتی فلموں کے آغاز سے اب تک مکالمے کی اہمیت برقرار ہے۔ ہزاروں مکالمے پسندیدگی کی سند پا چکے ہیں اور خاص و عام کی زبان پر جاری ہیں۔ جہاں بھی فلموں میں پُر اثر اداکاری کا ذکر ہوتا ہے وہیں مشہور ڈائلاگ برسوں تک شائقین بھول نہیں پاتے۔
آخر مکالمے میں ایسی کیا بات ہے کہ فلموں میں اس کی اتنی اہمیت ہے۔ اس کو تعریف کا جامہ کس طرح عطا کر سکتے ہیں، اس سلسلے میں فلموں سے وابستہ فن کاروں کی رائے سود مند ہو سکتی ہے اور ان نکات پر گفتگو کی جا سکتی ہے جن کی طرف آرٹسٹوں نے توجہ دلائی ہے۔ جناب احسن رضوی جنھوں نے فلم مغلِ اعظم کے کچھ مکالمے لکھے، ان کے مطابق ’’مکالمہ وہ پیرایۂ گفتگو ہے جو کہانی کی تمام ضرورتوں پر حاوی ہو۔‘‘ انھوں نے کہانی اور منظرنامے میں مکالمے کی بنیادی حیثیت کو قبول کیا ہے۔ جدید شاعری کا اہم ترین نام اخترالایمان تقریباً چالیس سال تک فلموں سے وابستہ رہے۔ کہانیاں، شاعری اور مکالمے انھوں نے فلموں کے لیے لکھے۔
فلم کی کام یابی کے لیے جن نکات پر محنت کی جاتی رہی ہے ان میں مکالمہ بھی ایک ہے۔ مکالمے صرف تحریر نہیں کیے جاتے ہیں بلکہ اس کی قرأت کو ریکارڈ کیا جاتا ہے۔ مکالمہ نویس اور اداکار کے درمیان مکالمے پر تبادلۂ خیال کو ضروری تصور کیا جاتا ہے۔ اداکار کو اس بات کے لیے تیّار کیا جاتا ہے کہ مکالمے اس انداز سے ادا کیے جائیں جو اس زبان کی اصلیت کو برقرار رکھے۔ اس کے لیے باضابطہ طور پر آدمی بحال کیے جاتے ہیں۔
اردو زبان کی ہمہ گیری اور مقبولیت کے پیشِ نظر فلموں کے مکالمے میں صرف الفاظ استعمال نہیں ہوتے ہیں بلکہ لہجہ بھی اردو والا ہی ہوا کرتا ہے۔ چند مکالمے ملاحظہ کیجیے اور ان میں اردو کی جلوہ گری محسوس کیجیے۔
’’آج میرے پاس گاڑی ہے، بنگلہ ہے، پیسہ ہے، تمہارے پاس کیا ہے؟‘‘۔۔۔۔ ’’میرے پاس، میرے پاس ماں ہے۔‘‘
’’آپ کے پاؤں بہت حسین ہیں، انھیں زمین پر مت اتاریے گا، میلے ہو جائیں گے۔‘‘ (فلم پاکیزہ)
’’انار کلی، سلیم کی محبّت تمہیں مرنے نہیں دے گی اور ہم تمہیں جینے نہیں دیں گے۔‘‘ (فلم مغلِ اعظم)
’’بڑے بڑے شہروں میں چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی رہتی ہیں۔‘‘ (فلم دل والے دلہنیا لے جائیں گے)
کبھی کبھی کچھ جیتنے کے لیے کچھ ہارنا پڑتا ہے۔ اور ہار کر جیتنے والے کو بازی گر کہتے ہیں۔‘‘ (فلم بازی گر)
یہ وہ مکالمے ہیں جو فلم دیکھنے والے حضرات کو ازبر ہیں۔ عوام میں ان مکالموں کا استعمال روزمرّہ کی طرح ہوتا ہے۔ کسی زبان کی سب سے بڑی خوبی یہ ہوتی ہے کہ اس کو بولنے والے سے اثر انداز ہو کر اس کو جاننے کی سعی کرنا۔ اردو زبان کی خصوصیت ہے کہ دوسری زبانوں کو جاننے والے جب ان الفاظ کو سنتے ہیں تو اس کو سیکھنے کی للک ہوتی ہے۔ ہندی یا دوسری علاقائی زبانوں کو جاننے اور بولنے والے اردو کے الفاظ کا استعمال کرکے خوش ہوتے ہیں اور اس کے حُسن کی تعریف کرتے ہیں۔
ہندوستانی فلموں کی ایک صد سالہ تاریخ کا مطالعہ کرنے سے واضح ہوتا ہے کہ ’عالم آرا‘ سے اب تک کی فلموں میں مکالمے کی حیثیت کلیدی رہی ہے۔ بے حد کام یاب فلمیں یا باکس آفس پر سپر ہٹ ہو نے والی فلموں کی کام یابی کی وجہ اگر تلاش کی جائے تو جہاں دوسرے عناصر کا نام آئے گا وہیں مکالمے کو کسی طور پر نظر انداز نہیں کیا جاسکتا۔
(محمد منور عالم کے مضمون سے انتخاب)