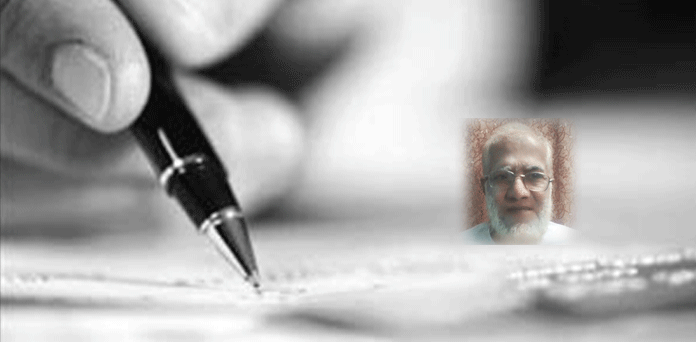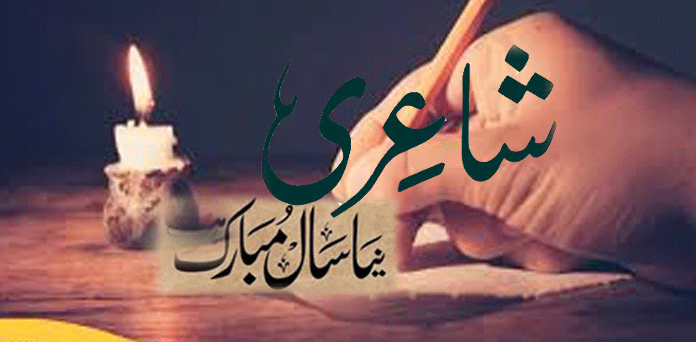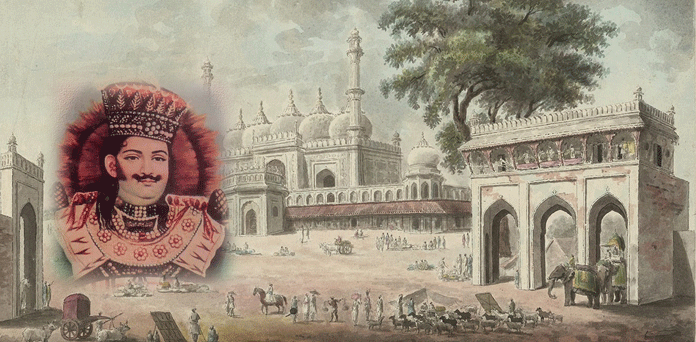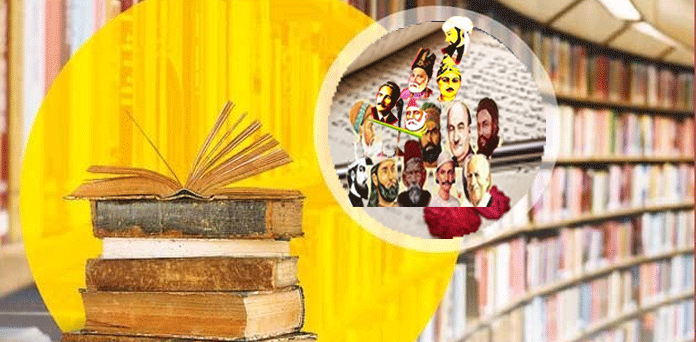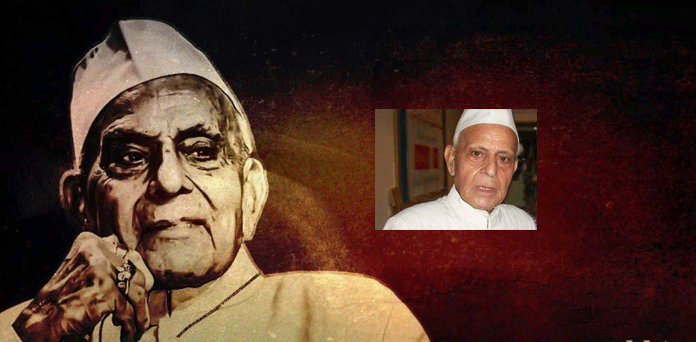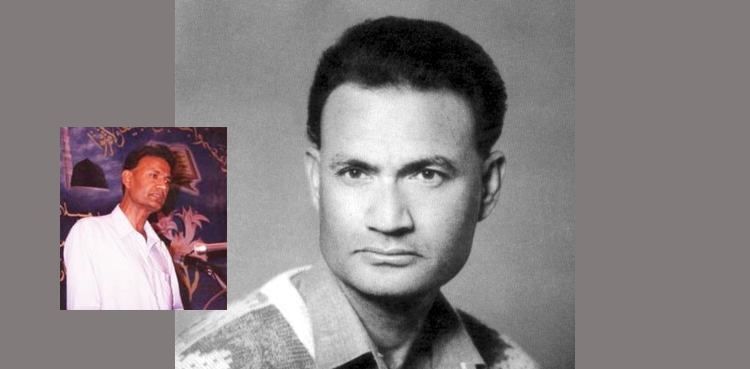شعرائے متقدمین اور نثر نگاروں کے درمیان ادبی معرکہ آرائی، معاصرانہ چشمک کے علاوہ بعض ایسے تنازع بھی کتابوں میں پڑھنے کو ملتے ہیں جن میں اپنے عہد کی نام ور شخصیات اور مشاہیر کا نام سامنے آتا ہے۔ یہ جھگڑے کہیں خالص ادبی نوعیت کے تھے تو کبھی ان کی وجہ محض عداوت اور حسد رہا۔ شاعرِ مشرق علّامہ اقبال کو بھی اپنی مثنوی میں قدیم صوفی شعرا پر تنقید کے بعد اپنی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا تھا۔
ادبی تحریریں اور علمی و تحقیقی مضامین پڑھنے کے لیے کلک کریں
فارسی کی مثنوی اسرارِ خودی کی اشاعت 1915ء میں ہوئی جو اقبال کے فلسفیانہ خیالات پر مبنی تھی۔ اسرارِ خودی کو چند سطروں میں سمیٹا جائے تو یہ ایسی مثنوی تھی جس میں اقبال نے اس دنیا کا تصور پیش کیا ہے جس میں مسلمان اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی بنیاد پر متحد ہوں۔ اقبال کی فکر کہتی ہے کہ اس کی تکمیل کے لیے ‘خودی’ پر انحصار کرنا ہوگا اور عملی طور پر کام کرنا ہوگا۔ لیکن صوفی شاعروں کے ترکِ دنیا کا فلسفہ بے عملی کی ترغیب دیتا ہے جو مسلمانوں کے زوال کی بڑی وجہ ہے۔ اقبال نے صوفیا پر تنقید کرتے ہوئے زور دیا کہ مسلمانوں کو گوشہ نشینی کی نہیں عملی میدان میں اترنے کی ضرورت ہے۔ اس کے ساتھ اقبال نے فارسی کے معروف شاعر حافظ شیرازی پر بھی تنقید کی اور ساتھ ہی فلسفۂ وحدت الوجود پر بھی سوال اٹھایا۔ ان کا یہ خیال تھا کہ بعض ایرانی شعرا نے وحدت الوجود سے متعلق جو نکتہ طرازیاں کی ہیں، وہ صرف پُرکشش ہیں، مگر اس شاعری نے تقریباً تمام اسلامی دنیا کو ذوقِ عمل سے محروم کردیا ہے جسے خودی کا فلسفہ بیدار کرسکتا ہے۔
ادبی تذکروں میں یہ تفصیل کچھ اس طرح پڑھنے کو ملتی ہے:
علّامہ اقبال کی فارسی مثنوی 1915ء میں شائع ہوئی۔ اس میں افلاطونؔ اور حافظ شیرازیؔ پر علّامہ نے تنقید کی تھی۔ انہوں نے حافظؔ پر 35 اشعار میں تنقید کرتے ہوئے مسلمانوں کو حافظ کے کلام سے دور رہنے کی تلقین کی تھی جس پر ادبی حلقوں میں بحث چھڑ گئی۔ اخباروں میں ان کے خلاف مضامین لکھے گئے۔ اہلِ تصوف علاّمہ سے بدظن ہوگئے۔ بعض حضرات نے ان کی مثنوی کا منظوم جواب دیا۔ جہلم کے میاں ملک محمد قادری نے اپنے منظوم جواب میں حافظ شیرازی کا دفاع کیا، اسی طرح پیر زادہ مظفر احمد فضلی نے ’اسرارِ خودی‘ کے جواب میں ’’رازِ بے خودی‘‘ کے عنوان سے مثنوی لکھی جس میں علاّمہ اقبال پر تنقید اور حافظ کا دفاع کیا گیا تھا۔
فارسی کے عظیم شاعر حافظ پر تنقید سے حسن نظامی اور اکبر الٰہ آبادی بھی ناراض ہوئے۔ مؤخرالذّکر نے مولانا عبدالماجد دریا بادی کے نام اپنے خطوط میں اپنی ناراضگی کا اظہار کیا۔ ’اسرار خودی‘ کے شائع ہونے کے دو سال بعد انہوں نے مولانا دریا بادی کو ایک خط تحریر کیا:’’اقبال صاحب کو آج کل تصوف پر حملے کا بڑا شوق ہے۔ کہتے ہیں عجمی فلاسفی نے عالم کو خدا قرار دے رکھا ہے اور یہ بات غلط ہے، خلافِ اسلام ہے۔‘‘
جب ’رموز بے خودی‘ شائع ہوئی تو اقبالؔ نے اس کا نسخہ اکبر الہ آبادیؔ کو بھی روانہ کیا جنھوں نے اسے دیکھنا بھی گوارا نہ کیا۔ انہوں نے مولانا دریا بادی کو لکھا: ’اقبال نے جب سے حافظ شیرازی کو علانیہ بُرا کہا ہے میری نظر میں کھٹک رہے ہیں۔ ان کی مثنوی اسرارِ خودی آپ نے دیکھی ہوگی۔ اب رموزِ بے خودی شائع ہوئی ہے۔ میں نے نہیں دیکھی۔ دل نہیں چاہا۔‘ تاہم بعد میں اکبر الہ آبادی ہی نے علامہ اقبال اور حسن نظامی میں صلح کروا دی۔
حافظ پر تنقید سے اہلِ تصوف بھی علّامہ سے ناراض ہوئے۔ انہوں نے اس تنقید کو تصوّف دشمنی پر محمول کیا۔ چنانچہ 15 جنوری 1916ء کو علامہ اقبال نے ’’وکیل‘‘ میں ’اسرارِ خودی اور تصوّف‘ کے عنوان سے ایک مضمون لکھا جس سے یہ سطور ملاحظہ ہوں:
’’شاعرانہ اعتبار سے میں حافظؔ کو نہایت بلند پایہ سمجھتا ہوں لیکن ملّی اعتبار سے کسی شاعر کی قدر و قیمت کا اندازہ کرنے کے لیے کوئی معیار ہونا چاہیے۔ میرے نزدیک معیار یہ ہے کہ اگر کسی شاعر کے اشعار اغراضِ زندگی میں ممد ہیں تو وہ شاعر اچھا ہے۔ اگر اس کے اشعار زندگی کے منافی ہیں یا زندگی کی قوت کو پست یا کمزور کرنے کا میلان رکھتے ہوں تو وہ شاعر خصوصاً قومی اعتبار سے مضرت رساں ہے۔ جو حالت خواجہ حافظ اپنے پڑھنے والوں کے دل میں پیدا کرنا چاہتے ہیں وہ حالت افرادِ قوم کے لیے جو اس زمان و مکان کی دنیا میں رہتے ہیں نہایت ہی خطر ناک ہے۔‘‘
انہوں نے مہاراجہ کشن پرشاد کو بھی اس کے دو ماہ بعد ایک خط میں یہی بات دہرائی اور فن کے متعلق اپنا نظریہ واضح کیا۔ لکھتے ہیں: ’’خواجہ حافظ کی شاعری کا میں معترف ہوں۔ میرا عقیدہ ہے کہ ویسا شاعر ایشیا میں آج تک پیدا نہ ہوا اور غالباً پیدا بھی نہ ہوگا لیکن جس کیفیت کو وہ پڑھنے والے کے دل پر پیدا کرنا چاہتے ہیں وہ کیفیت قوائے حیات کو کمزور اور ناتواں کرنے والی ہے۔‘‘
ادھر علاّمہ اقبال کی حمایت میں مولانا اسلم جیراجپوری نے بھی ایک مضمون لکھا جس میں انہوں نے کہا کہ خواجہ حافظ ؔ کے بارے میں اس طرح کی آرا پہلے بھی ظاہر کی جاچکی ہیں۔ چنانچہ مشہور ہے کہ اورنگ زیب عالمگیر نے منادی کرا دی تھی کہ دیوانِ حافظ کوئی نہ پڑھے کیوں کہ لوگ اس کے ظاہری معنیٰ سمجھ کر گمراہ ہوجاتے ہیں۔