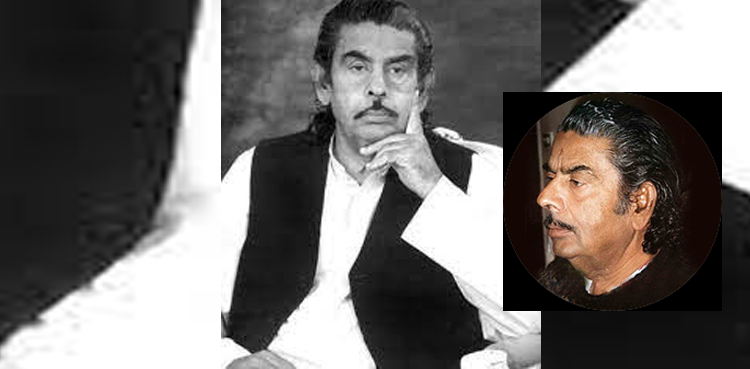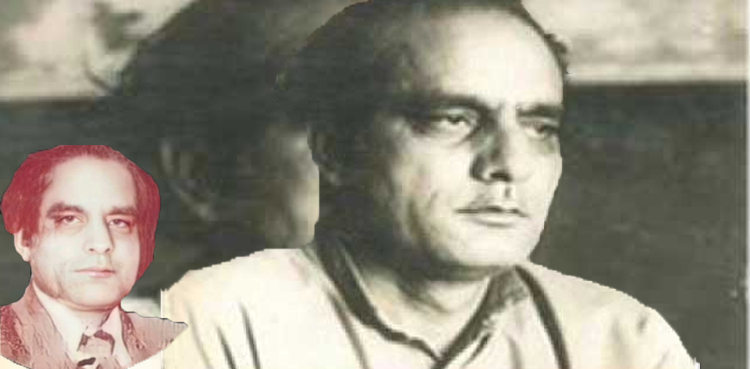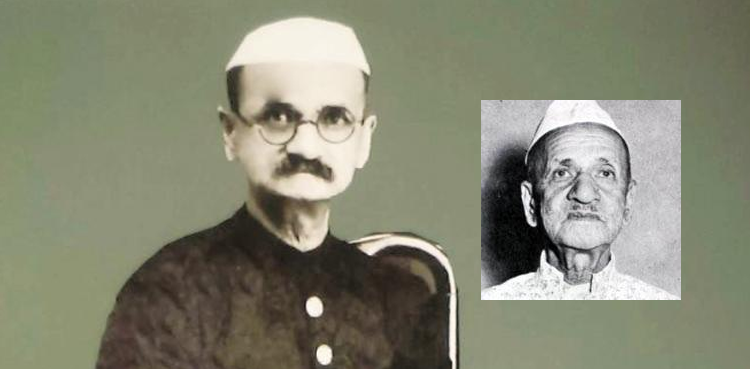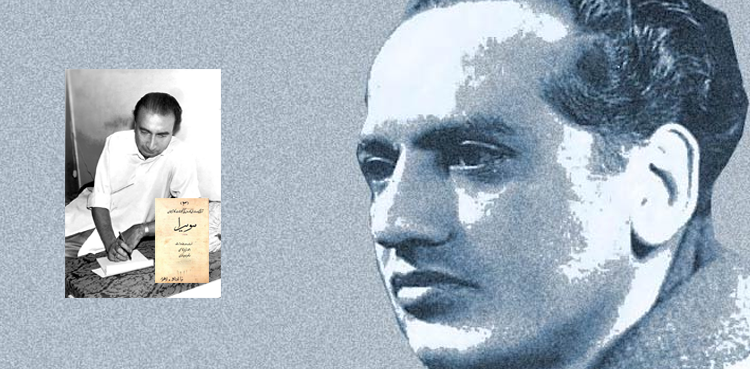فن موسیقی تین چیزوں کا امتزاج ہے سُر، لفظ اور تال۔ موسیقی میں ان تینوں عناصر کی اپنی اپنی جداگانہ اہمیت ہے جس میں یہاں ہم لفظ کی غنائی نوعیت کو موسیقی کی مختلف صورتوں کے ذریعے زیرِ بحث لا رہے ہیں۔
قارئین، ہر لفظ اپنی ایک غنائی ترکیب کے ساتھ وجود میں آتا ہے۔ اس لحاظ سے صوت، لفظ اور غنا دونوں پر مقدم ٹھہرتی ہے، کیونکہ صوت سے ہی لفظ تشکیل پاتا ہے اور غنا (موسیقی) بھی صوت ہی سے ترتیب پاتی ہے۔
لفظ آوازوں کا ایک مجموعہ ہوتا ہے۔ آوازوں کے اس مجموعے کو ایک خاص معنویت دے دی جاتی ہے۔ ماہرِ لسانیات کے نزدیک زبان گلے سے نکلی ہوئی ایسی آوازوں پر مشتمل ہوتی ہے جس میں اس کی معنویت اس زبان کے بولنے والوں نے شعوری طور پر متعین کی ہوتی ہے۔ اس کی معنویت میں اشاروں، چہرے اور ہاتھوں کی حرکات و سکنات سے اضافہ بھی کیا جاتا ہے۔
کچھ لوگ زبان کے اس عمل کو شعوری کی بجائے نفسیاتی عمل قرار دیتے ہیں، کچھ اس عمل کو حیاتیات سے جوڑ دیتے ہیں اور کچھ کے نزدیک زبان مخصوص علامات کا ایک نظام ہوتا ہے۔ پیش نظر مضمون میں موسیقی کے حوالے سے ہمارا تعلق صرف لفظ کے معنوی اور صوتی تصور سے ہو گا۔
لفظ اور معانی کا آپس جو رشتہ استوار ہوا ہے یہ عمل کس بنیاد پر ہوا ہے، یعنی اس کے پس منظر میں وہ کیا عوامل کارفرما ہوتے ہیں جو لفظ کی معنویت کا تعین کرتے ہیں۔ یہ وہ پیچیدہ مسئلہ ہے جو صدیوں سے لسانیات کا موضوع رہا ہے۔ موسیقی کا، لفظ اور معانی کے اس پیچیدہ مسئلے سے ایک خاص تعلق ہوتا ہے۔ دوسرا لفظ کے غنائی یا صوتی تصور کے حوالے سے دیکھا جائے تو موسیقی میں میں حروف علّت (vowel) حروفِ صحیح (consonant) کی نسبت زیادہ اہمیت رکھتے ہیں۔
اگر یہ کہا جائے کہ موسیقی کا اصل تعلق حروفِ علّت سے ہے تو غلط نہ ہو گا، کیونکہ یہی وہ حروف ہیں جن کو کھینچ تان کر کے یا گھٹا بڑھا کر ان سے صوتیت یا غنا پیدا کی جاتی ہے۔ اس امر کی وضاحت کے لیے یہ جملہ دیکھیے:
میں آج گھر جاؤں گا
میں آج گھر جاؤں گا
میں آج گھر، جاؤں گا
میں آج، گھر جاؤں گا
میں آج گھر جاؤں گا؟
میں آج گھر جاؤں گا!
آپ اس جملے سے سمجھ سکتے ہیں کہ اگر اسے روزمرّہ کے مطابق مختلف طریقوں سے ادا کیا جائے تو مختلف معانی پیدا کیے جا سکتے ہیں۔ جملے سے مختلف معانی برآمد کرنے کے لیے صرف الفاظ پر تاکید کو بدلنا ہوگا۔ جملے میں مختلف مقامات پر ٹھہرنے اور کچھ الفاظ کو کھینچ کر ادا کرنے سے مفاہیم میں تبدیلی واقع ہوتی جائے گی۔ یہ معنی آفرینی عمل موسیقی میں اساسی حیثیت رکھتا ہے۔
موسیقی میں حروف علّت پر معنی آفرینی کے اس عمل سے ایک ہی لفظ سے مختلف احساسات اور اس کی معنویت کو برآمد کرنا ممکن ہے۔
اس طرح ایک ہی لفظ سے حیرت، استعجاب، خوف، امید، مسرت، طنز، نفی، اثبات اور استفہام کی معنویت برآمد کی جاسکتی ہے۔ اور ایک ہی لفظ سے کثیرالمعانی کے اس امر کی مثالوں کو صرف اور صرف موسیقی سے ہی سمجھا جاسکتا ہے جب ایک لفظ کو مختلف غنائی لہجوں میں ادا کیا جائے تو اس امر کی وضاحت ہو جاتی ہے۔
زبان کے عام بول چال کے لہجہ کے برعکس زبان کے غنائی لہجہ سے الفاظ کی معنویت بدلتی ہے۔ عام بول چال کے لہجے میں لفظوں کی معنویت متعین ہوتی ہے جب کہ موسیقی میں ماہر مغنّی اپنے غنائی لہجے کے اتار چڑھاؤ سے ان کے معنی اور احساسات میں رد و بدل کرتا ہے۔ معنی آفرینی کا یہ عمل موسیقی میں خاص کر ان جذبات و کیفیات کےابلاغ کا سبب بنتا ہے جہاں ابلاغ کے دیگر ذرائع پوری طرح ساتھ نہیں دے پا تے۔ بقول رشید ملک:“جہاں ابلاغ کے مختلف ذرائع کی سرحدیں ختم ہوتی ہیں وہاں سے موسیقی کی اقلیم شروع ہوتی ہے۔ موسیقی بھی ایک زبان ہے۔ جس کے اپنے حروفِ تہجی، اپنے الفاظ، اپنی لسانی ترکیبیں، اپنا روزمرّہ، صرف و نحو اور فصاحت و بلاغت کے لیے اپنے معیار ہیں۔ یہ زبان ان کیفیات اور جذبات کا ابلاغ کرتی ہے جن کی ترسیل کسی اور ذریعے سے ممکن نہیں۔”
(راگ درپن کا تنقیدی جائزہ)
یہی وجہ ہے کہ کسی فلم میں ڈرامائی عناصر کو تقویت دینے میں موسیقی ایک اہم اور بنیادی کردار ادا کرتی ہے۔ فلمی گانوں کو فلمی سین، کسی ایکٹر کی شخصیت یا اس کے جذبات و احساسات کو اجاگر کرنے یا ابھارنے کے لیے ترتیب دیا جاتا ہے۔ بعض دفعہ فلم یا ڈراما میں کسی کردار کی باطنی کیفیت کا ابلاغ کسی گانے ہی کے ذریعے ممکن ہوتا ہے۔
فلمی موسیقی میں شعری ضابطے بنیادی اہمیت رکھتے ہیں اور گانے کے الفاظ کا معانی کے ساتھ گہرا اور مضبوط رشتہ استوار کرنے کے لیے چاہے فنِ موسیقی کے دیگر اصول و ضوابط کو نظرانداز ہی کیوں نہ کرنا پڑے۔ یہی صورتحال عوامی موسیقی میں ہوتی ہے۔ عوامی موسیقی میں بھی شاعری بنیادی اہمیت کی حامل ہوتی ہے اور لفظوں کی ادائیگی میں گانے والا معانی اور تفہیم کے عمل کو بنیادی اہمیت دیتا ہے، گائیکی کے اس عمل میں سُر کی اور دیگر فنِ موسیقی کی شعریات ثانوی حیثیت اختیار کر جاتی ہیں۔ فلمی موسیقی اور عوامی موسیقی میں اکثر گانوں میں ایسی مثالیں ملتی ہیں۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ فلمی موسیقی اپنی ذات میں ایک فن نہیں ہے بلکہ ایک ہنر یا تکنیک ہے جس کا مقصد صرف اور صرف ڈرامائی عناصر کو تقویت دینا ہوتا ہے۔ فلمی موسیقی ہو یا فلمی شاعری دونوں فلم کی کہانی کے تابع ہوتے ہیں۔ باوجود اس کے فلمی موسیقی ہر دور میں ایک خاص اہمیت کی حامل رہی ہے۔
اس کی اپنی ایک خاص وضع قطع ہوتی ہے۔ فلمی گانے کافی چنچل اور شوخ ہونے کے ساتھ ساتھ کافی اثر انگیز ہوتے ہیں جن میں معنوی گہرائی بدرجۂ اتم موجود ہوتی ہے۔ فلمی موسیقی اور فلمی شاعری خاص طرح کا رومانی تأثر لیے ہوئے ہوتے ہیں جس سے ڈرامائی کیفیت کا تأثر بھرپور انداز سے ابھر کر سامنے آجاتا ہے۔
کلاسیکی موسیقی یا موسیقی کی آرٹ فارم جو کافی ریاضت طلب فن ہے، فلمی موسیقی اور عوامی موسیقی سے کافی مختلف ہے۔ فلمی موسیقی اور عوامی موسیقی کے بر عکس اس میں لفظوں کو سُر کے تابع کر کے ادا کیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ موسیقی کی اس آرٹ فارم میں ہمیشہ سُر کو اوّلیت حاصل رہی ہے۔ راگ کا الاپ، گانے کو مکمل طور پر راگ کے رچاؤ کے ساتھ مخصوص کلاسیکل لے تال میں پیش کرنا کلاسیکی موسیقی کی خاصیت ہے۔
کلاسیکی گائیکی میں فنِ موسیقی کی تمام حدود و قیود اور ضابطوں کا پابندی کے ساتھ خیال رکھا جاتا ہے۔ جب کہ فلمی موسیقی یا عوامی موسیقی میں یہ پابندیاں ضروری نہیں ہوتیں۔ کلاسیکی موسیقی میں جو گانے والا ہوتا ہے وہ ایک منجھا ہوا مغنّی ہوتا ہے جو فن کی باریکیوں پر مکمل دسترس رکھتا ہے اور گانے کے دوران اس کی پیش کش باقی تمام چیزوں پر حاوی رہتی ہے۔ مثلاً وہ سازوں میں خود کو پابند کر کے نہیں گائے گا اور نہ ہی اس کی گائیکی کا انداز پہلے سے متعین کردہ ہوگا۔ اس کا تان، پلٹا، مرکی، زمزمہ اور دوسرے النکار وغیرہ ہر چکر میں پہلے والے تان، پلٹے اور زمزمہ سے مختلف اور جداگانہ ہوں گے۔
موسیقی کی جمالیات بھی یہی تقاضا کرتی ہے کہ غنائی ترکیبوں کی تکرار پیدا نہ کی جائے کیوں کہ اعادے اور تکرار سے فن پارہ معیار سے گر جاتا ہے۔ گانے کے آغاز سے لے کر اختتام تک وہ ہر چیز سے آزاد رہے گا۔ لیکن اس کی گائیکی موسیقی کے اصول و ضوابط سے باہر نہیں جائے گی۔ پوری گائیکی کے دوران مغنی کا سارا زور راگ کو متشکل کرنے پر صرف ہو گا۔ کیوں کہ کلاسیکی موسیقی اور دیگر موسیقی کے اوضاع میں یہی فرق ہوتا ہے کہ کلاسیکی موسیقی میں راگ اپنی تمام رعنائیوں اور جمالیات کےساتھ سامنے آتا ہے کلاسیکی گائیک اور فلمی موسیقی کے گائیک میں وہی فرق ہوتا ہے جو فلمی شاعر اور غیر فلمی شاعر میں ہوتا ہے۔
فلمی شاعر اپنی شاعری اور موضوع کی تخلیق کے حوالے سے فلمی کہانی اور اس کے ڈرامائی عناصر کا پابند ہو گا جب کہ غیر فلمی شاعر ایسی تمام روشوں سے آزاد ہو گا جن کا تعین پہلے سے کیا گیا ہو گا۔ فلمی شاعر کے برعکس غیر فلمی شاعر تخیل، موضوع اور جذبات و احساسات میں پہلے سے متعین کی گئی کسی چیز کا پابند نہیں ہوگا۔ اس کی شاعری اس کے اپنے جذبات، تجربات اور مشاہدات کی غماز ہوگی، لیکن شاعری کے اصول و ضوابط کا وہ پوری طرح خیال رکھے گا۔
جہاں تک کلاسیکی موسیقی میں لفظ اور اس کے معانی کا تعلق ہے تو کلاسیکی موسیقی کی آرٹ فارم میں لفظ اور معنی کا آپس میں رشتہ معطل ہو جاتا ہے، لفظ کو اس طرح سُر میں توڑ موڑ کر ادا کیا جاتا ہے کہ اس کی غنائی اہمیت تو بڑھ جاتی ہے لیکن معنوی سطح پر وہ گر جاتا ہے۔ اس ضمن میں رشید ملک رقم طراز ہیں: “جب موسیقی آرٹ فارم بنتی ہے تو الفاظ اور معانی کا رشتہ معطل ہو جاتا ہے۔ لفظ اپنی ادبی حیثیت کھو دیتا ہے۔ اور اپنی انفرادیت سے دست کش ہو کر نئی نئی صورتیں اختیار کرتا چلا جاتا ہے۔”
(راگ درپن کا تنقیدی جائزہ)
دھرو پد، خیال، ترانہ، پربندھ، دھمار، تروٹ اور پَدجو موسیقی کی آرٹ فارم کی اہم اقسام ہیں، ان میں پوری توجہ سُر پر ہی رہتی ہے اور لفظ ٹکڑوں میں تقسیم اس طرح ہو جاتا ہے کہ اس کی پہچان کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ الفاظ کی شکل و صورت یعنی مارفولوجی بالکل بدل جاتی ہے۔ دوسرے لفظوں میں موسیقی کی آرٹ فارم میں شعری ضابطے ثانوی سطح پر چلے جاتے ہیں اور موسیقی کی شعریات کی پابندی اور سُر کی ادائیگی ہر چیز سے مقدم ہو جاتی ہے۔ موسیقی کی اس فارم میں سُروں کے ذریعے جذبے یا احساس کی ترسیل کی جارہی ہوتی ہے جو کافی مشکل کام ہوتا ہے۔ لفظ کی معنویت کو غنائی ترکیب سے برآمد کیا جا رہا ہوتا ہے۔
نیم کلاسیکی موسیقی دیگر موسیقی کی فارمز کی نسبت موسیقی کی آرٹ فارم کے قدرے زیادہ قریب ہے۔ نیم کلاسیکی موسیقی میں ٹھمری، غزل اور کافی وغیرہ آجاتے ہیں لیکن ان میں بھی لفظ کا معنی کے ساتھ مکمل طور پر رشتہ قائم رہتا ہے اور گائیکی کے دوران شعری ضابطے زیادہ اہمیت اختیار کیے رکھتے ہیں۔ جب کہ موسیقی کی آرٹ فارم میں لفظ کے معانی غنا میں معدوم ہو جاتے ہیں۔ بعض اوقات تو لفظ کی ادائیگی کو اس طرح غنائی ترکیب میں باندھا جاتا ہے اس کی شکل بھی بگڑ کر رہ جاتی ہے۔ دراصل موسیقی کی آرٹ فارم جو خالص کلاسیکی موسیقی پر مشتمل ہے اس میں مغنی فن موسیقی کے تمام اصولوں و ضوابط کو دیگر تمام چیزوں پر چاہے وہ شاعری ہے، لفظ یا اس کی معنوی وضاحت ہے، سب پر مقدم سمجھتا ہے۔
اس کی وجہ یہ ہے کہ موسیقی کی آرٹ فارم اپنی ذات میں مکمل ایک زبان ہے جس میں جذبات و احساسات اور مافی الضمیر کا ابلاغ سُروں کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ اور ایسے خفیف جذبات و احساسات جن کا ابلاغ لفظ اور اس کی معنوی کشمکش میں پھنس کر رہ جاتا ہے، ایسے جذبات و احساسات کا ابلاغ موسیقی کی آرٹ فارم کے ذریعے ہی ممکن ہوتا ہے۔ بشرطے کہ اس فارم میں “ابلاغ کے فن” پر مغنّی پوری طرح دسترس رکھتا ہو۔ اس کے فن میں کسی طرح کا جھول نہ ہو اور وہ لفظوں کے صوتی تاثر سے ہی معنی پیدا کرنا جانتا ہو۔ لفظ کی صوتی تاثیر کے حوالے سے ابوالاعجاز حفیظ صدیقی لکھتے ہیں: “معانی سے الگ ہو کر بھی ہر لفظ کا اپنا ایک خاص تاثر ہوتا ہے جس کا تعلق ان حروف کی آوازوں اور ان کی ترتیب سے ہوتا ہے جن سے کوئی لفظ بنتا ہے۔ کوئی لفظ ناچتا، گنگناتا ہے، کوئی روتا بسورتا ہے۔ کوئی لبھاتا ہے، کوئی سننے والے کے ذہن پر خوف کا تأثر چھوڑتا ہے اور کوئی سرخوشی و سرمستی کا تأثر دیتا ہے۔ لفظ کے اس تأثر کو جس کا تعلق لفظ کی آوازوں سے ہوتا ہے صوتی تأثر کہتے ہیں۔”
(کشاف تنقیدی اصطلاحات)
لفظ کی موسیقیت دو حصّوں پر مشتمل ہوتی ہے، اصوات کی موسیقیت اور معانی کی موسیقیت۔ اوّل الذّکر کا تعلق اس صوتی تأثر سے ہے جو ان حروف کی آوازوں پر مشتمل ہوتا ہے جس سے وہ لفظ تشکیل پاتا ہے۔ صوتی تأثر سے تشکیل پانے والی موسیقی لفظ کی خارجی موسیقی کہلائے گی۔ مؤخر الذّکرکا تعلق لفظ کی معنوی تاثیر سے ہوتا ہے۔ لفظ کے معنوی احساس سے ایک لطیف موسیقیت وجود میں آتی ہے۔ معنوی تاثر سے پیدا ہونے والی موسیقی لفظ کی داخلی موسیقی کہلائے گی۔
کلاسیکی موسیقی میں تیسرا اہم شعبہ تال کا ہوتا ہے۔ موسیقی کی آرٹ فارم میں تال کا چکر اپنے متعین کردہ ماتروں کے ساتھ ایک دائرہ میں حرکت کرتا ہے۔ تال دو حصّوں پر مشتمل ہوتی ہے۔
موسیقی کی کوئی فارم بھی تال کے بغیر تشکیل نہیں پا سکتی۔ بندش کے لفظ چاہے وہ حروف صحیح پر مشتمل ہوں یا حروف علّت پر سب تال میں بندھے ہوتے ہیں۔ بالکل اسی طرح جس طرح کسی موزوں شعر کے الفاظ اس کی بحر کے ساتھ بندھے ہوتے ہیں۔
(از قلم: یاسر اقبال، کتابیات: راگ درپن کا تنقیدی جائزہ، ایلیٹ کے مضامین، شعر، غیر شعر اور نثر، کشاف تنقیدی اصطلاحات، تنقید کی شعریات، مبادیاتِ موسیقی)