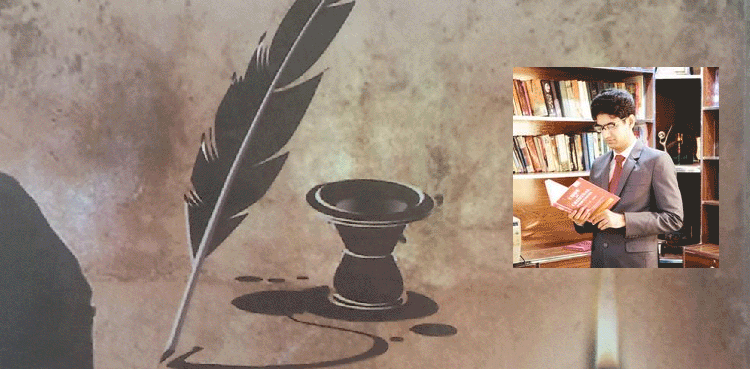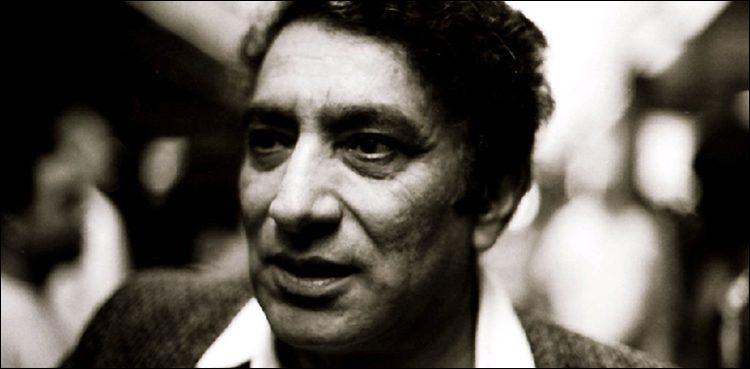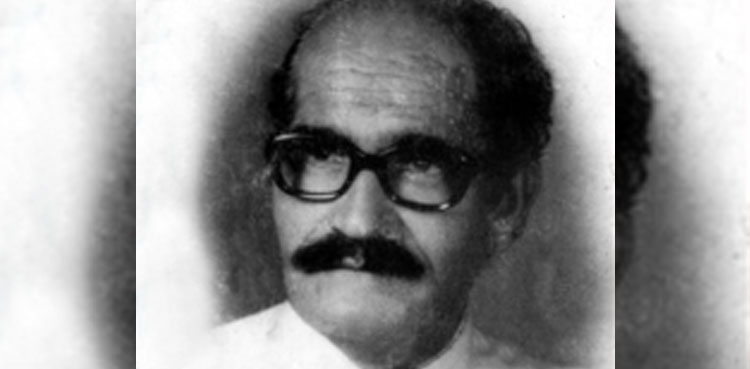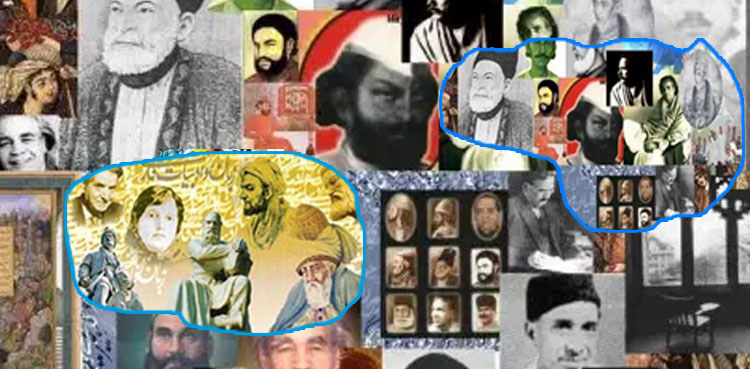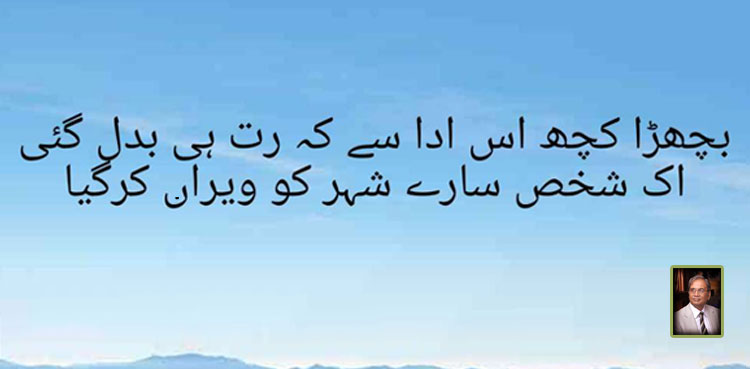بہادر شاہ ظفر کے پاس فوج کا لشکر تھا، نہ تیر اندازوں کا دستہ، ایسے تیر انداز جن کا نشانہ خطا نہ جاتا۔ شمشیر زنی میں ماہر سپاہی یا بارود بھری بندوقیں تان کر دشمن کا نشانہ باندھنے والے بھی نہیں تھے، لیکن ان کی آواز پر جنگِ آزادی لڑنے کے لیے ہندو اور مسلمان دونوں اٹھ کھڑے ہوئے اور تاجِ شاہی کے لیے اپنی جانیں قربان کر دیں۔
1837ء میں اکبر شاہ ثانی کے بعد ابوالمظفر سراج الدّین محمد بہادر شاہ غازی نے مغلیہ سلطنت کا تاج اپنے سَر پر سجایا، لیکن اپنے مرحوم باپ اور مغل بادشاہ کی طرح بے اختیار، قلعے تک محدود اور انگریزوں کے وظیفہ خوار ہی رہے۔ عظیم مغل سلطنت اب دہلی و گرد و نواح میں سمٹ چکی تھی، لیکن لوگوں کے لیے وہ شہنشاہِ ہند تھے۔
پیری میں اقتدار سنبھالنے والے بہادر شاہ ظفرؔ کو اندازہ ہوگیا تھا کہ ان کے ہاتھ کچھ نہیں۔ مسند نشینی سے 1857ء کی جنگِ آزادی تک ان کا دور ایک نہ ختم ہونے والی شورش کی داستان سے پُر تھا۔
وہ ایسے شہنشاہ تھے جنھیں زر و جواہر سے معمور شاہی خزانہ ملا، نہ بیش قیمت ہیرے۔ پکھراج کے قبضے والی وہ تلواریں بھی نہیں جنھیں خالص سونے کے بنے ہوئے نیام میں رکھا جاتا ہو، لیکن رعایا ان سے بے پناہ عقیدت رکھتی تھی اور ان کی تعظیم کی جاتی تھی۔ البتہ ظفرؔ کے مزاج میں شاہی خُو بُو نام کو نہ تھی۔ انھیں ایک دین دار، نیک صفت اور بدنصیب بادشاہ مشہور ہیں۔
بہادر شاہ ظفر، شیخ فخرالدّین چشتی کے مرید تھے اور ان کے وصال کے بعد قطب الدّین چشتی سے بیعت لی۔ انگریزوں کے برصغیر سے جانے کے بعد ان کا عرس ہر سال باقاعدگی سے منایا جانے لگا اور بالخصوص برما کے مسلمان انھیں صوفی بابا ظفر شاہ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔
بہادر شاہ ظفرؔ 14 اکتوبر 1775ء کو ہندوستان کے بادشاہ اکبر شاہ ثانی کے گھر پیدا ہوئے۔ بہادر شاہ ظفر نے 1840ء میں زینت محل کو اپنا شریکِ حیات بنایا جن کے بطن سے مرزا جواں بخت پیدا ہوئے تھے۔
بہادر شاہ ظفرؔ کو اپنے دادا شاہ عالم ثانی کی صحبت میں رہنے اور سیکھنے کا بھرپور موقع ملا۔ انھوں نے اردو، فارسی، عربی اور ہندی پر دست گاہ حاصل کی۔ وہ خطّاط اور خوش نویس بھی تھے۔ گھڑ سواری، تیر اندازی، شمشیر زنی میں بھی اپنا لوہا منوایا۔ انھیں ایک غیرمتعصب حکم ران بھی کہا جاتا ہے۔
انگریزوں نے 1857ء میں غدر، یعنی جنگِ آزادی کی ناکامی پر بہادر شاہ ظفر کو جلا وطن کر کے رنگون(برما) بھیج دیا تھا جہاں وہ بے یار و مددگار، عسرت اور وا ماندگی کے عالم میں وفات پاگئے۔
بہادر شاہ نے زندگی کے آخری چار سال اپنی بیوی زینت محل کے ساتھ رنگون میں شویڈاگون پاگوڈا کے جنوب میں ملٹری کنٹونمنٹ میں گزارے۔ ان کے معتقدین اور پیروکاروں کے اشتعال اور بغاوت کے خطرے کے پیشِ نظر انگریزوں نے انھیں اسی گھر کے ایک کونے میں دفن کردیا اور ان کی قبر کو بے نام و نشان رہنے دیا۔
بہادر شاہ ظفر کا یہ شعر آخری ایّام میں عالمِ حسرت و یاس اور ان کے صدمہ و کرب کا عکاس ہے۔
بھری ہے دل میں جو حسرت، کہوں تو کس سے کہوں
سنے ہے کون، مصیبت کہوں تو کس سے کہوں
بادشاہ نے میانمار کے شہر رنگون کے ایک خستہ حال چوبی مکان میں اپنے خاندان کے گنے چنے افراد کی موجودگی میں دَم توڑا تھا۔ 7 نومبر 1862ء کو بہارد شاہ ظفر کی برسی منائی جاتی ہے۔ ان کا یہ شعر دیکھیے۔
ہے کتنا بدنصیب ظفر دفن کے لیے
دو گز زمین بھی نہ ملی کوئے یار میں
ہندوستان کے آخری بے تخت و تاج مغل بادشاہ کا سب سے بڑا ورثہ ان کی اردو شاعری ہے۔ ان کی غزلیں برصغیر بھر میں مشہور ہوئیں۔ ان کا کلام نام ور گلوکاروں نے گایا اور ان کی شاعری پر مقالے اور مضامین تحریر کیے گئے۔
مولانا حالیؔ نے کہا ظفر کا تمام دیوان زبان کی صفائی اور روزمرّہ کی خوبی ہیں، اوّل تا آخر یکساں ہے۔‘‘ اسی طرح آبِ بقا کے مصنّف خواجہ عبد الرّؤف عشرت کا کہنا ہے کہ ’’اگر ظفر کے کلام پر اس اعتبار سے نظر ڈالا جائے کہ اس میں محاورہ کس طرح ادا ہوا ہے، روزمرہ کیسا ہے، اثر کتنا ہے اور زبان کس قدر مستند ہے تو ان کا مثل و نظیر آپ کو نہ ملے گا۔
ظفر بحیثیت شاعر اپنے زمانہ میں مشہور اور مقبول تھے۔ ‘‘ منشی کریم الدین ’’ ’’طبقاتِ شعرائے ہند‘‘ میں لکھتے ہیں۔ ’’شعر ایسا کہتے ہیں کہ ہمارے زمانہ میں ان کے برابر کوئی نہیں کہہ سکتا۔
بہادر شاہ ظفر کے ساتھ بطور شاعر بھی ناانصافی روا رکھی گئی۔ وہ اپنے دور کے معروف شعرا میں سے ایک تھے، لیکن بدقسمتی سے انھیں کلاسیکی شاعروں کے تذکروں میں وہ مقام نہیں دیا گیا جس کے وہ حق دار تھے۔ اکثر بلاتحقیق اور غیرمستند یا سنی سنائی باتوں کو ضبطِ تحریر میں لاتے ہوئے قلم کاروں نے ان کے کلام کو استاد ذوق سے منسوب کیا ہے۔
بہادر شاہ ظفر نے استاد ذوق سے بھی اصلاح لی اور اسی لیے یہ بات مشہور ہوئی۔ تاہم ادبی محققین اور بڑے نقّادوں نے اسے غلط قرار دیتے ہوئے ظفر کی شاعرانہ عظمت کو تسلیم کیا ہے۔ ان کی شاعری میں زندگی کے سارے رنگ نمایاں ہیں لیکن یاسیت اور جمالیات کے رنگوں کا درجہ سب سے بلند ہے۔
معروف ادبی محقّق منشی امیر احمد علوی کے مطابق بہادر شاہ ظفر نے پانچ دیوان چھوڑے جن میں ایک ہنگاموں کی نذر ہوگیا اور چار دیوان کو لکھنؤ سے منشی نول کشور نے شایع کیا۔
بہادر شاہ ظفر کی مسند نشینی سے جلاوطنی اور بعد کے واقعات پر مؤرخین کے علاوہ ادیبوں اور نقّادوں نے بھی ان کے فنِ شاعری پر کئی کتابیں لکھی ہیں۔