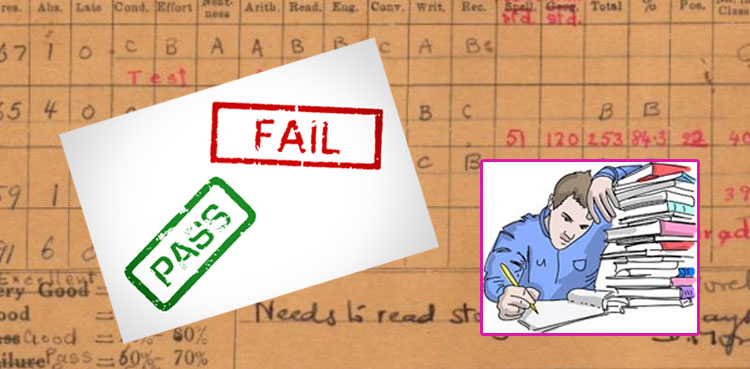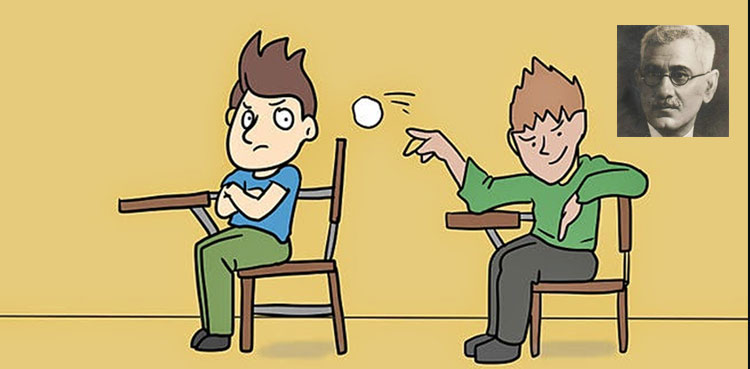آپ پوچھیں گے کہ میرے دل میں ایسا خیال کیوں آیا؟
آپ اسے خیال کہہ رہے ہیں؟ جناب یہ تو میری آرزو ہے، ایک دیرینہ تمنا ہے۔ یہ خواہش تو میرے دل میں اس وقت سے پل رہی ہے، جب میں لڑکے لڑکی کا فرق بھی نہیں جانتی تھی۔
اس آرزو نے اس دن میرے دل میں جنم لیا، جب پہلی بار میرے بھائی کو مجھ پر فوقیت دی گئی، ’جب‘ اور ’اب‘ میں اتنا ہی فرق ہے کہ جب میں یہ سوچا کرتی تھی کاش میں لڑکا (بھائی) ہو جاتی، اور ان سارے سرکش اور فضول سے بھائیوں سے گن گن کر بدلہ لیا کرتی اور ان کی وہ پٹائی کرتی، کہ وہ بھی یاد کرتے۔ اور اب یہ سوچا کرتی ہوں کاش میں مرد (شوہر) بن جاتی اور میرے ’مظلوم اور بے زبان‘ شوہر میری بیوی۔
یہی وجہ ہے کہ ایک بار جب ’وہ‘ بڑے طمطراق سے بولے، ’’کیا ہی اچھا ہوتا کہ میں بیوی ہوتا اور تم شوہر‘‘ تو میں نے جھٹ یہ جواب دیا، ’’تو بن جائیے نا، اس میں سوچنے کی کیا بات ہے؟‘‘
’’اچھا تو یہ بتاؤ کہ تم شوہر، ہوتیں تو کیا ہوتا؟‘‘
’’وہ نہ ہوتا جو آج ہو رہا ہے۔‘‘
’’مان لو کہ تم شوہر ہو گئیں۔ اب بتاؤ، تم کیا کرو گی؟‘‘
’’تو پھرمیں گن گن کر بدلہ لوں گی اور کیا کروں گی، لیکن ذرا مجھے اس بات پر خوش تو ہولینے دیجیے۔‘‘
اور سچ مچ میرے اوپر تھوڑی دیر تک ایک عجیب سی کیفیت طاری رہی۔ اس روح پرور خیال نے میرے پورے جسم و جان میں ایک وجدانی کیفیت پیدا کردی اور میں سوچنے لگی، کہ واقعی اگر میں شوہر بن جاتی تو کیا ہوتا، لیکن اتنا ہی تو کافی نہیں ہوتا کہ میں شوہربن جاتی، اس کے ساتھ میرے شوہر بھی تو میری بیوی بنتے۔ مزہ تو جب ہی تھا۔
ذرا تصور کی آنکھ سے دیکھیے۔ اب میں شوہر بن گئی ہوں۔ مجھے کہیں دعوت میں جانا ہے، میں اپنی تیاری شروع کرتا ہوں۔ شیو بناتا ہوں، نہاتا ہوں، گھنٹہ بھر آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر کریم پوڈر مل مل کر بڑی مشکل سے اپنے کالے چہرے کو سانولے کی حد تک لے آتا ہوں، پھر ٹائی باندھتا ہوں، ناٹ درست کرنے میں بھی کم وبیش آدھا گھنٹہ لگ ہی جاتا ہے، پریس کی ہوئی پینٹ کی کریز درست کرتا ہوں، ٹائی کے ہم رنگ نمائشی رومال کو کوٹ کی اوپری جیب میں باقاعدہ جماتا ہوں، وہ گندا رومال جو منہ، ہاتھ، چشمہ اور جوتے پونچھنے کے کام آتا ہے، اسے پینٹ کی جیب میں رکھتا ہوں۔
اپنے فارغ البال ہوتے ہوئے سر پر بچے کھچے بالوں کی تہ اچھی طرح جماتا ہوں، تاکہ کہیں سے سپاٹ چاند نہ نمودارہوجائے۔ گھر میں بدقسمتی سے ایک ہی آئینہ ہے اور اس پر کم و بیش ڈھائی تین گھنٹے میرا قبضہ رہتا ہے۔ گھر کے جملہ امور نوکر کو سمجھانے اور دروازے وغیرہ اچھی طرح بند کرنے کی ہدایت دے چکنے کے بعد جب میری بیوی (یعنی میرے موجودہ شوہر) آئینہ کے سامنے کھڑی ہوکر میک اپ شروع کرتی، تو میں ٹھیک اپنے موجودہ شوہر کی طرح کہتا ہوں، ’’بس اب تیار ہو بھی ہو چکو، تمہاری وجہ سے پارٹی میں دیر ہوگئی۔ خدا بچائے عورتوں کے سنگھار اور آرائش سے۔‘‘
میرے بار بار کہنے پر کہ دیر ہو رہی ہے، جلدی کرو، وہ غریب پندرہ منٹ میں الٹی سیدھی تیار ہوجاتی ہے اور جلدی میں ایک نئی اور ایک پرانی چپل پہن کر، یا ساڑی سے میچ کرتا ہوا پرس میز ہی پر چھوڑ کر پرانا پھٹا ہوا پرس ہاتھ میں لٹکائے چل پڑتی ہے، اور میں اس کی سابق شوہرانہ زیادیتوں کو یاد کر کے دل ہی دل میں خوش ہوتا ہوا اس کے ساتھ ہو لیتا ہوں۔ جب ہم دعوت میں پہنچتے ہیں تو تقریباً لوگ واپس جارہے ہوتے ہیں لیکن میں بڑی آسانی سے یہ کہہ کر صاف بچ جاتا ہوں۔
’’معاف کیجیے گا، ان کی تیاریوں میں دیر ہوگئی۔ عورتوں کا میک آپ تو آپ جانتے ہی ہیں۔‘‘
پھر بھلا کس میں ہمّت ہے کہ اس عالم گیر جھوٹ (جسے حقیقت کہا جاتا ہے) سے انکار کردے۔
شوہر بننے کے ایک اور افادی پہلو پر بھی ذرا غور کر لیں۔ مجھے کہیں صبح سویرے ہی جانا ہے، دسمبر کی کڑکڑاتی سردی ہے۔ میں گھڑی میں چار بجے کا الارم لگا کر سوجاتا ہوں، میری بیوی الارم کی کرخت اور مسلسل آواز سے گھبرا کر اٹھ بیٹھتی ہے اور باورچی خانہ میں جاکر ناشتے کی تیاری میں جٹ جاتی ہے۔ اتنے سویرے نوکر کو اٹھانے کی کس میں ہمّت ہے، آپ ہی بتائیے، جب شوہر نہیں اٹھتا، تو نوکر کیا اٹھے گا۔
باورچی خانے میں کھٹ پٹ کی آواز ہوتی رہتی ہے، اور میں لحاف میں دبکا پڑا رہتا ہوں۔ گرما گرم پراٹھوں، انڈوں حلوے وغیرہ کی اشتہا انگیز خوشبو بھی مجھے بستر سے اٹھانے میں ناکام رہتی ہے تو پھر میری بیوی آتی ہے، ہولے ہولے مجھے اٹھاتی ہے، اور پھر جب میں گرم پانی سے شیو کرنے اور نہانے کے بعد تیار ہو کر میز پر پہنچتا ہوں تو ناشتہ کی بیش تر چیزیں اور چائے ٹھنڈی ہوچکی ہوتی ہے، اور ان چیزوں کے دوبارہ گرم ہونے میں جو وقت لگتا اسے اپنے لیٹ ہونے کا ذمہ دار قرار دے کر بکتا جھکتا میں گھر سے روانہ ہوجاتا ہوں۔
اگر میں شوہر ہوتی۔ تو اس وقت کتنا مزا آتا جب دفتر سے ٹھیک ٹائم سے واپسی پر دفتر کے کینٹین یا کسی دوسرے ریستوران میں دوستوں کے ساتھ چائے ناشتہ کرتے ہوئے خوش گپیاں کرنے کے بعد منہ سکھائے ہوئے دفتر کے کام سے تھک جانے اور اپنے باس کی زیادتیوں کی شکایت لیے ہوئے گھر میں داخل ہوتا اور بے دم ہو کر مسہری پر گر پڑتا۔
بیوی بے چاری لپک کر جوتے اتارتی، پنکھا آن کرتی اور تکیے وغیرہ ٹھیک سے رکھ دیتی اور تھوڑی دیر کے لیے میرے آرام و سکون کی خاطر گھر کے تمام ہنگاموں کو روک دیا جاتا اور میں بیوی کی طرف سے کروٹ لیے دل ہی دل میں ہنسا کرتا۔
اور اس سے بڑھ کر مزا تو اس وقت آتا، جب دفتر سے نکلتے ہی یار لوگ کسی ادبی یا غیر ادبی پروگرام کے لیے باہر ہی باہر مجھے گھسیٹ لیتے اور ساڑھے پانچ بجے کی بجائے دس بارہ بجے رات کو تھکا ماندہ گھر پہنچتا اور بیوی کی عقل مندی اور تیزی و طراری کے باوجود اسے یہ باور کرانے میں کام یاب ہو جاتا کہ اسٹاف کی کمی کی وجہ سے آج میری ڈبل ڈیوٹی لگا دی گئی تھی۔
میری بیوی دفتر کے بدانتظامیوں کو برا بھلا کہتی ہوئی کھانا گرم کرنے چل پڑتی۔ باورچی خانے سے اس کی بڑبڑانے کی آواز آتی رہتی اور میں دل کھول کر خوش ہوتا اور مزے لیتا۔
ایک اور پُرلطف بات یہ ہوتی کہ میرے لیے پڑھنے لکھنے کا سامان اور سکون ہر وقت موجود ہوتا اور فرصت کے اوقات میں، میں بڑی آسانی سے لکھ پڑھ لیتا، میری زیادہ مصروفیت دیکھ کر میری بیوی گرم گرم چائے کی پیالی میز پر رکھ جاتی۔ یہی نہیں، بلکہ ایسے وقت میں ہر آنے والے کو ’’صاحب گھر میں نہیں ہیں‘‘ کا پیغام پہنچا دیا جاتا۔
اس وقت تو میری خوشی کا ٹھکانہ نہ ہوتا جب میں دیکھتا کہ میری بیوی اب کچھ لکھنے کو بیٹھی ہے۔ ابھی اسے کاغذ قلم لے کر بیٹھے ہوئے کچھ دیر بھی نہ ہوئی ہوتی کہ ملازم آدھمکتا۔
’’بی بی جی، سودا لایا ہوں، حساب ملا لیجیے۔‘‘ تھوڑی دیر بعد ہانک لگاتا، ’’بی بی جی گوشت کیسا پکے گا، شوربے دار یا بھنا ہوا۔‘‘ پھر ایک آواز آتی، ’’بی بی جی! کپڑے لائی ہوں، ملالیجیے۔‘‘ اور میری بیوی بھنّاتے ہوئے کاغذ قلم پٹخ کر دھوبن کا حساب کتاب کرنے اور پھر میلے کپڑے لکھنے کو چل پڑتی، اور جب اس سے کوئی پوچھتا کہ آپ کے لکھنے پڑھنے کو کیا ہوا تو جل کر جواب دیتی، ’’چولھے بھاڑ میں گیا۔‘‘
پہلی تاریخ کو ایک فرماں بردار شوہر کی مثال قائم کرتے ہوئے تنخواہ بیوی کے ہاتھ پر رکھتے ہوئے تمام آسانی اور زمینی آفتوں سے بری الذّمہ ہوجاتا۔ بے فکری کے دن اور رات کٹتے، کبھی سوچنے کی ضرورت نہ پڑتی کہ گھر کیسے چل رہا ہے۔ مقررہ جیب خرچ کے علاوہ بیوی کی صندوقچی پر بھی چھوٹے موٹے ڈاکے ڈالا کرتا اور اس کے پوچھنے پر اچھی خاصی جنگ کا ماحول پیدا کر دیتا۔ مجھے کبھی یہ پتہ نہ چلتا، کہ کب عید آئی اور کیسے بقرعید منائی گئی۔ ایک قربانی کے لیے بیوی نے کتنی قربانیاں دیں۔
دوسروں کے یہاں کی تقریبات نے اپنے گھر گرہستی کی دنیا میں کتنا بڑا زلزلہ پیدا کیا اور تنخواہ کی بنیادیں تک ہلیں۔ میں تو بس ٹھاٹ سے ان تقریبات میں حصہ لیا کرتا، دوستوں اور عزیزوں سے ملاقاتیں ہوتیں، مزے دار کھانے ملتے اور خوب تفریح رہتی۔ اگر میری بیوی کبھی میری فضول خرچی سے تنگ آکر بجٹ فیل ہونے کی بات کہتی، تو میں بڑے پیار سے کہتا، ’’جان من! بجٹ فیل تو ہر بڑی حکومت کا رہتا ہے، بجٹ کا فیل ہونا باعثِ فکر نہیں، بلکہ باعث عزت و شوکت ہے۔‘‘
تو جناب یہ ہے کہ میرا پروگرام۔ بس خدا ایک بار مجھے شوہر بنا دے تاکہ میں بھی فخر سے کہہ سکوں….
زندگی نام ہے ہنس ہنس کے جیے جانے کا
(طنز و مزاح پر مبنی یہ تحریر سرور جمال کی ہے جن کا تعلق بہار، بھارت سے ہے)