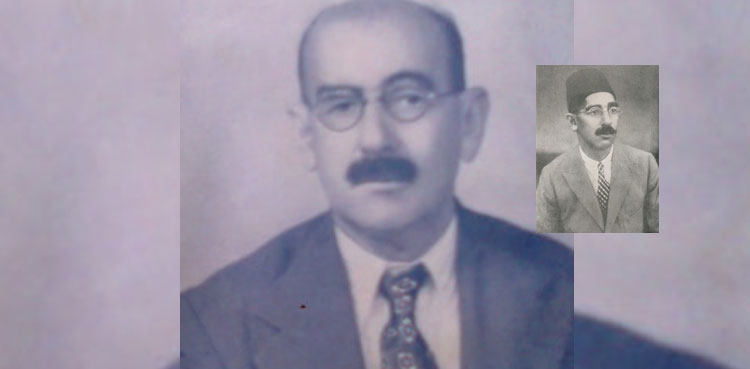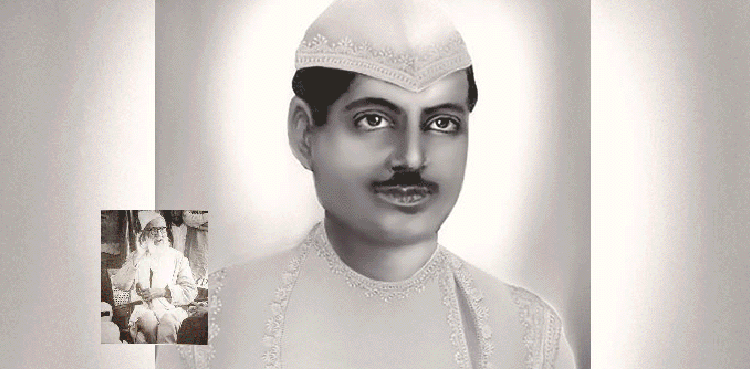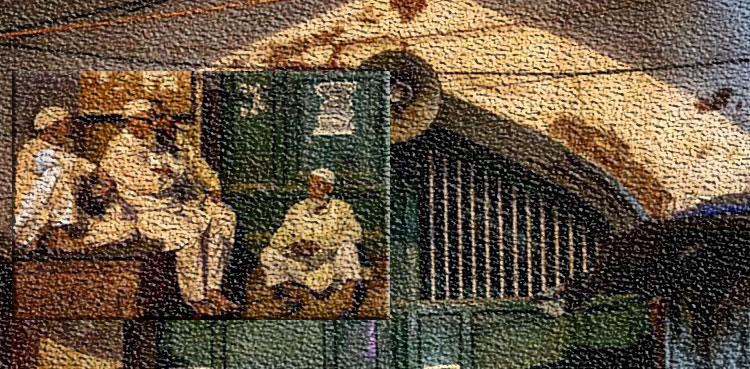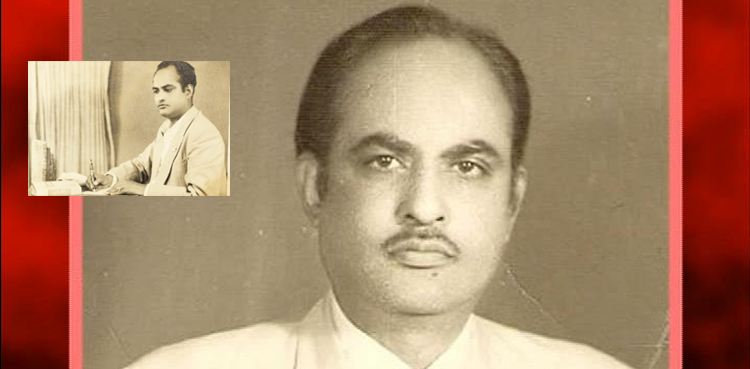یہ اس زمانے کی بات ہے جب میری عمر بس کوئی تیرہ چودہ برس کی تھی۔ ہم جس محلے میں رہتے تھے وہ شہر کے ایک بارونق بازار کے پچھواڑے واقع تھا۔
اس جگہ زیادہ تر درمیانے طبقے کے لوگ یا غریب غربا ہی آباد تھے۔ البتہ ایک پرانی حویلی وہاں ایسی تھی جس میں اگلے وقتوں کی نشانی کوئی صاحب زادہ صاحب رہا کرتے تھے۔
ان کے ٹھاٹھ تو کچھ ایسے امیرانہ نہ تھے، مگر اپنے نام کے ساتھ ’’رئیس اعظم‘‘ لکھنا شاید وہ اپنا فرض منصبی سمجھتے تھے۔ ادھیڑ عمر بھاری بھرکم آدمی تھے۔
گھر سے باہر ذرا کم ہی قدم نکالتے، ہاں ہر روز تیسرے پہر حویلی کے احاطہ میں اپنے احباب کے جھرمٹ میں بیٹھ کر گپیں لڑانا اور زورزور سے قہقہے لگانا ان کا دل پسند مشغلہ تھا۔
ان کے نام کی وجہ سے اکثر حاجت مند، یتیم خانوں کے ایجنٹ اور طرح طرح کے چندہ اگاہنے والے ان کے دروازے پر سوالی بن کر آیا کرتے۔ علاوہ ازیں جادو کے پروفیسر، رمال، نجومی، نقال، بھاٹ اور اسی قماش کے دوسرے لوگ بھی اپنا ہنر دکھانے اور انعام اکرام پانے کی توقع میں آئے دن ان کی حویلی میں حاضری دیا کرتے۔
جس زمانے کا میں ذکر کر رہا ہوں، ایک بہروپیا بھی طرح طرح کے روپ بھر کر ان کی حویلی میں آیا کرتا، کبھی خاکی کوٹ پتلون پہنے، چمڑے کا تھیلا گلے میں ڈالے، چھوٹے چھوٹے شیشوں اور نرم کمانیوں والی عینک آنکھوں پر لگائے چٹھی رساں بنا ہر ایک سے بیرنگ خط کے دام وصول کر رہا ہے۔ کبھی جٹا دھاری سادھو ہے، لنگوٹ کسا ہوا، جسم پر بھبوت رمائی ہوئی، ہاتھ میں لمبا سا چمٹا، سرخ سرخ آنکھیں نکال نکال ’’بم مہا دیو‘‘ کا نعرہ لگا رہا ہے۔ کبھی بھنگن کے روپ میں ہے جو سرخ لہنگا پہنے، کمر پر ٹوکرا، ہاتھ میں جھاڑو لیے جھوٹ موٹ پڑوسنوں سے لڑتی، بھڑتی آپ ہی آپ بکتی جھکتی چلی آرہی ہے۔
میرے ہم سبقوں میں ایک لڑکا تھا مدن۔ عمر میں تو وہ مجھ سے ایک آدھ برس چھوٹا ہی تھا مگر قد مجھ سے نکلتاہوا تھا، خوش شکل بھولا بھالا مگر ساتھ ہی بچوں کی طرح بلا کا ضدی۔
ہم دونوں غریب ماں باپ کے بیٹے تھے۔ دونوں میں گہری دوستی تھی۔ اسکول کے بعد کبھی وہ میرے محلے میں کھیلنے آجاتا، کبھی میں اس کے ہاں چلاجاتا۔
ایک دن سہ پہر کو میں اور مدن، صاحب زادہ صاحب کی حویلی کے باہر سڑک پر گیند سے کھیل رہے تھے کہ ہمیں ایک عجیب سی وضع کا بوڑھا آدمی آتا دکھائی دیا۔ اس نے مہاجنوں کے انداز میں دھوتی باندھ رکھی تھی، ماتھے پر سیندور کا ٹیکا تھا۔
یہ شخص حویلی کے پھاٹک پر پہنچ کر پل بھر کو رکا، پھر اندر داخل ہو گیا۔ میں فوراً جان گیا، یہ حضرت سوائے بہروپیے کے اور کون ہو سکتے تھے۔ مگر مدن ذرا ٹھٹکا۔ اس نے بہروپیے کو پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ میں نے ذرا چھیڑنے کو پوچھا:’’مدن جانتے ہو ابھی ابھی اس حویلی میں کون گیا ہے؟‘‘
’’کوئی مہاجن تھا۔‘‘
’’ارے نہیں پگلے یہ تو بہروپیا ہے بہروپیا!‘‘
’’بہروپیا؟“مدن نے کچھ حیرانی ظاہر کرتے ہوئے کہا۔
’’ارے تم نہیں جانتے۔ یہ لوگ طرح طرح کے روپ بھر کر امیر امرا کو اپنا کمال دکھاتے ہیں اور ان سے انعام لیتے ہیں۔‘‘
’’تو کیا یہ شخص ہر روز آتا ہے؟‘‘
’’نہیں، ہفتے میں بس دو ایک ہی بار۔ روز روز آئے تو لوگ پہچان جائیں۔ بہروپیوں کا کمال تو بس اسی میں ہے کہ ایسا سوانگ رچائیں کہ لوگ دھوکا کھا جائیں اور سچ سمجھنے لگیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ لوگ کسی شہر میں دو تین مہینے سے زیادہ نہیں ٹکتے۔‘‘
’’کیا ان کو ہر دفعہ انعام ملتا ہے؟‘‘
’’نہیں تو۔ یہ جب پندرہ بیس مرتبہ روپ بھر چکتے ہیں تو آخری بار سلام کرنے آتے ہیں، بس یہی وقت انعام لینے کا ہوتا ہے۔‘‘
’’بھلا کتنا انعام ملتا ہو گا انہیں؟‘‘
’’کچھ زیادہ نہیں، کہیں سے ایک روپیہ، کہیں سے دو روپے اور کہیں سے کچھ بھی نہیں۔ یہ رئیسِ اعظم صاحب اگر پانچ روپے بھی دے دیں تو بہت غنیمت جانو۔ بات یہ ہے کہ آج کل اس فن کی کچھ قدرنہیں رہی۔
اگلے وقتوں کے امیر لوگ تو اس قسم کے پیشے والوں کو اتنا اتنا انعام دے دیا کرتے تھے کہ انہیں مہینوں روزی کی فکر نہ رہتی تھی۔ مگر آج کل تو یہ بے چارے بھوکوں مر رہے ہوں گے اور۔۔۔‘‘
میں کچھ اور کہنے ہی کو تھا کہ اتنے میں وہی بہروپیا حویلی کے پھاٹک سے نکلا۔ مدن اسے دیکھ کر چونک پڑا۔ بہروپیا ہماری طرف دیکھ کر مسکرایا اور پھر بازار کی طرف چل دیا۔
بہروپیے کا پیٹھ موڑنا تھا کہ مدن دھیمی آواز میں کہنے لگا، ’’اسلم آؤ اس کا پیچھا کریں اور دیکھیں کہ وہ کہاں رہتا ہے، اس کا گھر کیسا ہے، اس کا کوئی نہ کوئی میک اپ روم تو ہوگا ہی، شاید اس تک ہماری رسائی ہو جائے، پھر میں یہ بھی دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ اپنی اصلی صورت میں کیا لگتا ہے۔‘‘
’’مدن دیوانے نہ بنو۔‘‘میں نے کہا،’’نجانے اس کا ٹھکانہ کدھر ہے۔ ہم کہاں مارے مارے پھریں گے۔ نجانے ابھی اس کو اور کن کن گھروں میں جانا ہے۔۔۔‘‘
مگر مدن نے ایک نہ سنی۔ وہ مجھے کھینچتا ہوا لے چلا۔ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ اس کے مزاج میں طفلانہ ضد تھی۔ ناچار میں اس کے ساتھ ہو لیا۔
یہ گرمیوں کی ایک شام تھی، کوئی چھے کا عمل ہو گا، اندھیرا ہونے میں ابھی کم سے کم ڈیڑھ گھنٹہ باقی تھا۔
وہ تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا ایک سے دوسرے بازار میں گزرتا جارہا تھا۔ راستے میں جب کبھی کوئی بڑی حویلی یا کسی مکان کا دیوان خانہ نظر آتا تو وہ بلاتکلف اندر داخل ہو جاتا اور ہمیں دو تین منٹ باہر اس کا انتظار کرنا پڑتا۔ بعض بڑی بڑی دکانوں میں بھی اس نے حاضری دی، مگر وہاں وہ ایک آدھے منٹ سے زیادہ نہ رکا۔ بہروپیا اب شہر کے دروازے سے باہر نکل آیا تھا اور فصیل کے ساتھ ساتھ چلنے لگا تھا۔
ہم نے اب تک بڑی کام یابی سے اپنے کو اس کی نظروں سے اوجھل رکھا تھا۔ اس میں بازاروں کی ریل پیل سے ہمیں بڑی مدد ملی تھی مگر اب ہم ایک غیر آباد علاقے میں تھے جہاں اکا دکا آدمی ہی چل پھررہے تھے۔
ہمیں زیادہ چلنا نہ پڑا۔ جلد ہی ہم ایک ایسے علاقے میں پہنچ گئے جہاں فصیل کے ساتھ ساتھ خانہ بدوشوں اور غریب غربا نے پھونس کے جھونپڑے ڈال رکھے تھے۔ بہروپیا آخری جھونپڑے کے پاس پہنچا جو ذرا الگ تھلگ تھا۔ اس کے دروازے پر ٹاٹ کا پردہ پڑا ہوا تھا۔
جھونپڑے کے باہر ایک ننھی سی لڑکی جس کی عمر کوئی تین برس ہو گی اور ایک پانچ برس کا لڑکا زمین پر بیٹھے کنکریوں سے کھیل رہے تھے۔ وہ خوشی سے چلانے لگے: ’’اباجی آگئے! ابا جی آگئے!‘‘ اور وہ اس کی ٹانگوں سے لپٹ گئے۔
بہروپیے نے ان کے سروں پر شفقت سے ہاتھ پھیرا، پھر ٹاٹ کا پردہ سرکا کر بچوں سمیٹ جھونپڑے میں داخل ہوگیا۔ میں نے مدن کی طرف دیکھا،’’کہو اب کیا کہتے ہو؟‘‘
’’ذرا رکے رہو۔ وہ ابھی مہاجن کا لباس اتار کر اپنے اصلی روپ میں باہر نکلے گا۔ اتنی گرمی میں اس سے جھونپڑے کے اندر کہاں بیٹھا جائے گا۔‘‘
ہم نے کوئی پندرہ بیس منٹ انتظار کیا ہو گا کہ ٹاٹ کا پردہ پھر سرکا اور ایک نوجوان آدمی ململ کی دھوتی کرتا پہنے پٹیاں جمائے، سر پردو پلی ٹوپی ایک خاص انداز سے ٹیڑھی رکھے جھونپڑے سے باہر نکلا، بوڑھے مہاجن کی سفید مونچھیں غائب تھیں اور ان کی بجائے چھوٹی چھوٹی سیاہ آنکھیں اس کے چہرے پر زیب دے رہی تھیں۔
’’یہ وہی ہے‘‘۔ یک بارگی مدن چلا اٹھا، ’’وہی قد، وہی ڈیل ڈول۔‘‘
اور جب ہم اس کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے تو اس کی چال بھی ویسی ہی تھی جیسی مہاجن کا پیچھا کرنے میں ہم نے مشاہدہ کی تھی۔
وہ شخص کچھ دور فصیل کے ساتھ ساتھ چلتا رہا، پھر ایک گلی میں ہوتا ہوا دوبارہ شہر کے اندر پہنچ گیا۔ وہ بازار میں چلتے چلتے ایک پنواڑی کی دکان پر رک گیا۔ ہم سمجھے کہ شاید پان کھانے رکا ہے مگر ہم نے دیکھا کہ پنواڑی دکان سے اتر آیا اور بہروپیا اس کی جگہ گدی پر بیٹھ گیا۔
پنواڑی کے جانے کے بعد اس دکان پر کئی گاہک آئے جن کو اس نے سگریٹ کی ڈبیاں اور پان بنابنا کر دیے۔ وہ پان بڑی چابک دستی سے بناتا تھا جیسے یہ بھی کوئی فن ہو۔ اور ہم وہاں سے اپنے اپنے گھروں کو چلے آئے۔
اگلے روز اتوار کی چھٹی تھی۔ میں نے سوچا تھا کہ صبح آٹھ نو بجے تک سو کر کل کی تکان اتاروں گا مگر ابھی نور کا تڑکا ہی تھا کہ کسی نے میرا نام لے لے کر پکارنا اور دروازہ کھٹکھٹانا شروع کردیا۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ نیچے گلی میں جھانک کر دیکھا تو مدن تھا۔ میں پیچ و تاب کھاتا سیڑھیوں سے اترا۔
’’اسلم جلدی سے تیارہو جاؤ‘‘۔ اس نے مجھے دیکھتے ہی کہا۔
’’کیوں کیا بات ہے؟‘‘
’’جلدی کرو، کہیں بہروپیا صبح ہی صبح گھر سے نہ چل دے۔‘‘ اور اس نے مجھے ایسی التجا بھری نظروں سے دیکھا کہ میرا دل فوراً پسیج گیا۔
جب ہم کبھی دوڑتے، کبھی تیز تیز قدم اٹھاتے فصیل کی طرف جارہے تھے تو مدن نے مجھے بتایا کہ رات بھر وہ بہروپیے کو خواب میں طرح طرح کے روپ میں دیکھتا رہا۔ ابھی سورج نکلنے نہیں پایا تھا کہ ہم بہروپیے کے جھونپڑے کے پاس پہنچ گئے۔
دن کی روشنی میں ہمیں ان جھونپڑوں کے مکینوں کی غربت اور خستہ حالی کا بخوبی اندازہ ہو گیا۔ بہروپیے کے جھونپڑے پر ٹاٹ کا جو پردہ پڑا تھا اس میں کئی پیوند لگے تھے۔
ہم دو تین بار اس کے جھونپڑے کے سامنے سے گزرے۔ ہر بار ہمیں اندر سے بچوں کی آوازیں، دو ایک نسوانی آوازوں کے ساتھ ملی ہوئی سنائی دیں، آخر کوئی دس منٹ کے بعد ایک شخص بوسیدہ سا تہمد باندھے، بنیان پہنے، ایک ہاتھ میں گڑوی تھامے جھونپڑے سے برآمد ہوا۔ اس کی داڑھی مونچھ صاف تھی۔ سانولا رنگ، اس کو دیکھ کر اس کی عمر کا صحیح اندازہ کرنا مشکل تھا۔
وہ شخص آگے آگے اور ہم اس کے پیچھے پیچھے۔ آگے ایک باڑا آیا، وہ شخص اس باڑے کے اندر چلا گیا اور میں اور مدن باہر ہی اس کی نظروں سے اوجھل ایک طرف کھڑے اس کی حرکات و سکنات کو بخوبی دیکھ سکتے تھے۔
اس نے ایک بھینس کو پچکارا، پھر بھینس کو دوہنا شروع کیا۔ جب وہ ایک بھینس کو دوہ چکا تو دوسری کی طرف گیا۔ اس کام میں کوئی ایک گھنٹہ صرف ہوا۔ ایک بڈھے نے اس کی گڑوی کو دودھ سے بھر دیا جسے لے کر وہ باڑے سے نکل آیا۔
جب وہ ذرا دور چلا گیا تو میں نے کہا: ’’لو اب تو حقیقت کھل گئی تم پر۔ چلو اب گھر چلیں۔ ناحق تم نے میری نیند خراب کی۔‘‘
’’مگر بھیا وہ بہروپیا کہاں تھا۔ وہ تو گوالا تھا گوالا۔ آؤ تھوڑی دیر اور اس کا پیچھا کریں۔‘‘ میں نے مدن سے زیادہ حیل وحجت کرنا مناسب نہ سمجھا۔ جب ہمیں اس کے جھونپڑے کے آس پاس گھومتے آدھ گھنٹہ ہوگیا تو ہمیں ایک تانگہ تیزی سے ادھر آتا ہوا دکھائی دیا۔
یہ جھونپڑے کے قریب پہنچ کر رک گیا۔ اس کی آواز سنتے ہی ایک آدمی جھونپڑے سے نکلا، اس نے کوچوان کا سا خاکی لباس پہن رکھا تھا۔ اس کو دیکھ کر تانگے والا اتر پڑا اور یہ شخص تانگے میں آبیٹھا اور گھوڑے کو بڑی مہارت سے ہانکنے لگا۔ جیسے ہی تانگہ چلا پہلے شخص نے پکار کر کہا،’’تانگہ ٹھیک دو بجے اڈے پر لے آنا۔‘‘
دوسرے شخص نے گردن ہلائی۔ اس کے بعد وہ تانگہ نظروں سے اوجھل ہو گیا۔
آخر مدن نے سکوت کو توڑا،’’چلو یہ تو معلوم ہو ہی گیا کہ یہ شخص دو بجے تک کیا کرے گا۔ اتنی دیر تک ہمیں بھی چھٹی ہوگئی۔ اب ہمیں ڈھائی تین بجے تک یہاں پہنچ جانا چاہیے۔‘‘
میں نے کچھ جواب نہ دیا۔ سچ یہ ہے کہ میں اس کی اصلیت جاننے کے لیے اتنا ہی بیتاب ہو گیا تھا جتنا کہ مدن۔
ہم لوگ تین بجے سے پہلے ہی پھر بہروپیے کے جھونپڑے کے آس پاس گھومنے لگے۔ جھونپڑے کے اندر سے بچوں اور عورتوں کی آوازوں کے ساتھ ساتھ کبھی کبھی کسی مرد کی آواز بھی سنائی دے جاتی تھی۔ اس سے ہم نے اندازہ کر لیا کہ بہروپیا گھر واپس پہنچ گیا ہے۔
ہمیں زیادہ دیر انتظار نہ کرنا پڑا اور اب کے بہروپیا ایک اور ہی دھج سے باہر نکلا۔ اس نے سیاہ چغہ پہن رکھا تھا۔ سر پر کالی پگڑی جو بڑی خوش اسلوبی سے باندھی گئی تھی۔ گلے میں رنگ برنگی تسبیحیں، ترشی ہوئی سیاہ داڑھی، شانوں پر زلفیں بکھری ہوئی۔ اس نے بغل میں لکڑی کی ایک سیاہ صندوقچی داب رکھی تھی۔ معلوم ہوتا تھا کہ آج اس نے ایک صوفی درویش کا سوانگ بھرا ہے۔
ہم چپکے چپکے اس کے پیچھے پیچھے چلتے رہے، وہ شہر میں داخل ہوگیا۔ وہ کئی بازاروں سے گزرا۔ تھوڑی دیر میں ہم جامع مسجد کے پاس پہنچ گئے جس کے آس پاس ہر روز تیسرے پہر بازار لگا کرتا تھا۔ پھیری والے، بچوں کے سلے سلائے کپڑے، مٹھائیاں، چاٹ علاوہ ازیں تعویذ گنڈے والے، جڑی بوٹی والے بازار کی رونق بڑھاتے تھے۔
ہمارا بہروپیا بھی خاموشی سے ان لوگوں میں آکر شامل ہو گیا۔ اس نے اپنی سیاہ صندوقچی کھول کر بڑے گمبھیر لہجے میں صدا لگانی شروع کی:’’آپ کی آنکھوں میں دھند ہو، لالی ہو، خارش ہو، ککرے ہوں، بینائی کم زور ہو، پانی ڈھلکتا ہو، رات کو نظر نہ آتا ہو تو میرا بنایا ہوا خاص سرمہ ’’نین سکھ‘‘ استعمال کیجیے۔‘‘
’’اس کا نسخہ مجھے مکہ شریف میں ایک درویش بزرگ سے دست یاب ہوا تھا۔ خدمتِ خلق کے خیال سے قیمت بہت ہی کم رکھی گئی ہے۔ یعنی صرف چار آنے فی شیشی۔‘‘
میں اور مدن حیرت زدہ ہو کر بہروپیے کو دیکھنے لگے۔ ہمیں اپنی آنکھوں پر یقین نہ آتا تھا مگر اس نے سچ مچ سرمہ فروشی شروع کر دی تھی۔
دو تین آدمی اس کے پاس آکھڑے ہوئے اور اس سے باری باری آنکھوں میں سرمے کی سلائی لگوانے لگے۔
ہم جلد ہی وہاں سے رخصت ہوگئے۔ ہم نے بہروپیے کو اس کے اصل روپ میں دیکھنے کا خیال چھوڑ دیا۔
(مشہور ادیب اور افسانہ نگار غلام عباس کی ایک شان دار تخلیق)