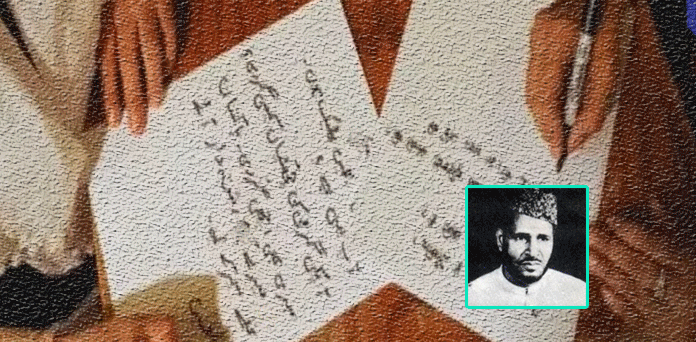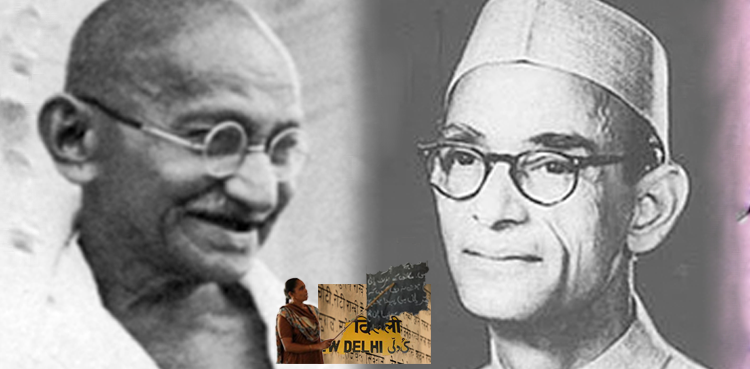مشہور شاعر داغ دہلوی نے کیا خوب کہا ہے ؎
اردو ہے جس کا نام ہمیں جانتے ہیں داغؔ
ہندوستاں میں دھوم ہماری زباں کی ہے
اردو ہمارے ملک کی مشترکہ وراثت کی امین ہے۔ یہ خالص ہندوستانی زبان ہے اور ہمارے مشترکہ کلچرکی نمائندگی کرتی ہے۔ اردو ترکی زبان میں فوج یا لشکر کو کہتے ہیں۔ دراصل اس زبان کی پیدائش اور پرورش فوجی چھاؤنی میں ہوئی جہاں ہر مذہب، ذات اور نسل کے فوجی ہوتے ہیں۔ ان فوجیوں کے آپسی میل جول اور مختلف زبانوں کے تال میل سے اردو زبان وجود میں آئی۔
ایک غلط فہمی ہمارے معاشرے (ہندوستان) میں عام ہو چکی ہے کہ اردو صرف مسلمانوں کی زبان ہے۔ اس غلط فہمی کی ایک وجہ اس زبان کا فارسی رسم الخط ہے اور دوسری وجہ یہ ہے کہ آج اردو لکھنے پڑھنے کا دستورعموماً مسلمانوں میں ہی پایا جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اردو میں ۶۰ فیصد سے زیادہ کھڑی بولی کے الفاظ ہیں جو اردو اور ہندی دونوں کی ماں ہے۔ اس زبان کو ابتدا میں ہندوستانی، ہندوی اور اردو کے نام سے موسوم کیا گیا۔ چودھویں صدی عیسوی میں جب ہندوستان پر مسلمانوں کی حکومت قائم ہوئی تو ان کے فوجی سپاہیوں کی زبان ترکی، عربی اور فارسی تھی۔ اس وقت ہندوستان میں سنسکرت، کھڑی بولی، برج بھاشا، مگہی اور ہریانوی زبانوں کا بول بالا تھا۔ مختلف تہذیبوں اور زبانوں کے باہمی میل جول سے ایک نئی تہذیب اور ایک نئی زبان وجود میں آئی جس میں مختلف تہذیبوں کی رنگا رنگی اور مختلف زبانوں کے الفاظ و استعارات نے جگہ پائی۔ مشہور تاریخ داں ڈاکٹر تارا چند لکھتے ہیں:
’’مسلم ذہن ہندوانہ رنگ و روپ قبول کرنے لگا اور اس نے فارسی و ترکی کی جگہ مقامی زبانوں کو سیکھنا اور استعمال کرنا شروع کیا۔ ہندوؤں نے عربی، فارسی اور ترکی الفاظ کو مقامی محاوروں میں جگہ دی۔ اس لین دین کا منافع ہماری تہذیب کے خزانے میں اردو کی شکل میں شامل ہوا۔‘‘
کرشن چندر نے اردو کی خصوصیت پر روشنی ڈالتے ہوئے لکھا ہے:
’’اردو ادب شروع ہی سے ایک مشترکہ ہند آریائی تہذیب اور کلچر کا گہوارہ رہا ہے۔ اس کی ترویج و اشاعت میں ہندوؤں اور مسلمانوں، سکھوں اور عیسائیوں نے مل جل کر حصہ لیا ہے۔اردو ایک ہندوستان گیر زبان ہے۔ اس نے اپنے دائرہ اثر میں ہر مذہب و ملت ، ہر رنگ و نسل کے افراد کے محسوسات اور جذبات کو سمو کر ایسا ادبی رنگ و روپ عطا کیا ہے جس سے اس زبان کے ادب اور شاعری پر باہمی میل جول، رواداری، محبت، اخوت اور قومی یکجہتی کے جذبوں کی گہری چھاپ پڑ چکی ہے۔ ان ہی عناصر کی موجودگی نے اردو زبان و ادب کو ایک سیکولر مزاج عطا کیا ہے جو سارے ہندوستانی عوام کے جمہوری جذبے سے ہم آہنگ ہے۔‘‘
انہی خیالات کو جگن ناتھ آزاد نے شعری پیکر میں یوں ڈھال کر پیش کیا ہے:
غلط ہے جو سمجھتا ہے اغیار کی بولی
یہ ہے اخلاص کی، طرزِ تکلم، پیار کی بولی
ریاضِ ہند میں اردو وہ اک خوش رنگ پودا ہے
جسے خون جگر سے ہندو مسلم نے سینچا ہے
برج لال رعنا نے اردو کے ہندوستانی نژاد ہونے کا یوں اعتراف کیا ہے:
نام اردو کبھی ہندی کبھی ہندوستانی
فارسی خالہ مری سنسکرت ہے نانی
بھارتی اپنا لباس اور سنگھار ایرانی
لے کے ہر پھول سے رس، کرتی ہوں گل افشانی
میرا ہر دیس سے پربندھ ہے، ہر قوم سے سمبندھ
میں کسی دین کی تابع، نہ دھرم کی پابند
اردو زبان کے اس سیکولر مزاج کے باوجود آج اردو زبان کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ اسے محض مسلمانوں کی زبان تعبیر کر لیا گیا ہے۔ زبان تہذیب اور کلچر کی پروردہ ہوتی ہے لیکن اسے مذہب سے جوڑکر دیکھا جانے لگا۔ زبان مذہبی لٹریچر کے مطالعے کا وسیلہ تو ہوسکتی ہے لیکن کوئی مذہب کسی زبان کو جنم نہیں دے سکتا۔ آج چونکہ اردو لکھنے پڑھنے والا طبقہ بیشتر مسلمانوں پر محیط ہے، اس لئے اگر ہم تسلیم کر بھی لیں کہ اردو مسلمانوں کی زبان ہے تو اردو زبان و ادب کی ترقی اور نشوونما میں کار ہائے نمایاں انجام دینے والے غیر مسلم ادیبوں، شاعروں اور دانشوروں کے ساتھ ہونے والی زیادتی کو ہم کیا نام دیں گے؟ کیا اردو زبان و ادب کی تاریخ سینکڑوں غیر مسلم شعرا و ادیب کے ذکر کے بغیر مکمل ہو سکتی ہے جنہوں نے نہایت پیارسے اردو کی زلفیں سنواری ہیں اور اس زبان کی آبیاری اور نشوونما میں اپنا خونِ جگر شامل کیا ہے۔
یہ درست ہے کہ اردو کے فروغ اور ارتقائی سفر میں ولی دکنی، میر امن، مرزا ہادی رسوا، داغ دہلوی، بہادر شاہ ظفر، حسرت موہانی، میر، غالب، ذوق، اقبال، فیض، ساحر وغیرہ کا اہم رول رہا ہے لیکن نہال چند لاہوری، درگا سہائے سرور، للو لال جی کوی، دیا شنکر نسیم، لبھو رام جوش ملیسانی، پنڈت بالمکند عرش ملیسانی، موہن دتاتریہ کیفی، برج نارائن چکبست، تلوک چند محروم وغیرہ بھی وہ شاعر اور ادیب ہیں جنہوں نے ابتدائی دور میں اردو کے خدوخال کو نمایاں کرنے میں اہم رول ادا کیا۔ یہ رام بابو سکسینہ تھے جنہوں نے پہلی بار اردو ادب کی تاریخ مرتب کی۔ منشی نول کشور کی خدمات سے صرف نظر ممکن ہی نہیں ہے، جنہوں نے ۱۸۵۸ء میں لکھنؤ میں نول کشور پرنٹنگ پریس اور بک ڈپو قائم کیا جس کے توسط سے سینکڑوں کتابیں اور رسالے محفوظ ہوئے۔ ان کی اس گراں بہا خدمت کے اعتراف میں حکومت ہند نے ۱۹۷۰ء میں ان پر ڈاک ٹکٹ جاری کیا۔ راجہ رام نارائن موزوں، مہاراجہ شتاب رائے، کلیان سنگھ عاشق کی سرپرستی اور مربیانہ سلوک کی وجہ سے اردو نے ترقی کی منزلیں طے کیں۔ ان لوگوں نے نہایت محبت اور شفقت کے ساتھ اردو کو پاؤں پاؤں چلنا سکھایا۔اردو ادب کی تاریخ منشی پریم چند کو کیسے فراموش کر سکتی ہے جنہوں نے اردو کا پہلا افسانہ ’سوز وطن‘ کے عنوان سے تحریر کیا۔ یہی نہیں بلکہ منشی پریم چند نے ہی اردو افسانے کو رومان کی وادی سے نکال کر حقیقت کی سنگلاخ زمینوں پر قدم جمانے کا ہنر عطا کیا۔ یہ پریم چند تھے جنہوں نے ہندوستان میں ترقی پسند تحریک کے شروع ہونے سے پہلے افسانہ ’کفن‘ لکھ کر اپنی دور اندیشی اور ترقی پسندی کا ثبوت دیا۔
سعادت حسن منٹو، عصمت چغتائی، احمد ندیم قاسمی، علی عباس حسینی کے ساتھ ساتھ راجندر سنگھ بیدی، اپندر ناتھ اشک، دیوندر ستیارتھی، بلونت سنگھ، ہنس راج رہبر، رامانند ساگر وغیرہ نے اردو افسانے کو فن کی بلندی تک پہنچانے میں اہم رول ادا کیا۔ اسی طرح شاعری کے میدان میں مجاز، فیض، جگر مراد آبادی، جوش، سردار جعفری، جذبی، کیفی اعظمی، اخترالایمان کے ساتھ رام پرساد بسمل، رگھوپتی سہائے فراق گورکھپوری کی غزلوں نے اردو عوام کے دلوں پر حکومت کی ہے۔ یہ دور اردو زبان و ادب کا سب سے سنہرا دور کہلاتا ہے جس میں اردو زبان اپنی پوری توانائی کے ساتھ جلوہ گر ہوئی اور ہر طرح کے موضوعات و مضامین اردو زبان کے وسیلے سے ادا ہونے لگے۔ اردو شاعر و ادیب کی اس نسل سے پیوستہ جو دوسری نسل اردو کی آبیاری کے لئے تیار ہوئی اس میں مسلم ادیب و شاعر کے شانہ بہ شانہ جگن ناتھ آزاد، کنہیا لال کپور، نریش کمار شاد، بششیر پردیپ، دیوندر اسر، برج پریمی، آنند نارائن ملا، حکم چند نیر، گیان چند جین، مالک رام، کمار پاشی، کشمیری لال ذاکر، کنور مہندر سنگھ سحر وغیرہ جیسے عاشقانِ اردو کا نام سنہری حرفوں سے لکھے جانے کے لائق ہے۔
اردو کو اپنے قلم کا وسیلہ بنانے والوں کی یہ طویل فہرست اس بات کی ضامن ہے کہ اردو زبان کسی خاص مذہب، فرقے یا علاقے کی زبان نہیں ہے بلکہ اس کی آبیاری اور نشوونما میں ہر مذہب و ملت اور خطے کے افراد نے بھرپور حصہ لیا ہے۔ اردو زبان اسی مشترکہ تہذیب کی نہ صرف نمائندہ ہے بلکہ اس تہذیب کے اظہار کا وسیلہ بھی ہے۔ لیکن آج اس تلخ حقیقت کو بھی ہم نظر انداز نہیں کر سکتے کہ اردو کے متوالوں کی تعداد پہلے کے تناسب میں کافی کم ہو چکی ہے۔ اردو کو اوڑھنا بچھونا بنانے والے شیدائی اب خال خال نظر آتے ہیں لیکن صورت حال مایوس کن بھی نہیں ہے۔
سلیقے سے ہواوؤں میں جو خوشبو گھول سکتے ہیں
ابھی کچھ لوگ باقی ہیں جو اردو بول سکتے ہیں
کالم نگار شکیل شمسی نے اردو کے ماضی اور موجودہ تشفی بخش صورت حال پر روشنی ڈالتے ہوئے لکھا ہے:
’’اگر ہم اردو کی تاریخ پر نظر ڈالیں تو کسی زمانے میں منشی نول کشور اس کے فروغ میں مصروف نظر آئیں گے، کہیں غالب کی تحریروں میں ہر گوپال تفتہ جا بجا مسکراتے ہوئے ملیں گے، کہیں پنڈت برج نارائن چکبست اور رتن ناتھ سرشاراردو کی راہوں میں پھول بچھاتے ہوئے نظر آرہے ہوں گے۔ شاید کوئی کہے کہ آزادی سے پہلے کی بات کرنے کا کیا فائدہ؟ مگر آزادی کے بعد بھی تو رگھوپتی سہائے فراق گورکھپوری، کنور مہندر سنگھ بیدی، جگن ناتھ آزاد، نریش کمار شاد، سمپورن سنگھ گلزار، کرشن بہاری نور، شین کاف نظام اور پنڈت گلزار زتشی جیسے نام بھی تو گلستان اردو کو سیراب کرتے رہے اور آج تو نہ جانے کتنے نوجوان لڑکے رنجیت چوہان کی شکل میں اردو کی خدمت کررہے ہیں تو ان کو کیا کہیں گے؟
دراصل اردو زبان میں محبت کی ایسی خوشبو بسی ہوئی ہے جو ہر کسی کے دل و دماغ کو معطر کر دیتی ہے۔ اس زبان کی جادوئی قوت نے سب کے دلوں کو مسخر کر رکھا ہے۔ اردو دراصل محبت اور آشتی کی زبان ہے۔ اس زبان میں دوسری زبانوں کے الفاظ کو اپنانے کی بڑی قوت ہے۔اس لئے اردو میں مختلف زبانوں کے الفاظ نے جگہ بنائی ہے۔ یہ ممکن ہے کہ تمام لوگ اس زبان کو لکھ یا پڑھ نہ سکیں لیکن ہندوستان کے بیشتر علاقوں میں اسے سمجھا اور بولا جاتا ہے۔ اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ اردو زبان کا اپنا کوئی مخصوص علاقہ نہیں ہے لیکن یہ سارے علاقے کی زبان ہے۔ اردو زبان کی شیرینی اور مٹھاس کے بغیر فلم، ڈرامے، غزلیں، گانے سب نامکمل ہیں۔ اردو زبان کی فصاحت اور شین قاف کی درستی کی وجہ سے گلوکاروں اور اداکاروں کے لئے اس زبان کو اپنانا لازمی ہوتا ہے۔ کسی شاعر نے بہترین اعتراف کیا ہے:
وہ کرے بات تو ہر لفظ سے خوشبو آئے
ایسی بولی وہی بولے جسے اردو آئے
(بھارتی ادیب اور مضمون نگار وصیہ عرفانہ کی ایک تحریر سے اقتباسات)