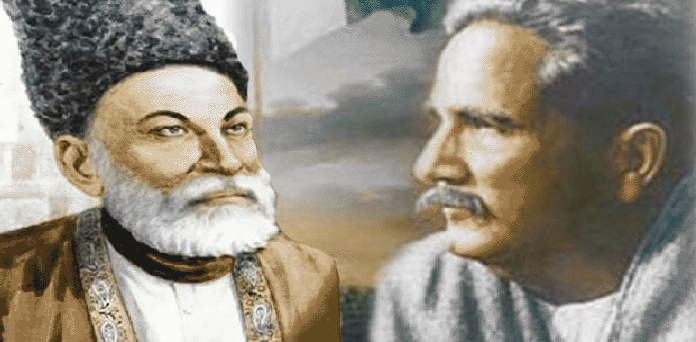انتظار حسین کے افسانے’’ شرمُ الحرم‘‘ کے مرکزی کردار کی نیند اُڑ گئی ہے۔ وہ آنکھیں بند کرتا ہے تو اسے یوں لگتا ہے جیسے وہ بیتُ المقدس میں ہے اور لڑ رہا ہے۔
انتظار حسین کا یہ کردار ہماری قوم کا ضمیر ہے۔ ہماری قوم جو گزشتہ نصف صدی سے بیتُ المقدس میں ہے اور لڑ رہی ہے، اقبال اس محاذ کے مجاہدِ اوّل تھے۔ وہ آزادیٔ فلسطین کے محاذ پر عربوں سے بھی پہلے پہنچے۔ اقبال نے اس جنگ کو اپنی قومی آزادی کی جنگ کا اٹوٹ سمجھا اور اس کی تہ در تہ معنویت کو آشکار کیا۔ ان کے نزدیک فلسطین کی آزادی اتنی اہمیت رکھتی تھی کہ دسمبر 1931ء میں وہ عالمِ اسلام کے نمائندوں کی کانفرنس میں شرکت کی خاطر لندن میں ہندی مسلمانوں کی آزادی کے مذاکرات کو ادھوڑا چھوڑ کر بیتُ المقدس جا پہنچے تھے۔
اقبالؔ نے اقوامِ مشرق کو اس جہانِ پیر کی موت کی بشارت ہی نہ دی تھی جسے فرنگ نے قمار خانہ بنا رکھا تھا بلکہ آزادی کی منزل سَر کرتے ہوئے مشرق کو مغرب کے نو آبادیاتی اور سامراجی عزائم سے خبردار بھی کیا تھا۔ اقبال کی زندگی کا نصف آخر مشرق اور بالخصوص اسلامی مشرق کو مغرب کی تہذیبی اور سیاسی استعمار سے نجات کی راہیں سمجھانے اور اپنی خودی کی پرورش کی ترغیب دینے میں صرف ہوا۔ اپنی زندگی کے آخری چند برسوں میں اقبال کو تقسیمِ فلسطین کے تصوّر نے مسلسل بے چین رکھا۔
اقبال نے اُس وقت سے ہی فکری اور عملی پیش بندیاں شروع کردی تھیں جب برطانوی سامراج ابھی مسئلہ فلسطین ایجاد کرنے میں کوشاں تھا۔ اس محاذ پر بھی اقبال نے اپنی سیاسی فکر اور اپنے فنی اعجاز ہر دو سے کام لیا مگر برطانیہ اور دنیائے عرب میں رائے عامّہ کی بیداری اور کل ہند مسلم لیگ کی عملی جدوجہد کے باوجود برطانوی سامراج اپنے ارادوں پر قائم رہا اور بالآخر فلسطین کی تقسیم کا فیصلہ نافذ ہو کے رہا۔ اقبال کے خیال میں یہ مسئلہ یہودیوں کے لیے وطن کی تلاش کی خاطر ایجاد نہیں کیا گیا بلکہ در حقیقت یہ مشرق کے دروازے پر مغربی سامراج کے فوجی اڈے کی تعمیر کا شاخسانہ ہے۔ وہ اسے عالمِ اسلام کے قلب میں ایک ناسور سے تعبیر کرتے ہیں:
رندانِ فرانسیس کا مے خانہ سلامت
پُر ہے مئے گلرنگ سے ہر شیشہ حلب کا
ہے خاکِ فلسطین پہ یہودی کا اگر حق
ہسپانیہ پر حق نہیں کیوں اہلِ عرب کا؟
مقصد ہے ملوکیتِ انگلیس کا کچھ اور
قصہ نہیں نارنج کا یا شہد و رَطَب کا!
رائل کمیشن کی رپورٹ میں تقسیمِ فلسطین کی تجویز نے اقبال کو اس قدر مضطرب کیا کہ رپورٹ کے شائع ہوتے ہی اقبال نے لاہور کے موچی دروازے میں ایک احتجاجی جلسۂ عام کا اہتمام کروایا۔ اس اجتماع میں اقبال کا جو بیان پڑھا گیا وہ سیاسی بصیرت اور پیش بینی کی بدولت دنیائے اسلام کی جدید سیاسی فکر میں ایک اہم سنگِ میل ہے۔ اس بیان میں اقبال نے مغربی سامراج کے مذموم عزائم کو بے نقاب کرنے کے ساتھ ساتھ دنیائے اسلام کو خود احتسابی کا درس بھی دیا ہے، وہ اس المیے کو دو بڑی عبرتوں کا آئینہ دار بتاتے ہیں۔ اوّل یہ کہ دنیائے اسلام کی سیاسی ہستی کی بقا کا راز عربوں اور ترکوں… عرب و عجم کے اتحاد میں مضمر ہے اور دوّم یہ کہ:
’’عربوں کو چاہیے کہ اپنے قومی مسائل پر غور و فکر کرتے ہوئے عرب ممالک کے بادشاہوں کے مشوروں پر اعتماد نہ کریں کیونکہ بہ حالاتِ موجودہ ان بادشاہوں کی حیثیت ہرگز اس قابل نہیں ہے کہ وہ محض اپنے ضمیر و ایمان کی روشنی میں فلسطین کے متعلق کسی فیصلے یا کسی صائب نتیجے پر پہنچ سکیں۔‘‘
اقبال کا یہ بیان تحریکِ آزادیٔ فلسطین کو عرب بادشاہوں کی مسندِ اقتدار سے متصادم دیکھتا ہے اور قرار دیتا ہے کہ مسئلہ فلسطین مسلمانوں کو موجودہ عالمی اداروں سے برگشتہ کر کے بالآخر اپنی علیحدہ جمعیتِ اقوام کے قیام کے امکانات پر غور کرنے پر مجبور کر دے گا:
تہران ہو اگر عالمِ مشرق کا جنیوا
شاید کرۂ اَرض کی تقدیر سنور جائے
اقبال نے عرب عوام کو عرب بادشاہوں سے بیزاری کا درس صرف اپنی سیاسی تحریروں میں ہی نہیں دیا بلکہ جمالِ فن سے بھی اس درس کو دل نشین بنایا ہے:
یہی شیخِ حرم ہے جو چرا کر بیچ کھاتا ہے
گلیمِ بو ذر و دلقِ اویس و چادرِ زہرا
پیرِ حرم تو حفظِ حرم کے تقاضوں کو پسِ پشت ڈال چکا ہے، اس لیے اب اقبال کی آخری امید عرب عوام ہیں جن سے اقبال یوں مخاطب ہیں:
زمانہ اب بھی نہیں جس کے سوز سے فارغ
میں جانتا ہوں وہ آتش ترے وجود میں ہے
تری دوا نہ جنیوا میں ہے نہ لندن میں
فرنگ کی رگِ جاں پنجۂ یہود میں ہے
سنا ہے میں نے غلامی سے اُمتوں کی نجات
خودی کی پرورش و لذّتِ نمود میں ہے
مگر اقبال کی آواز صدا بہ صحرا ثابت ہوئی اور ہماری طرح دنیائے عرب بھی اپنی خودی کی پرورش سے کہیں زیادہ غیر کے دست و بازو پر ناز کرتی رہی۔ نتیجہ یہ کہ فروری 1949ء کی پسپائی نے اسرائیل کو قدموں تلے روند ڈالنے اور صفحۂ ہستی سے مٹا کر دَم لینے کے نعروں کا طلسم توڑ کر رکھ دیا۔ اس شکست نے مصر میں شہنشاہیت کے خلاف فوجی انقلاب کو ممکن بنایا اور صدر ناصر کی زیرِ قیادت تمام عرب دنیا میں انقلاب کی صدائیں گونجنے لگیں۔ برطانیہ اور فرانس کی مشترکہ یلغار کے مقابلے میں مصر کی ثابت قدمی اور کامرانی نے غریب عوام کو وہ اعتمادِ ذات اور غرورِ نفس بخشا جو، ن م راشد کی نظم ’’دل مرے صحرا نوردِ پیر دل‘‘ میں جلوہ گر ہے۔ ریگِ صحرا میں تمناؤں کے بے پایاں الاؤ کے قریب بیٹھ کر راشد اپنے ہم نفسوں سے یوں مخاطب ہیں:
سالکو، فیروز بختو، آنے والے قافلو!
شہر سے لوٹو گے تم تو پاؤ گے
ریت کی سرحد پہ جو روحِ ابد خوابیدہ تھی
جاگ اٹھی ہے ’’شکوہ ہائے نے‘‘ سے وہ
ریت کی تہ میں جو شرمیلی سحر روئیدہ تھی
جاگ اٹھی ہے حرّیت کی لَے سے وہ
ریگ شب بیدار ہے، سنتی ہے ہر جابر کی چاپ
ریگِ شب بیدار ہے، نگراں ہے مانندِ نقیب
دیکھتی ہے سایۂ آمر کی چاپ!
ریگ ہر عیار غارت گر موت کی!
ریگ استبدار کے طغیاں کے شور و شر کی موت
ریگ جب اٹھتی ہے، اڑ جاتی ہے ہر فاتح کی نیند
ریگ کے نیزوں سے زخمی سب شہنشاہوں کے خواب
ریگ، اے صحرا کی ریگ
مجھ کو اپنے جاگتے ذروں کے خوابوں کی
نئی تعبیر دے
سوئز کے بحران کے گرد و پیش عرب بیداری کی بلند لہر سے وابستہ توقعات کے پس منظر میں جون 67ء کی جنگ میں عربوں کی آناً فاناً شکست نے ہمارے تخلیقی فن کار کی انا کو شدید چوٹ لگائی اور وہ منظور عارف کا ہم زباں ہو کر چیخ اٹھا:
میں نے دیکھا، نہیں محسوس کیا ہے
پھر بھی اک درد کی شدت ہے میرے سینے میں
شکل کیا دیکھوں کئی داغ ہیں آئینے میں (آئینے کے داغ)
اپنے داغ داغ چہرے اور اپنی زخم زخم ہستی کا اندمال اُسے اسلام کی انقلابی روح کی بازیافت میں نظر آیا اور یوں اس کی انسان دوستی کا رخ نمایاں طور پر اسلامی ہوگیا۔ اس کے ذہن کی گہرائیوں میں ہلچل مچانے والے سوال کو ابنِ انشاؔ نے یوں لب گویا عطا کیا:
’’آدھی دُنیا سوشلسٹ ہوچکی ہے اور باقی آدھی آزاد اور خود مختار…اور یہ سب مل کر اقوامِ متحدہ کے ایوانوں پر حاوی۔ لیکن ان کی مجموعی مادّی اور اخلاقی قوّت اسرائیل کی جارحیت کے معاملے میں صرف ایک بڑے اور امیر ملک کے ویٹو اور دھونس کی وجہ سے بیکار ہو کر رہ گئی ہے۔ بیروت کے تل زعتر کیمپ سے خاک و خون میں لتھڑے ہوئی عرب کی فغاں اٹھ رہی ہے اور کوئی سننے اور دست گیری کرنے والا نہیں۔‘‘
اس ظلم پر ضمیر عالم خاموش کیوں ہے؟ انسان دوستی اور امن پسندی کے علم بردار دانشور مسلمانوں کو انسان کیوں نہیں سمجھتے ہو؟ اور خود مسلمان ویت نامی حرّیت پسندوں کا طرزِ عمل کیوں نہیں اپناتے؟ بیچارگی، تنہائی اور بے عملی کے اس صحرا میں ہمارے ادب نے اسلامی تاریخ سے توانائی اخذ کرنے کی ٹھانی:
رن سے آتے تھے تو باطبلِ ظفر آتے تھے
ورنہ نیزوں پہ سجائے ہوئے سَر آتے تھے
اور….
ایک بار اور بھی بطحا سے فلسطین میں آ
راستہ دیکھتی ہے مسجدِ اقصی تیرا
(احمد ندیم قاسمی)
فیض احمد فیض صحرائے سینا میں گرم معرکۂ کار زار میں خدا کا جلوہ دیکھتے ہیں اور حرّیت پسندوں کی سرفروشی اور جاں سپاری کو قرآنی اور صوفیانہ استعاروں میں بیان کرتے ہیں:
پھر برق فروزاں ہے سرِ وادیٔ سینا
پھر رنگ پہ ہے شعلۂ رخسارِ حقیقت
پیغامِ اجل دعوتِ دیدارِ حقیقت
اے دیدۂ بینا
اب وقت ہے دیدار کا دم ہے کہ نہیں ہے
اب قاتلِ جاں چارہ گرِ کلفتِ غم ہے!
گلزارِ ارم پرتوِ صحرائے عدم ہے
پندارِ جنوں
حوصلہ راہِ عدم ہے کہ نہیں ہے!
پھر برق فروزاں ہے سرِ وادیٔ سینا، اے دیدۂ بینا
آزمائش و ابتلا کی اس گھڑی میں فیضؔ اہلِ ایمان کے پندارِ جنوں کو پکارتے ہیں:
پھر دل کو مصفا کرو، اس لوح پہ شاید
مابینِ من و تو نیا پیماں کوئی اترے
اب رسمِ ستم حکمتِ خاصانِ زمیں ہے
تائیدِ ستم مصلحتِ مفتیٔ دیں ہے
اب صدیوں کے اقرارِ اطاعت کو بدلنے
لازم ہے کہ انکار کا فرماں کوئی اترے
یہ رجائیت اُس رومانی انقلابیت سے پھوٹی ہے ، جس کی جڑیں حقیقت کی سرزمین میں زیادہ گہری نہیں ہیں اور جس پر مجھے فلسطینی شاعرہ فَدویٰ طوقان کی ڈائری کا ایک ورق یاد آتا ہے:
’’عرب رجعت پسندی روز بروز قوت پکڑ رہی ہے۔ اس کی وجہ وہ دولت ہے جو ریگ زاروں سے پھوٹ نکلی ہے … اور عرب ترقی پسندی ہنوزِ عالمِ طفلی میں ہے۔ اس کی عقل ابھی خام ہے لیکن اس کی زبان کافی دراز ہے۔‘‘
عرب ترقی پسندی کے باب میں ہماری رومانی تصوریت کو حقیقت آشنا کرنے کا فریضہ تنقید، تراجم اور سفر ناموں نے سر انجام دیا ہے۔ جدید عربی اور ہم عصر فلسطینی ادب کے تنقید و تجزیہ اور ترجمہ و تعارف کا کام محمد کاظم نے جس دقّتِ نظر اور جس جرأتِ فکر کے ساتھ سر انجام دیا ہے، وہ اپنی مثال آپ ہے۔ محمد کاظم کے زیرِ اثر ادیبوں کا ایک پورا گروہ فلسطینی ادب کے تراجم میں مصروف ہے اور احمد ندیم قاسمی، امجد اسلام امجد، محمود شام، منو بھائی، کشور ناہید اور اظہر سہیل وغیرہ کے تراجم نے اردو میں مزاحمتی ادب کا ایک نیا دبستان کھول دیا ہے۔ اس دبستان کی بدولت نغمۂ حرّیت کی لَے ہمارے دلوں کو گرما رہی ہے اور ہمارے ذہنوں کو فلسطینی طرزِ فکر و احساس سے آشنا کر رہی ہے۔ مستنصر حسین تارڑ کا سفر نامہ’’ خانہ بدوش‘‘ اور مظہر الاسلام کا افسانہ ’’ زمین کا اغوا‘‘ پڑھنے کے بعد ابن انشا کا یہ سوال اور زیادہ شدت کے ساتھ ذہن کو تہہ و بالا کرنے لگتا ہے:
اور….. اہل عرب
جن کے اجداد نے
شرق سے غرب تک
شہسواری بھی کی، تاجداری بھی کی
شہر و صحرا میں آواره و بے وطن ہیں
حیفہ و جافہ و ناصره کے مکیں
سالہا سال سے بے مکاں سَر فشاں
دشت بھی غیر کا، شہر بھی غیر کا
بحر بھی غیر کا
اے خداوندِ افلاکیاں خاکیاں
کیا عرب کو بھی آوارہ ہونا پڑے گا
یعنی صدیوں تلک
یوں ہی دیوارِ گریہ پہ رونا پڑے گا؟
(دیوارِ گریہ)
یہ تو ہے اس المیے کی انسانی سطح مگر اس بربادی کی ایک اس سے بھی برتر سطح ہے ۔ یہ سطح اس ظلم کی اسلامی معنویت سے عبارت ہے۔ اس معنویت کو انتظار حسین نے اپنی کہانیوں میں معجزۂ فن بنایا ہے۔
(اقتباسات: فلسطین… اُردو ادب میں، از پروفیسر فتح محمد ملک)