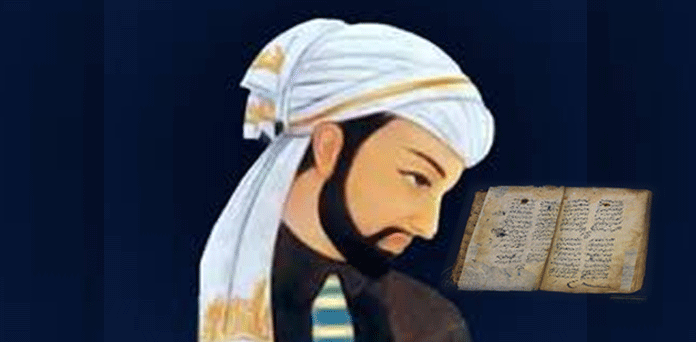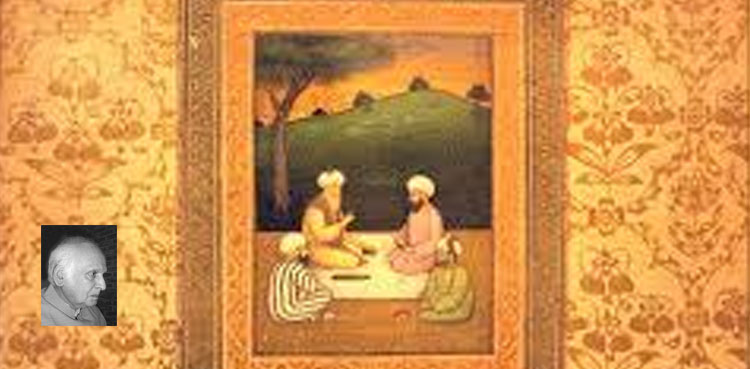حضرت امیر خسرو عمیق فکر کے مالک تھے۔ فارسی کے عظیم شاعر، موسیقار اور صوفی امیر خسرو نے ہندوستان میں اپنے علم و فن سے شہرت اور شخصیت و کردار سے ہر خاص و عام سے سندِ قبولیت پائی اور تاریخ میں نام رقم کیا۔ انھیں دقیق موضوعات میں غور و فکر کی عادت، فطری ذہانت اور نکتہ رسی کے سبب ہندوستان بھر میں ایک مدبر و مصلح سمجھا گیا۔ ان کی نصیحتیں سبھی کو بھائیں اور مشہور ہے کہ ان کے عہد میں لوگ اپنے مسائل کا حل طلب کرنے دور دور سے ان کے پاس چلے آتے تھے۔
خسرو نے اپنی بیٹی کو بھی منظوم نصیحتیں کی تھیں جن کے اردو تراجم ہمیں پڑھنے کو ملتے ہیں۔ یہ ایسا ہی ایک پارہ ہے جس میں اگرچہ نصیحتیں اس دور کے اعتبار سے ہیں، تاہم ان نصیحتوں کو آج کے زمانے سے منطبق کر کے دیکھیں تو یہ بہت مفید اور کارآمد ہیں۔
امیر خسرو ؔنے تیرہویں صدی میں جنم لیا۔ وہ ایسے شاعر تھے جس نے کبھی پہیلیوں اور کہہ مکرنیوں میں علم بانٹا تو کبھی شادی بیاہ کے گیتوں میں لوگوں کی تفریحِ طبع کا سامان کیا۔ وہ ایک شاعر اور ماہر موسیقی تھے۔ کہا جاتا ہے کہ خسرو نے متعدد ساز اور کئی راگ ایجاد کیے۔ امیر خسرو کو ایک صوفی کا درجہ بھی حاصل ہے جو حضرت خواجہ نظام الدّین اولیاء کے مریدِ خاص رہے۔
امیر خسرو کے مکتوب کا اردو ترجمہ ملاحظہ کیجیے۔
’’اے بیٹی تیرا وجود میرے دل کا چشم و چراغ ہے اور میرے دل کے باغ میں کوئی اور میوہ تجھ سے بہتر نہیں۔ اگرچہ تیرے بھائی بھی تیری طرح خوش بخت ہیں مگر جہاں تک میری نظر کا تعلق ہے وہ تجھ سے بہتر نہیں۔
باغبان جب باغ کی طرف نظر اٹھا کر دیکھتا ہے تو اس کے نزدیک سرو کی بھی وہی قدر ہوتی ہے جو سوسن کی ہوتی ہے۔ تیرا نصیب جس نے تجھے نیک فال بتایا، اسی نے تیرا نام مستورہ میمون (نیک بخت و عصمت مآب خاتون) رکھ دیا۔
اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اس نے تیرے اندازِ طبیعت کو پہلے سے دیکھا تو میری شرم و حیا اور پاک دامنی کو زیادہ سے زیادہ پایا۔ مجھے امید ہے کہ اس خوش بختی و نیک فالی کے باعث تیرے نام کو تیرے کردار سے چار چاند لگ جائیں گے۔ لیکن تجھے بھی کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے نیک انجام سے اپنے اس نام کی بنیاد کو صحیح ثابت کرے۔ عمر کے اعتبار سے تیرا یہ ساتواں سال ہے جب تو سترہ سال کی ہوجائے گی تو ان باتوں کو سمجھ سکے گی۔
جب تو اس عمر کو پہنچے گی تو میری ان نصیحتوں پر عمل کرکے اپنی نیک نامی سے مجھے بھی سر بلند کرے گی۔ اس طرح زندگی بسر کر کہ تیرے شان دار کارناموں سے تیرے قرابت داروں کا نام بھی روشن ہو۔
جس موتی کی طرف بزرگ توجہ مبذول کرتے ہیں، اس کے طفیل میں اس کے والدین یعنی سیپی کو بھی یاد کر لیتے ہیں۔ بہتر ہے کہ اپنی عصمت و عفت کی حفاظت کے لیے تو اپنی نقل و حرکت کو اپنے دامن کی حدود میں منحصر کر دے۔ تاکہ تیرا دامنِ شکوہ و وقار بھی جگہ سے اسی طرح نہ ہلے جس طرح دامنِ کوہ پتھر سے جدا نہیں ہوتا۔ اگر تیرا وقار ایک بھاری پتھر کی طرح تیرے دامن کا لنگر ہے تو یقیناً تیرا دامن تیری عصمت کا محافظ ہے۔
وہ عورت جس کا گھر سے نکلنا آسان ہو جاتا ہے وہ گھر کے اندر سب سے خوف زدہ رہتی ہے۔ جو عورت گلستان و لالہ زار میں ٹہلتی پھرتی ہے وہ اپنا گریبان گل کی نذر کر دیتی ہے اور دامن خار کو بخش دیتی ہے۔
جب اس کی نظر گلِ سرخ پر پڑتی ہے تو پھول کی ہنسی یہ تقاضا کرتی ہے کہ شراب پینی چاہیے۔ تُو اپنے چہرہ سے نمائشِ باطل کا غازہ دھو ڈال اور یہ کوشش کر کہ تو غازہ ہی کے بغیر سرخرو ہو جائے۔ تاکہ صدق و صواب کی شہرتِ عامّہ، تیری اس سرخروئی کی وجہ سے، تجھے حمیرا (حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے لقب کا مخفف) کا خطاب عطا کر دے۔
جو عورت راحت و آرام سے بے پروا رہی اس کا ویران گھر آباد ہو گیا۔ جو عورت لذتِ شراب کی رو میں بہہ کر پستی کے اندر چلی گئی، اس کا گھر خرابات بن گیا اور وہ خود بھی خراب ہوئی۔ جب اس کی شریف ذات شراب سے آلودہ ہو گئی تو در و دیوار سے دشمن اندر گھس آئے گا۔
اگر بند کمرے میں بھی شراب کا دور چلے تو اس کی بُو پڑوسیوں کو یہ پیغام پہنچا دیتی ہے کہ یہاں شراب پی جا رہی ہے۔ کسی عورت کا ایک چھوٹا سا آنچل جو وہ اپنی نشت گاہ میں بیٹھ کر بطور نقاب ڈال دیتی ہے ان فقیہوں کی پوری دو پگڑیوں سے بہتر ہے جو فسق و فجور میں مست ہیں۔
جلوہ گری یہ نہیں کہ ایک پری چہرہ حسینہ زن و شوہر کے تعلقات میں جلوہ گر ہو۔ جلوہ گری اس عورت کا حصہ ہے جو شرم و حیا اور خوف خدا کے باعث لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ ہونے کے باوجود اپنے اعلیٰ کردار کے لیے مشہور ہے۔
تُو سورج کی طرح اپنے آپ کو اجالوں میں چھپا لے اور شرم و حیا کو رخسار کا پردہ بنا۔ جس نے حیا کا نقاب اتار کر پھینک دیا اس سے کوئی امید نہ رکھو، کیونکہ اس کی عزت و آبرو پر پانی پھر گیا۔
جو مرد اس کی عریانی کے لیے کوشش کرتا ہے، وہ اس کو برہنہ کرنے کے بعد پھر اس کی پردہ پوشی کیا کرے گا؟ وہ آوارہ گرد جو بغیر کچھ کیے ہوئے ڈینگیں مارتا ہے، جب کوئی گناہ کر لے گا تو اسے کس طرح ظاہر نہ کرے گا۔
برے لوگوں کی یہ رسم ہے کہ جب کوئی برا کام کرتے ہیں تو اس کی شہرت کو اپنے لیے بڑائی سمجھتے ہیں۔ ہر بننے ٹھننے والی عورت جو نمائشِ حسن کے درپے ہوتی ہے، دس پردوں کے اندر بھی اپنی رسوائی کا سامان مہیا کر لیتی ہے۔
جب کوئی بری عورت تباہی کی طرف رخ ملتی ہے تو اس کی صورت اس کے فسق و فجور کی گواہی دینے لگتی ہے۔ عورت کے لیے فراخ حوصلگی و سخاوت زیب نہیں دیتی، البتہ اگر مرد میں یہ اوصاف نہ ہوں تو وہ عورت بن جاتا ہے۔
لیکن اتنی بد مزاج بھی نہ بن کہ تیری خادمائیں تجھ سے بھاگ کر باہر گلی میں چلی جائیں۔ ایسا گھر جس میں آرام و آسائش کم میسر ہو اگر اپنے ساز و سامان کے اعتبار سے بہشت بھی ہو تو جہنم کے مترادف ہو جاتا ہے۔
اس شوہر کو جس کی بیوی دراز ہو یہ سمجھنا چاہیے کہ ایک وحشی کتؑے کے ساتھ بند کر دیا گیا ہے۔ جو شوہر دولت و ثروت رکھتا ہے، اس کی بیوی خود گھر کے اندر سونے میں پیلی ہوتی ہے۔ لیکن جب کسی شوہر کے پاس پونجی نہ ہو تو اس کی بیوی کے لیے قناعت سے بہتر کوئی زیور نہیں ہے۔ نفس، جو انسان کے قالب میں سرایت کیے ہوئے ہے، انسان دشمن ہونے کے باوجود اس کے تن بدن میں موجود ہے۔ یہ نفس نہیں چاہتا کہ جس دل کو دنیا کا عیش حاصل ہے، وہ عقبیٰ کی فکر میں پڑ جائے اس لیے جہاں تک ہو سکے اس نفس کی رسی دراز نہ ہونے دے۔ یہ ساری مصیبت جو تن پر آتی ہے اس نظر کی بدولت آتی ہے جو توبہ کو توڑ کر گناہ پر مائل کرتی ہے۔
جس طرح موتی سیپ کے اندر چھپا ہوا ہوتا ہے اسی طرح اپنی آنکھ کو شرم و حیا میں چھپا لے تاکہ تو تیرِ بلا کا نشانہ نہ بنے۔ جب آنکھ مائل ہوتی ہے تو دل قابو سے باہر ہو جاتا ہے اور نظر کا ہاتھ دل کے ڈورے کھینچنے لگتا ہے۔
وہ عورت، جسے حق تعالیٰ نے خود داری کا جذبہ دیا ہے، جان دے دیتی ہے مگر تن کو فسق و فجور میں مبتلا نہیں ہونے دیتی۔
ایک بادشاہ اپنے اونچے محل کی چھت پر کھڑا ہوا، ادھر ادھر نظر ڈال رہا تھا۔ اس نے محل کے دیوار کے پیچھے ایک حسینہ کو دیکھا جو اپنے حسن سے اس زمانہ کے تمام حسینوں کو مات کرتی تھی۔ جیسے ہی بادشاہ نے اسے دیکھا، بے چین ہو گیا اور اس کے صبر و قرار کی بنیاد اپنی جگہ سے مل گئی۔ فوراً ایک پیغامبر کو اس کے پاس بھیجا تاکہ اسے بلا کر اس پر دست درازی کرے۔
اس حسینہ نے اپنی پاک دامنی کی بنا پر اپنے وقار کو عصمت کا پردہ بنا لیا اور چھپ گئی۔ پہلے تو ایک عرصہ تک در پردہ گفتگو ہوتی رہی مگر چاہنے والے کی مقصد براری نہ ہوئی۔
جب بادشاہ کا دل ہوس سے ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا تو اس نے کھل کر بات کی اور یہ خوف دلایا کہ میں جان سے مار ڈالوں گا۔ خادم کو حکم دیا کہ اسے اپنے گھر سے باہر گھسیٹ کر، بالوں سے کھینچتا ہوا، بادشاہ کی خواب گاہ میں لے آئے۔ (جب وہ حسینہ آئی تو) اس نے کہا کہ” اے فرمانروائے وقت، بادشاہوں کو فقیروں سے کیا واسطہ ہے۔ میرے جسم میں ایسی کون سی چیز ہے جو تیری آنکھوں کو بھا گئی ہے اور جسے تُو نے اپنے جذبۂ دل سے مجبور ہو کر عزیز بنا لیا ہے۔
بادشاہ نے اپنی آرزو مند آنکھوں میں آنسو بھر کر کہا۔” تیری دونوں آنکھوں نے مجھ سے میری نیند چھین لی ہے۔” وہ خوش جمال حسینہ اندر کی طرف ایک کونے میں چلی گئی اور انگلی سے اپنی دونوں آنکھیں باہر نکال لیں۔ اور خادم کو وہ دونوں آنکھیں دے کر کہا۔ "جا انہیں لے جا اور امیر سے کہہ دے کہ میری جو چیز تجھے عزیز تھی اسے تھام۔”
خادم نے جو یہ کیفیت بادشاہ پر ظاہر کی تو اس کے دل میں آگ لگ گئی اور اس کی سوزش سے دھواں بھر گیا۔ اپنے کرتوت پر شرمندہ ہو کر بیٹھ رہا اور اس حسینہ کا پاک دامن اپنے ہاتھ سے چھوڑ دیا۔
اے بیٹی تُو خسرو کی آنکھ کا نور ہے تو بھی اسی طرح اپنی عصمت پر صابر و مستقیم رہ۔‘‘
(امیر خسرو سے منسوب اس منظوم مکتوب کے مختلف اہلِ قلم نے تراجم کیے ہیں جن میں تفاوت ناگزیر ہے)