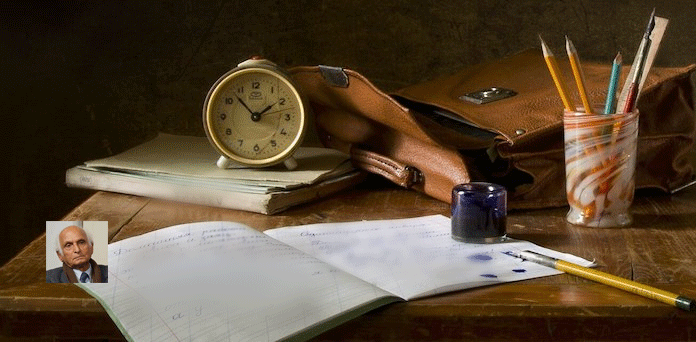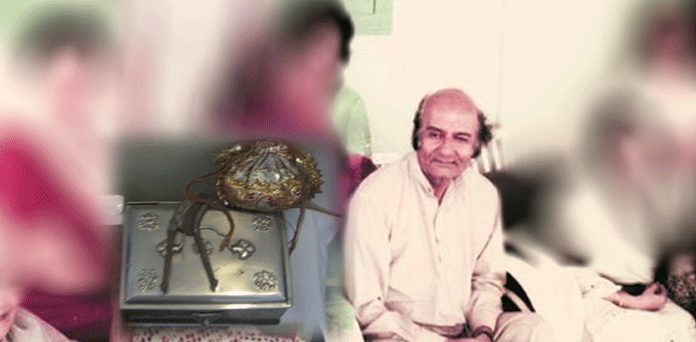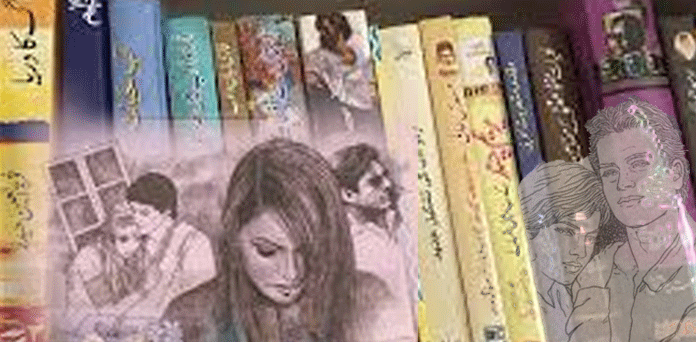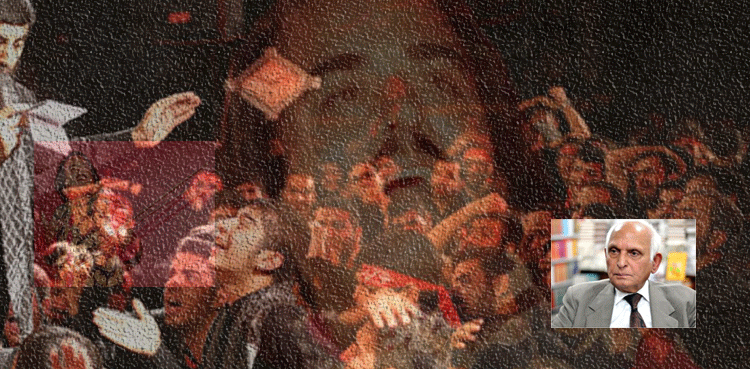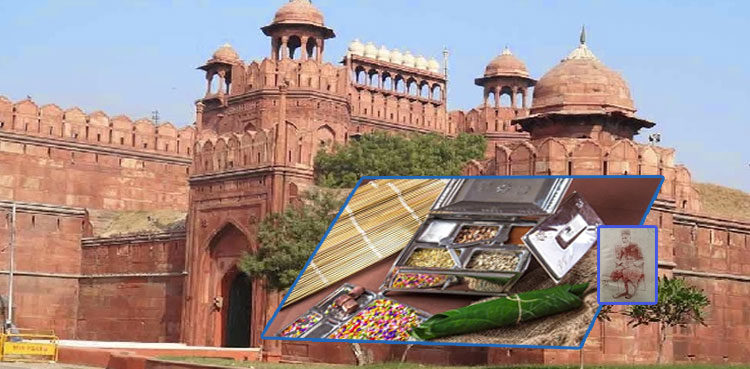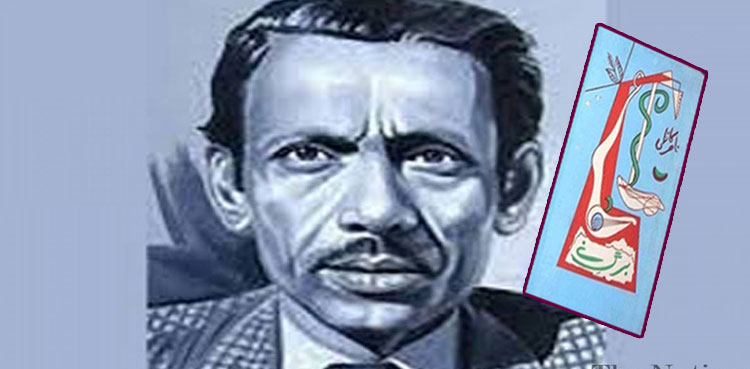یہ جاتک کتھا اور تاریخی واقعات پر مبنی افسانہ ہے۔ سمندر کے کنارے ایک بستی ہے، اس بستی کے لوگ مچھلی کا شکار کر اپنا گزر بسر کرتے ہیں۔ انھیں ایک خاص دن کو مچھلی پکڑنے سے منع کیا جاتا ہے، لیکن لوگ بات کو ان سنا کر کے مچھلی پکڑتے ہیں اور وہ بندر میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ بس ایک شخص بچتا ہے جو بندر نہ بننے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتا ہے۔
اردو کے ممتاز فکشن رائٹر اور منفرد حکایتی اسلوب کے حامل ادیب انتظار حسین نے یہ کہانی آخری آدمی کے عنوان سے تحریر کی تھی انتظار حسین وہ پہلے پاکستانی ادیب تھے جن کا نام مین بکر پرائز کے لیے شارٹ لسٹ کیا گیا۔ ان کی کہانی پڑھیے۔
الیاسف اس قریے میں آخری آدمی تھا۔ اس نے عہد کیا تھا کہ معبود کی سوگند میں آدمی کی جون میں پیدا ہوا ہوں اور میں آدمی ہی کی جون میں مروں گا۔ اور اس نے آدمی کی جون میں رہنے کی آخر دم تک کوشش کی۔
اور اس قریے سے تین دن پہلے بندر غائب ہو گئے تھے۔ لوگ پہلے حیران ہوئے اور پھر خوشی منائی کہ بندر جو فصلیں برباد اور باغ خراب کرتے تھے نابود ہو گئے۔ پر اس شخص نے جو انہیں سبت کے دن مچھلیوں کے شکار سے منع کیا کرتا تھا یہ کہا کہ بندر تو تمہارے درمیان موجود ہیں مگر یہ کہ تم دیکھتے نہیں۔ لوگوں نے اس کا برا مانا اور کہا کہ کیا تو ہم سے ٹھٹھا کرتا ہے اور اس نے کہا کہ بے شک ٹھٹھا تم نے خدا سے کیا کہ اس نے سبت کے دن مچھلیوں کے شکار سے منع کیا اور تم نے سبت کے دن مچھلیوں کا شکار کیا اور جان لو کہ وہ تم سے بڑا ٹھٹھا کرنے والا ہے۔
اس کے تیسرے دن یوں ہوا کہ الیعذر کی لونڈی گجر دم ، الیعذر کی خواب گاہ میں داخل ہوئی اور سہمی ہوئی الیعذر کی جورو کے پاس الٹے پاؤں آئی۔ پھر الیعذر کی جورو خواب گاہ تک گئی اور حیران و پریشان واپس آئی۔ پھر یہ خبر دور دور تک پھیل گئی اور دور دور سے لوگ الیعذر کے گھر آئے اور اس کی خواب گاہ تک جا کر ٹھٹھک ٹھٹھک گئے کہ الیعذر کی خواب گاہ میں الیعذر کی بجائے ایک بڑا بندر آرام کرتا تھا اور الیعذر نے پچھلے سبت کے دن سب سے زیادہ مچھلیاں پکڑی تھیں۔
پھر یوں ہوا کہ ایک نے دوسرے کو خبر دی کہ اے عزیز! الیعذر بندر بن گیا ہے۔ اس پر دوسرا زور سے ہنسا، تو نے مجھ سے ٹھٹھا کیا۔ اور وہ ہنستا چلا گیا، حتٰی کہ منہ اس کا سرخ پڑ گیا اور دانت نکل آئے اور چہرے کے خد و خال کھینچتے چلے گئے اور وہ بندر بن گیا۔ تب پہلا کمال حیران ہوا۔ منہ اس کا کھلا کا کھلا رہ گیا اور آنکھیں حیرت سے پھیلتی چلی گئیں اور پھر وہ بھی بندر بن گیا۔
اور الیاب، ابن زبلون کو دیکھ کر ڈرا اور یوں بولا کہ اے زبلون کے بیٹے تجھے کیا ہوا ہے کہ تیرا چہرا بگڑ گیا ہے۔ ابن زبلون نے اس بات کا برا مانا اور غصے سے دانت کچکچانے لگا۔ تب الیاب مزید ڈرا اور چلّا کر بولا کہ اے زبلون کے بیٹے! تیری ماں تیرے سوگ میں بیٹھے، ضرور تجھے کچھ ہو گیا ہے۔ اس پر ابن زبلون کا منہ غصے سے لال ہو گیا اور دانت بھینچ کر الیاب پر جھپٹا۔ تب الیاب پر خوف سے لرزہ طاری ہوا اور ابن زبلون کا چہرہ غصے سے اور الیاب کا چہرہ خوف سے بگڑتا چلا گیا۔ ابن زبلون غصے سے آپے سے باہر ہوا اور الیاب خوف سے اپنے آپ میں سکڑتا چلا گیا اور وہ دونوں کہ ایک مجسم غصہ اور ایک خوف کی پوٹ تھے آپس میں گتھ گئے۔ ان کے چہرے بگڑتے چلے گئے۔ پھر ان کے اعضا بگڑے۔ پھر ان کی آوازیں بگڑیں کہ الفاظ آپس میں مدغم ہوتے چلے گئے اور غیر ملفوظ آوازیں بن گئے۔ پھر وہ غیر ملفوظ آوازیں وحشیانہ چیخ بن گئیں اور پھر وہ بندر بن گئے۔
الیاسف نے کہ ان سب میں عقل مند تھا اور سب سے آخر تک آدمی بنا رہا۔ تشویش سے کہا کہ اے لوگو! ضرور ہمیں کچھ ہو گیا ہے۔ آؤ ہم اس شخص سے رجوع کریں جو ہمیں سبت کے دن مچھلیاں پکڑنے سے منع کرتا ہے۔ پھر الیاسف لوگوں کو ہمراہ لے کر اس شخص کے گھر گیا۔ اور حلقہ زن ہو کے دیر تک پکارا کیا۔ تب وہ وہاں سے مایوس پھرا اور بڑی آواز سے بولا کہ اے لوگو! وہ شخص جو ہمیں سبت کے دن مچھلیاں پکڑنے سے منع کیا کرتا تھا آج ہمیں چھوڑ کر چلا گیا ہے۔ اور اگر سوچو تو اس میں ہمارے لئے خرابی ہے۔ لوگوں نے یہ سنا اور دہل گئے۔ ایک بڑے خوف نے انہیں آ لیا۔
دہشت سے صورتیں ان کی چپٹی ہونے لگیں۔ اور خد و خال مسخ ہو تے چلے گئے۔ اور الیاسف نے گھوم کر دیکھا اور بندروں کے سوا کسی کونہ پایا۔
جاننا چاہیے کہ وہ بستی ایک بستی تھی۔ سمندر کے کنارے۔ اونچے برجوں اور بڑے دروازوں والی حویلیوں کی بستی، بازاروں میں کھوے سے کھوا چھلتا تھا۔ کٹورا بجتا تھا۔ پر دم کے دم میں بازار ویران اور اونچی ڈیوڑھیاں سونی ہو گئیں۔ اور اونچے برجوں میں عالی شان چھتوں پر بندر ہی بندر نظر آنے لگے اور الیاسف نے ہراس سے چاروں سمت نظر دوڑائی اور سوچا کہ میں اکیلا آدمی ہوں اور اس خیال سے وہ ایسا ڈرا کہ اس کا خون جمنے لگا۔ مگر اسے الیاب یاد آیا کہ خوف سے کس طرح اس کی صورت بگڑتی چلی گئی اور وہ بندر بن گیا۔ تب الیاسف نے اپنے خوف پر غلبہ پایا اور عزم باندھا کہ معبود کی سوگند میں آدمی کی جون میں پیدا ہوا ہوں اور آدمی ہی کی جون میں مروں گا اور اس نے ایک احساسِ برتری کے ساتھ اپنے مسخ صورت ہم جنسوں کو دیکھا اور کہا۔ تحقیق میں ان میں سے نہیں ہوں کہ وہ بندر ہیں اور میں آدمی کی جون میں پیدا ہوا۔ اور الیاسف نے اپنے ہم جنسوں سے نفرت کی۔ اس نے ان کی لال بھبوکا صورتوں اور بالوں سے ڈھکے ہوئے جسموں کو دیکھا اور نفرت سے چہرہ اس کا بگڑنے لگا مگر اسے اچانک زبان کا خیال آیا کہ نفرت کی شدت سے صورت اس کی مسخ ہو گئی تھی۔ اس نے کہا کہ الیاسف نفرت مت کر کہ نفرت سے آدمی کی کایا بدل جاتی ہے اور الیاسف نے نفرت سے کنارہ کیا۔
الیاسف نے نفرت سے کنارہ کیا اور کہا کہ بے شک میں انہی میں سے تھا اور اس نے وہ دن یاد کئے جب وہ ان میں سے تھا اور دل اس کا محبت کے جوش سے امنڈنے لگا۔ اسے بنت الاخضر کی یاد آئی کہ فرعون کے رتھ کی دودھیا گھوڑیوں میں سے ایک گھوڑی کی مانند تھی۔ اور اس کے بڑے گھر کے در سرو کے اور کڑیاں صنوبر کی تھیں۔ اس یاد کے ساتھ الیاسف کو بیتے دن یاد آ گئے کہ وہ سرو کے دروں اور صنوبر کی کڑیوں والے مکان میں عقب سے گیا تھا اور چھپر کھٹ کے لئے اسے ٹٹولا جس کے لئے اس کا جی چاہتا تھا اور اس نے دیکھا لمبے بال اس کی رات کی بوندوں سے بھیگے ہوئے ہیں اور چھاتیاں ہرن کے بچوں کے موافق تڑپتی ہیں۔ اور پیٹ اس کا گندم کی ڈیوڑھی کی مانند ہے اور پاس اس کے صندل کا گول پیالہ ہے اور الیاسف نے بنت الاخضر کو یاد کیا اور ہرن کے بچوں اور گندم کی ڈھیر اور صندل کے گول پیالے کے تصور میں سرو کے دروں اور صنوبر کی کڑیوں والے گھر تک گیا۔ ساس نے خالی مکان کو دیکھا اور چھپر کھٹ پر اسے ٹٹولا۔ جس کے لئے اس کا جی چاہتا تھا اور پکارا کہ اے بنت الاخضر! تو کہاں ہے اور اے وہ کہ جس کے لئے میرا جی چاہتا ہے۔ دیکھ موسم کا بھاری مہینہ گزر گیا اور پھولوں کی کیاریاں ہری بھری ہو گئیں اور قمریاں اونچی شاخوں پر پھڑپھڑاتی ہیں۔ تو کہاں ہے؟ اے اخضر کی بیٹی! اے اونچی چھت پر بچھے ہوئے چھپر کھٹ پر آرام کرنے والی، تجھے دشت میں دوڑتی ہوئی ہرنیوں اور چٹانوں کی دراڑوں میں چھپے ہوئے کبوتروں کی قسم تو نیچے اتر آ۔ اور مجھ سے آن مل کہ تیرے لئے میرا جی چاہتا ہے۔ الیاسف بار بار پکارتا کہ اس کا جی بھر آیا اور بنت الاخضر کو یاد کر کے رویا۔
الیاسف بنت الاخضر کو یاد کر کے رویا مگر اچانک الیعذر کی جورو یاد آئی جو الیعذر کو بندر کی جون میں دیکھ کر روئی تھی۔ حالانکہ اس کی ہڑکی بندھ گئی اور بہتے آنسوؤں میں اس کے جمیل نقوش بگڑتے چلے گئے۔ اور ہڑکی کی آواز وحشی ہوتی چلی گئی یہاں تک کہ اس کی جون بدل گئی۔ تب الیاسف نے خیال کیا۔ بنت الاخضر جن میں سے تھی ان میں مل گئی۔ اور بے شک جو جن میں سے ہے وہ ان کے ساتھ اٹھایا جائے گا اور الیاسف نے اپنے تئیں کہا کہ اے الیاسف ان سے محبت مت کر مبادا تو ان میں سے ہو جائے اور الیاسف نے محبت سے کنارہ کیا اور ہم جنسوں کو نا جنس جان کر ان سے بے تعلق ہو گیا اور الیاسف نے ہرن کے بچوں اور گندم کی ڈھیری اور صندل کے گول پیالے کو فراموش کر دیا۔
الیاسف نے محبت سے کنارہ کیا اور اپنے ہم جنسوں کی لال بھبوکا صورتوں اور کھڑ ی دم دیکھ کر ہنسا اور الیاسف کو الیعذر کی جورو یاد آئی کہ وہ اس قریے کی حسین عورتوں میں سے تھی۔ وہ تاڑ کے درخت کی مثال تھی اور چھاتیاں اس کی انگور کے خوشوں کی مانند تھیں۔ اور الیعذر نے اس سے کہا تھا کہ جان لے کہ میں انگور کے خوشے توڑوں گا اور انگور کے خوشوں والی تڑپ کر ساحل کی طرف نکل گئی۔
الیعذر اس کے پیچھے پیچھے گیا اور پھل توڑا اور تاڑ کے درخت کو اپنے گھر لے آیا اور اب وہ ایک اونچے کنگرے پر الیعذر کی جوئیں بن بن کر کھاتی تھی۔ الیعذر جھری جھری لے کر کھڑا ہو جاتا اور وہ دم کھڑی کر کے اپنے لجلجے پنجوں پر اٹھ بیٹھی۔ اس کے ہنسنے کی آواز اتنی اونچی ہوتی کہ اسے ساری بستی گونجتی معلوم ہوئی اور وہ اپنے اتنی زور سے ہنسنے پر حیران ہوا مگر اچانک اسے اس شخص کا خیال آیا جو ہنستے ہنستے بندر بن گیا تھا اور الیاسف نے اپنے تئیں کہا۔ اے الیاسف تو ان پر مت ہنس مبادا تو انہیں کی جنس بن جائے اور الیاسف نے ہنسی سے کنارہ کیا۔
الیاسف نے ہنسی سے کنارہ کیا۔ الیاسف محبت اور نفرت سے غصہ اور ہمدردی سے رونے اور ہنسنے سے ہر کیفیت سے گزر گیا اور ہم جنسوں کو نا جنس جان کر ان سے بے تعلق ہو گیا۔ ان کا درختوں پر اچکنا، دانت پیس پیس کر کلکاریاں کرنا، کچے کچے پھلوں پر لڑنا اور ایک دوسرے کو لہو لہان کر دینا۔ یہ سب کچھ اسے آگے کبھی ہم جنسوں پر رلاتا تھا، کبھی ہنساتا تھا۔ کبھی غصہ دلاتا کہ وہ ان پر دانت پیسنے لگا اور انہیں حقارت سے دیکھتا اور یوں ہوا کہ انہیں لڑتے دیکھ کر اس نے غصہ کیا اور بڑی آواز سے جھڑکا۔ پھر خود اپنی آواز پر حیران ہوا۔ اور کسی کسی بندر نے اسے بے تعلقی سے دیکھا اور پھر لڑائی میں جٹ گیا۔ اور الیاسف کے تئیں لفظوں کی قدر کی جاتی رہی۔ کہ وہ اس کے اور اس کے ہم جنسوں کے درمیان رشتہ نہیں رہے تھے اور اس کا اس نے افسوس کیا۔ الیاسف نے افسوس کیا اپنے ہم جنسوں پر، اپنے آپ پر اور لفظ پر۔ افسوس ہے ان پر بوجہ اس کے وہ اس لفظ سے محروم ہو گئے۔ افسوس ہے مجھ پر بوجہ اس کے لفظ میرے ہاتھوں میں خالی برتن کی مثال بن کر رہ گیا۔ اور سوچو تو آج بڑے افسوس کا دن ہے۔ آج لفظ مر گیا۔ اور الیاسف نے لفظ کی موت کا نوحہ کیا اور خاموش ہو گیا۔
الیاسف خاموش ہو گیا اور محبت اور نفرت سے، غصے اور ہمدردی سے، ہنسنے اور رونے سے در گزرا۔ اور الیاسف نے اپنے ہم جنسوں کو نا جنس جان کر ان سے کنارہ کیا اور اپنی ذات کے اندر پناہ لی۔ الیاسف اپنی ذات کے اندر پناہ گیر جزیرے کے مانند بن گیا۔ سب سے بے تعلق، گہرے پانیوں کے درمیان خشکی کا ننھا سا نشان اور جزیرے نے کہا میں گہرے پانیوں کے درمیان زمین کا نشان بلند رکھو ں گا۔
الیاسف اپنے تئیں آدمیت کا جزیرہ جانتا تھا۔ گہرے پانیوں کے خلاف مدافعت کرنے لگا۔ اس نے اپنے گرد پشتہ بنا لیا کہ محبت اور نفرت، غصہ اور ہمدردی، غم اور خوشی اس پر یلغار نہ کریں کہ جذبے کی کوئی رو اسے بہا کر نہ لے جائے اور الیاسف اپنے جذبات سے خوف کرنے لگا۔ پھر جب وہ پشتہ تیار کر چکا تو اسے یوں لگا کہ اس کے سینے کے اندر پتھری پڑ گئی ہے۔ اس نے فکر مند ہو کر کہا کہ اے معبود میں اندر سے بدل رہا ہوں تب اس نے اپنے باہر پر نظر کی اور اسے گمان ہونے لگا کہ وہ پتھری پھیل کر باہر آ رہی ہے کہ اس کے اعضاء خشک، اس کی جلد بد رنگ اور اس کا لہو بے رس ہوتا جا رہا ہے۔ پھر اس نے مزید اپنے آپ پر غور کیا اور اسے مزید وسوسوں نے گھیرا۔ اسے لگا کہ اس کا بدن بالوں سے ڈھکتا جا رہا ہے۔ اور بال بد رنگ اور سخت ہوتے جا رہے ہیں۔ تب اسے اپنے بدن سے خوف آیا اور اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ خوف سے وہ اپنے اندر سمٹنے لگا۔ اسے یوں معلوم ہوا کہ اس کی ٹانگیں اور بازو مختصر اور سر چھوٹا ہوتا جا رہا ہے تب اسے مزید خوف ہوا اور اعضاء اس کے خوف سے مزید سکڑنے لگے اور اس نے سوچا کہ کیا میں بالکل معدوم ہو جاؤں گا۔
اور الیاسف نے الیاب کو یاد کیا کہ خوف سے اپنے اندر سمٹ کر وہ بندر بن گیا تھا۔ تب اس نے کہا کہ میں اندر کے خوف پر اسی طور غلبہ پاؤں گا جس طور میں نے باہر کے خوف پر غلبہ پایا تھا اور الیاسف نے اندر کے خوف پر غلبہ پا لیا۔ اور اس کے سمٹتے ہوئے اعضاء دوبارہ کھلنے اور پھیلنے لگے۔ اس کے اعضاء ڈھیلے پڑ گئے۔ اور اس کی انگلیاں لمبی اور بال بڑے اور کھڑے ہونے لگے۔ اور اس کی ہتھیلیاں اور تلوے چپٹے اور لجلجے ہو گئے اور اس کے جوڑ کھلنے لگے اور الیاسف کو گمان ہوا کہ اس کے سارے اعضاء بکھر جائیں گے تب اس نے عزم کر کے اپنے دانتوں کو بھینچا اور مٹھیاں کس کر باندھا اور اپنے آپ کو اکٹھا کرنے لگا۔
الیاسف نے اپنے بد ہیئت اعضاء کی تاب نہ لا کر آنکھیں بند کر لیں اور جب الیاسف نے آنکھیں بند کیں تو اسے لگا کہ اس کے اعضاء کی صورت بدلتی جا رہی ہے۔
اس نے ڈرتے ڈرتے اپنے آپ سے پوچھا کہ میں، میں نہیں رہا۔ اس خیال سے دل اس کا ڈھینے لگا۔ اس نے بہت ڈرتے ڈرتے ایک آنکھ کھولی اور چپکے سے اپنے اعضاء پر نظر کی۔ اسے ڈھارس ہوئی کہ اس کے اعضاء تو جیسے تھے ویسے ہی ہیں۔ اس نے دلیری سے آنکھیں کھولیں اور اطمینان سے اپنے بدن کو دیکھا اور کہا کہ بے شک میں اپنی جون میں ہوں مگر اس کے بعد آپ ہی آپ اسے پھر وسوسہ ہوا کہ جیسے اس کے اعضاء بگڑتے جا رہے ہیں اور اس نے پھر آنکھیں بند کر لیں۔
الیاسف نے آنکھیں بند کر لیں اور جب الیاسف نے آنکھیں بند کیں تو اس کا دھیان اندر کی طرف گیا اور اس نے جانا کہ وہ کسی اندھیرے کنویں میں دھنستا جا رہا ہے اور الیاسف کنویں میں دھنستے ہوئے ہم جنسوں کی پرانی صورتوں نے اس کا تعاقب کیا۔ اور گزری راتیں محاصرہ کرنے لگیں۔ الیاسف کو سبت کے دن ہم جنسوں کا مچھلیوں کا شکار کرنا یاد آیا کہ ان کے ہاتھوں مچھلیوں سے بھر ا سمندر مچھلیوں سے خالی ہونے لگا۔ اور اس کی ہوس بڑھتی گئی اور انہوں نے سبت کے دن بھی مچھلیوں کا شکار شروع کر دیا۔ تب اس شخص نے جو انہیں سبت کے دن مچھلیوں کے شکار سے منع کرتا تھا کہا کہ رب کی سو گند جس نے سمندر کو گہرے پانیوں والا بنایا اور گہرے پانیوں کی مچھلیوں کا مامن ٹھہرایا، سمندر تمہارے دستِ ہوس سے پناہ مانگتا ہے اور سبت کے دن مچھلیوں پر ظلم کرنے سے باز رہو کہ مباد ا تم اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے قرار پاؤ۔ الیاسف نے کہا کہ معبود کی سوگند میں سبت کے دن مچھلیوں کا شکار نہیں کرو ں گا اور الیاسف عقل کا پتلا تھا۔ سمندر سے فاصلے پر ایک گڑھا کھودا اور نالی کھود کر اسے سمندر سے ملا دیا اور سبت کے دن مچھلیاں سطحِ آب پر آئیں تو تیرتی ہوئی نالی کی راہ گڑھے پر نکل گئیں۔ اور سبت کے دوسرے دن الیاسف نے اس گڑھے سے بہت سی مچھلیاں پکڑیں۔ وہ شخص جو سبت کے دن مچھلیاں پکڑنے سے منع کرتا تھا۔ یہ دیکھ کر بولا کہ تحقیق جس نے اللہ سے مکر کیا اللہ اس سے مکر کرے گا۔ اور بے شک اللہ زیادہ بڑا مکر کرنے والا ہے اور الیاسف یہ یاد کر کے پچھتایا اور وسوسہ کیا کہ کیا وہ مکر میں گھر گیا ہے۔ اس گھڑی اسے اپنی پوری ہستی ایک مکر نظر آئی۔ تب وہ اللہ کی بارگاہ میں گڑگڑایا کہ پیدا کرنے والے نے تو مجھے ایسا پیدا کیا جیسے پیدا کرنے کا حق ہے۔ تو نے مجھے بہترین کینڈے پر خلق کیا۔ اور اپنی مثال پر بنایا۔ پس اے پیدا کرنے والے تو اب مجھ سے مکر کرے گا اور مجھے ذلیل بندر کے اسلوب پر ڈھالے گا اور الیاسف اپنے حال پر رویا۔ اس کے بنائے ہوئے پشتہ میں دراڑ پڑ گئی تھی اور سمندر کا پانی جزیرے میں آ رہا تھا۔
الیاسف اپنے حال پر رویا اور بندروں سے بھری بستی سے منہ موڑ کر جنگل کی سمت نکل گیا کہ اب بستی اسے جنگل سے زیادہ وحشت بھری نظر آتی تھی۔ اور دیواروں اور چھتوں والا گھر اس کے لئے لفظ کی طرح معنی کھو بیٹھا تھا۔ رات اس نے درخت کی ٹہنیوں پر چھپ کر بسر کی۔
جب صبح کو وہ جاگا تو اس کا سارا بدن دکھتا تھا اور ریڑھ کی ہڈی درد کرتی تھی۔ اس نے اپنے بگڑے اعضاء پر نظر کی کہ اس وقت کچھ زیادہ بگڑے بگڑے نظر آ رہے تھے۔ اس نے ڈرتے ڈرتے سوچا کیا میں، میں ہی ہوں اور اس آن اسے خیال آیا کہ کاش بستی میں کوئی ایک انسان ہوتا کہ اسے بتا سکتا کہ وہ کس جون میں ہے اور یہ خیال آنے پر اس نے اپنے تئیں سوال کیا کہ کیا آدمی بنے رہنے کے لئے یہ لازم ہے کہ وہ آدمیوں کے درمیان ہو۔ پھر اس نے خود ہی جواب دیا کہ بیشک آدم اپنے تئیں ادھورا ہے کہ آدمی، آدمی کے ساتھ بندھا ہوا ہے۔ اور جو جن میں سے ہے ان کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اور جب اس نے یہ سوچا تو روح اس کی اندوہ سے بھر گئی اور وہ پکارا کہ اسے بنت الاخضر تو کہا ں ہے کہ تجھ بن میں ادھورا ہوں۔ اس آن الیاسف کو ہرن کے تڑپتے ہوئے بچوں اور گندم کی ڈھیری اور صندل کے گول پیالے کی یاد بے طرح آئی۔
جزیرے میں سمندر کا پانی امنڈا چلا آ رہا تھا اور الیاسف نے درد سے صدا کی۔ کہ اے بنت الاخضر اے وہ جس کے لئے میرا جی چاہتا ہے۔ تجھے میں اونچی چھت پر بچھے ہوئے چھپر کھٹ پر اور بڑے درختوں کی گھنی شاخوں میں اور بلند برجیوں میں ڈھونڈوں گا۔ تجھے سرپٹ دوڑی دودھیا گھوڑیوں کی قسم ہے۔ قسم ہے کبوتروں کی جب وہ بلندیوں پر پرواز کرے۔ قسم ہے تجھے رات کی جب وہ بھیگ جائے۔ قسم ہے تجھے رات کے اندھیرے کی جب وہ بدن میں اترنے لگے۔ قسم ہے تجھے اندھیرے اور نیند کی۔ اور پلکوں کی جب وہ نیند سے بوجھل ہو جائیں۔ تو مجھے آن مل کہ تیرے لئے میراجی چاہتا ہے اور جب اس نے یہ صدا کی تو بہت سے لفظ آپس میں گڈ مڈ ہو گئے جیسے زنجیر الجھ گئی ہو۔ جیسے لفظ مٹ رہے ہوں۔ جیسے اس کی آواز بدلتی جا رہی ہو اور الیاسف نے اپنی بدلتی ہوئی آواز پر غور کیا اور زبلون اور الیاب کو یاد کیا کہ کیوں کر ان کی آوازیں بگڑتی چلی گئی تھیں۔ الیاسف اپنی بدلتی ہوئی آواز کا تصور کر کے ڈرا اور سوچا کہ اے معبود کیا میں بدل گیا ہوں اور اس وقت اسے یہ نرالا خیال سوجھا کہ اے کاش کوئی ایسی چیز ہوتی کہ اس کے ذریعے وہ اپنا چہرہ دیکھ سکتا۔ مگر یہ خیال اسے بہت انہونا نظر آیا۔ اور اس نے درد سے کہا کہ اے معبود میں کیسے جانوں کہ میں نہیں بد لاہوں۔
الیاسف نے پہلے بستی کو جانے کا خیال کیا مگر خود ہی اس خیال سے خائف ہوگیا، اور الیاسف کو خالی بستی اور اونچے گھروں سے خفقان ہونے لگا، اور جنگل کے اونچے درخت رہ رہ کر اسے اپنی طرف کھینچتے تھے، الیاسف بستی واپس جانے کے خیال سے خائف چلتے چلتے جنگل میں دور نکل گیا۔ بہت دور جاکر اسے ایک جھیل نظر آئی کہ پانی اس کا ٹھہرا ہوا تھا۔ جھیل کے کنارے بیٹھ کر اس نے پانی پیا، جی ٹھنڈا کیا۔ اسی اثنا میں وہ موتی ایسے پانی کو تکتے تکتے چونکا۔ یہ میں ہوں؟ اسے پانی میں اپنی صورت دکھائی دے رہی تھی۔ اس کی چیخ نکل گئی اور الیاسف کو الیاسف کی چیخ نے آلیا۔ اور وہ بھاگ کھڑا ہوا۔
الیاسف کو الیاسف کی چیخ نے آلیا تھا۔ اور وہ بے تحاشا بھاگا چلا جاتا تھا۔وہ یوں بھاگا جاتا تھا جیسے جھیل اس کا تعاقب کررہی ہے۔ بھاگتے بھاگتے تلوے اس کے دکھنے لگے اور چپٹے ہونے لگے اور کمر اس کی درد کرنے لگی، پر وہ بھاگتا رہا اور کمر کا درد بڑھتا گیا اور اسے یوں معلوم ہوا کہ اس کی ریڑھ کی ہڈی دوہری ہوا چاہتی ہے اور دفعتا جھکا بے ساختہ اپنی ہتھیلیاں زمین پر ٹکا دیں۔
الیاسف نے جھک کر ہتھیلیاں زمین پر ٹکا دیں اور بنت الاخضر کو سوگھتا ہوا چاروں ہاتھوں پیروں کے بل تیر کے موافق چلا۔