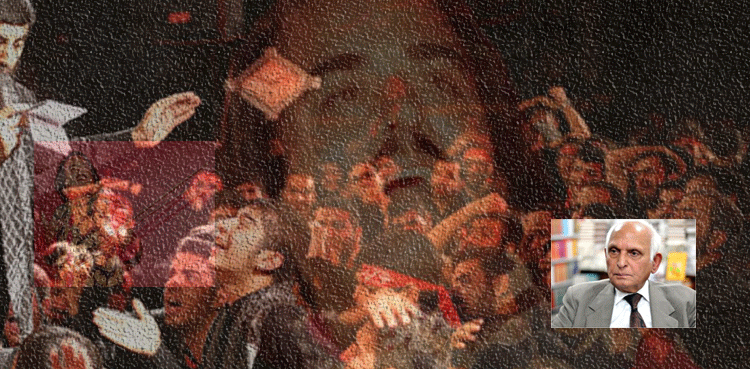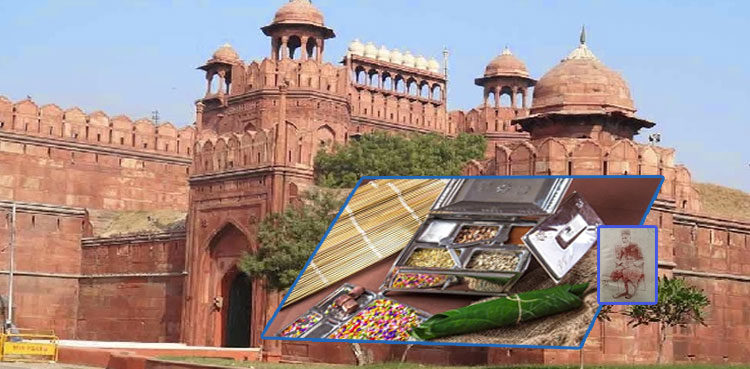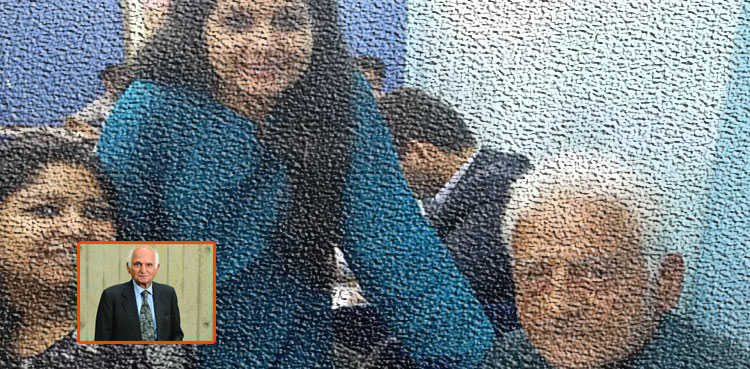’’پتہ نہیں یہ خواجہ معین الدین کے ڈرامہ ”لال قلعہ سے لالو کھیت تک“ کی برکت تھی یا اس علاقہ میں بسنے والے مہاجروں کا کمال تھا۔ بہرحال لالو کھیت نے پاکستان کے ابتدائی برسوں میں بہت شہرت کمائی۔
خیر، لاہور میں ہمارا اپنا ایک لالو کھیت تھا۔ لالو کھیت تو لالو کھیت نہیں رہا، لیاقت آباد بن گیا۔ مگر کرشن نگر بدستور کرشن نگر چلا آتا ہے۔ اسے اسلام پورہ بنانے کی کوششیں ابھی تک تو بار آور ہوئی نہیں ہیں۔ میں نے پاکستان میں قدم رکھنے کے بعد یہیں آنکھ کھولی تھی۔
خوب جگہ تھی۔ اجڑی اجڑی اور ساتھ ہی میں اتنی آباد کہ بازار سے گزرتے ہوئے کھوے سے کھوا چھلتا تھا۔ یہ سب کھوے پناہ گیروں کے تھے جو رفتہ رفتہ پناہ گیر سے مہاجر بن گئے۔ انہیں پناہ گیروں میں وہ ایک بڑھیا بھی تھی جس کے منہ سے نکلا ہوا معصوم سا فقرہ عسکری صاحب نے لپک لیا اور اس میں سے پاکستان کا فلسفہ کشید کر لیا۔ وہ ہمارے آگے آگے پناہ گیروں کی ایک ٹولی میں گھری چل رہی تھی اور اپنی رو میں بول رہی تھی۔ کہنے لگی اے بھیا ملک ولک کیا ہے۔ بس بچارے مسلمانوں نے لشٹم پشٹم ایک کچا گھر کھڑا کر لیا ہے۔ چلو سر چھپانے کو ایک کونا تو مل گیا۔
اسی بازار کے ایک نکڑ پہ ایک دکان کے تھڑے پہ ایک میر صاحب بیٹھے تھے۔ پورا نام تھا میر عترت حسین۔ مظفر نگر سے لٹ پٹ کر آئے تھے۔ مگر اس تھڑے پہ آ کر ایسے بیٹھے تھے جیسے پشتوں سے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ پان سگریٹ کی اس دکان پر گاہک تو کم ہی دکھائی دیتے تھے۔ شعر و شاعری کا چسکا رکھنے والوں اور گپ ہانکنے والوں کی پھڑ جمی رہتی تھی۔ جب بے فکروں کا ہجوم زیادہ ہوا تو میر صاحب نے ایک اعلان نامہ لکھ کر دکان پر آویزاں کر دیا۔ اس میں کہا گیا تھا کہ ہمارے حلقۂ خاص میں داخل ہونے کی شرائط مندرجہ ذیل ہیں۔ آدمی گریجویٹ ہو، خوش شکل ہو، مذاقِ سخن رکھتا ہو، زبان صحیح بولتا ہو۔
اس حلقۂ خاص کے رکن رکین ڈاکٹر صفدر حسین تھے کہ وہ بھی مظفر نگر ہی سے تعلق رکھتے تھے اور اس دکان سے چند قدم کے فاصلہ پر ایک مکان میں آکر بسے تھے۔ دوسرا رکن جو مجھے یاد آ رہا ہے وہ سانولی رنگت والا گورنمنٹ کالج کا ایک ایم اے کا طالب علم تھا۔ نام تھا سلیم گیلانی جو شاعری سے زیادہ موسیقی کا دلدادہ تھا۔ آگے چل کر ریڈیو پاکستان کے واسطے سے ترقی کی منزلیں طے کیں۔
تو کرشن نگر کا بازار تو بہت آباد تھا۔ مگر گلیاں اجڑی اجڑی نظر آتی تھیں۔ کتنے گھر ابھی تک بے آباد تھے۔ مکان بہت اچھے بنے ہوئے، دو دو منزلہ، سہ سہ منزلہ۔ باہر تالے پڑے ہوئے۔ اندر فرنیچر سے آراستہ۔ نقشہ بتا رہا تھا کہ یہاں کوئی فساد نہیں ہوا۔ بس ان مکانوں کے مکین اچانک یہاں سے رخصت ہوئے ہیں اور اس طرح رخصت ہوئے ہیں کہ اوپر کی منزلوں کی جو کھڑکیاں کھلی تھیں وہ کھلی ہی رہ گئیں۔ دن میں ان مکانوں پر اداسی برستی۔ رات کے اندھیرے میں وہ بھوت بن جاتے تھے۔ اور جب تیز ہوا چلتی تو کھڑکیوں کے پٹ دھاڑ دھاڑ بولتے تھے۔
جو مکان آباد ہو گئے تھے وہ مکان اپنے مکینوں کے ساتھ گھلے ملے نظر نہیں آتے تھے۔ مکانوں کی اپنی شان، مکینوں کا اپنا رنگ۔ ایک ڈرائنگ روم کا نقشہ اب یہ تھا کہ اندر فرنیچر ایک کونے میں سمیٹ دیا گیا تھا۔ باقی جگہ میں بھوسہ بکھرا ہوا تھا۔ آگے برآمدے میں بھینس بندھی ہوئی تھی۔
میرا عسکری صاحب کے ساتھ بسیرا تھا۔ اور عسکری صاحب نے اپنے ایک پھپھیرے ممیرے یا خلیرے بھائی کے گھر میں چھاؤنی چھائی تھی۔ یہ گھر بس واجبی واجبی تھا۔ میں نے عسکری صاحب سے کہا کہ عسکری صاحب کرشن نگر میں یار تو بڑے اچھے اچھے آراستہ و پیراستہ مکانوں میں آ کر براجمان ہوئے ہیں۔ آپ کے بھائی نے یہ کیسا مکان الاٹ کرایا تھا۔ فرنیچر کے نام یہاں تو ایک کرسی بھی نظر نہیں آ رہی۔
کہنے لگے کہ اس مکان میں ایک ہی چیز ملی تھی وہ بھی مالک مکان آ کر لے گیا۔ میں نے پوچھا”وہ کیا چیز تھی۔“
بولے ”تمہارے آنے سے کوئی دو تین دن پہلے ایک سکھ فوجی جیپ پر سوار پاکستانی پہرے میں یہاں آیا۔ کہا کہ ”یہ ہمارا مکان تھا۔ باقی سامان تو ہم نے سنگھوا لیا تھا۔ مگر یہاں ہماری مرغیوں کا ٹاپا رہ گیا ہے۔“
”مرغیوں کا ٹاپا۔“ میں نے حیران ہو کر پوچھا:
بولا ”بات یہ ہے جی کہ ٹاپا نہ ہونے سے مرغیوں کے سلسلہ میں ہمیں بڑی پریشانی ہو رہی ہے۔ مہربانی کر کے ہمارا ٹاپا دے دیجیے۔“
سکھ فوجی نے ٹاپا جیپ پہ رکھا اور پاکستانی سپاہیوں کے پہرے میں بحفاظت تمام…. یہاں سے لے گیا۔‘‘
(ممتاز ادیب اور فکشن نگار انتظار حسین کی کتاب چراغوں کا دھواں سے ایک پارہ)