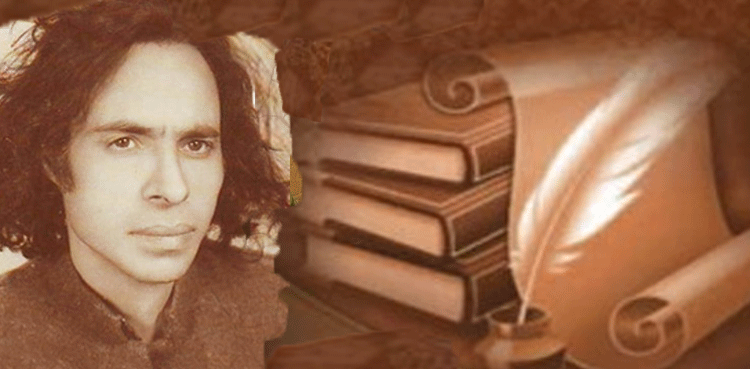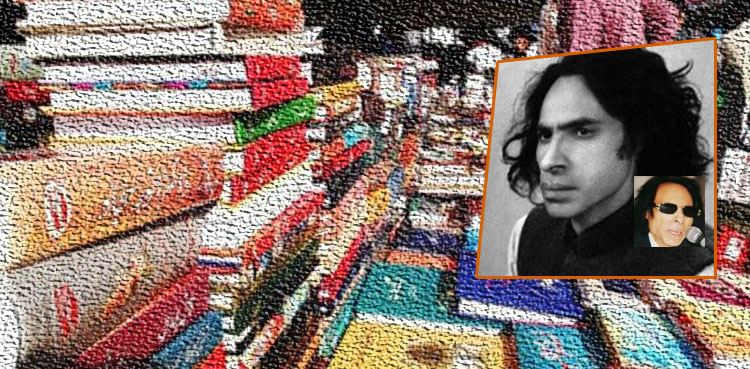بستیاں سوالوں کے انبوہ میں گھری ہوئی ہیں۔ ساتھ ہی وہ مسئلے ہیں جن سے ساری دنیا دوچار ہے۔ ہر مسئلہ اپنے سے بڑے مسئلے کا حل چاہتا ہے اور یہ دائرہ پھیلتا ہی چلا جاتا ہے۔ اگر ہماری آںکھوں پر پٹی بندھی ہوئی، زبان گل نہیں گئی ہے اور عقل کو جنون نہیں ہو گیا ہے تو بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم زندگی کی ان تیز و تند حقیقتوں سے بھاگ کر اپنے اندر پناہ لینا چاہیں؟
مشاہیرِ ادب کی تحریریں پڑھنے کے لیے لنک کھولیں
مسئلوں کے اس ہجوم میں انسانیت کے کھوے چھل گئے ہیں۔ تم ذرا دیکھو تو انسانیت کی جواں ہمتی پر کس قدر بوجھ ڈال دیا ہے، پَر انسانیت کا یہ قافلہ افتاں و خیزاں برابر آگے بڑھ رہا ہے جانتے نہ جانتے اور سب کچھ جان کر انجان بننے کے درمیاں ایک جنگ ہے جو صدیوں سے جاری ہے۔ آج بھی سچائی کو جھٹلایا جاتا ہے پر ایسا ہے کہ لہجے کی کھوٹ اور کپٹ اب چھپائے نہیں چھپتی۔ انسان کی تمام بد بختیوں نے نادانی اور ناحق کوشی کی کوکھ سے جنم لیا ہے۔ جھگڑا بس یہ ہے بعض مسخرے اس کرۂ ارض پر سر کے بل چلنا چاہتے ہیں۔ ہم نے انھیں ٹوکا اور برابر ٹوکتے رہیں گے۔ یہ ملکوں اور قوموں کا جھگڑا نہیں ہے قدروں کا جھگڑا ہے۔
انسانیت ایک خاندان ہے، نہ اس میں کوئی امتیاز ہے اور نہ تفریق۔ جو تفریق پیدا کرتے ہیں وہ اس مقدس خاندان میں شامل نہیں۔ لکھنے والوں اور بولنے والوں کا جتنا بھی مقدور ہو اس کے مطابق عالمگیر سماج کے قیام کی کوشش کرنا ان کا سب سے پہلا فرض ہے۔ یہ وہ مقصد ہے جو ہمیں سب سے زیادہ عزیز ہے۔ جب ہم امریکا یا انگلستان کو برا کہتے تو وہاں کے شریف عوام اور دانشور مراد نہیں ہوتے وہ ہمارے خاندان کے محترم رکن ہیں۔
انسانیت دشمن چاہے پاکستان کے رہنے والے ہوں یا امریکا اور انگلستان کے وہ ہماری نفرت کے یکساں طور پر مستحق ہیں۔ دنیا میں صرف دو عقیدے پائے جاتے ہیں۔ انسانیت اور انسانیت دشمن اور صرف دو قومیں رہتی ہیں انسان اور انسان دشمن۔ یہ دنیا کے ہر حصے میں ایک دوسرے سے برسرِ پیکار ہیں۔ یہ شاید ایک اتفاق ہے کہ ہمیں ایک ایسے دور میں اپنے انسانی فرض کی بجا آوری کا موقع ملا ہے۔ جن انسانیت کے دشمنوں نے مغرب کو اپنا مرکز قرار دیا ہے اگر یہ مرکزیت مشرق کو حاصل ہو جائے تو پھر ہماری تمام سخت کلامیوں کا ہدف مشرق قرار پائے گا۔
پیشہ ور مجرموں کے اس عالمی جتھے سے خبردار رہو جو نہ مغرب کا دوست ہے اور نہ مشرق کا۔ تمہاری تمام مصیبتوں اور محرمیوں کے ذمے دار یہی لوگ ہیں۔ یہ اور ان کے خیرخواہ انساںوں کو بہلانے اور بہکانے کے ہنر میں طاق ہیں۔ دیکھو صرف اچھی باتوں ہی کو اپنا مداوا نہ سمجھو۔ صرف باتوں سے بدن پر گوشت نہیں چڑھتا۔ ان جھوٹے اور باتونی چارہ گروں کی باتوں میں نہ آنا۔ یہ تمہیں محض خوش آیند لفظوں پر قانع رکھنا چاہتے ہیں۔ اگر زندہ رہنا ہے تو ایسی قناعت سے پناہ مانگو۔ اور ہاں عالمی اُخوت کے جعلی نعروں کا فریب کبھی نہ کھانا۔ کچھ لوگ ہیں جو اس باب میں بہت عجیب باتیں کرتے ہیں۔ یہ اپنے سرپرستوں سے کچھ کم نہیں ہیں۔
لو انھیں پہچانو! یہ گروہ اپنے ذاتی عقیدے کو دوسروں پر مسلط کرنا چاہتا ہے۔ انھیں اس کی کوئی فکر نہیں کہ ایک شخص فاقے کی آگ میں جل رہا ہے۔ انھیں اس بات سے سروکار ہے کہ وہ ان کا عقیدہ تسلیم کرتا ہے یا نہیں۔ یہ حضرات زمین اور اس کے معاملوں سے بہت بلند ہیں۔ انھوں نے تو آسمانوں کو گویا پہن لیا ہے۔ ان کے مقدس عقیدے کا نہ کوئی وطن ہے اور نہ کوئی زبان۔ یہ بستیوں کو، اُمنگوں کو بجھا دینا چاہتے ہیں۔ عالمی سماج کا نظریہ تمھیں وطن دشمنی اور اپنی تہذیب سے غداری کرنے کی تعلیم نہیں دیتا۔ مگر جس عالمی اُخوت کا نعرہ یہ لوگ بلند کرتے ہیں اس کا حاصل یہ ہے کہ تم اپنی آزادی استحکام حبِ وطن سماجی سالیمت اور اپنی تخلیقی انا سے یکسر دستبردار ہو جاؤ۔ اچھا فرض کرو کہ ان کا مطلب یہ نہیں ہے اور ہم بہتان تراشی سے کام لے رہے ہیں، پر یہ سوچو کہ اگر وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں اور تم اپنی زبان تہذیب اور اپنے وطن سے یکسر بیگانہ ہو جاؤ تو اس کا فائدہ کون اٹھائے گا، تم یا تمہارے دشمن؟
یقین کر لو اس کا فائدہ تمہارے دشمن اٹھائیں گے جو خود ان حضرات کے دوست نہیں ہیں۔
کچھ لوگ ہیں جو اس ملک کو برا کہہ کر ہی سکون پاتے ہیں۔ ایسے لوگ صرف یہیں پائے جاتے ہیں۔ دنیا کی کوئی قوم ایسی نہیں جو ایسے لوگوں کو اپنے درمیان پائے اور انھیں برداشت کرتی رہے۔ جنھیں اس قوم پہ غصہ آتا ہے، ان کا احترام کرو، ان کے سامنے محبت اور عقیدت سے گردنیں جھکاؤ مگر جو صرف برائی کرنا اور پاکستان کی تحریک کو طعنے دینا جانتے ہیں، انھیں نمک حرام اور غدار جانو کہ بروں کو برا کہنا اور سمجھنا بھی بڑی نیکی ہے۔
(مقبول شاعر اور نثر نگار جون ایلیا کی ادبی پرچے انشاء کے جنوری 1963 کے شمارے میں شایع ہونے والی فکر انگیز تحریر)