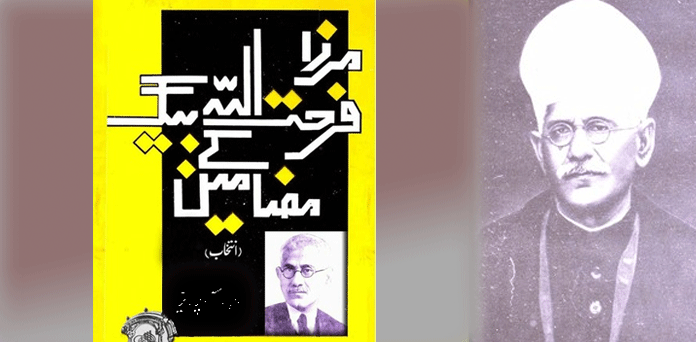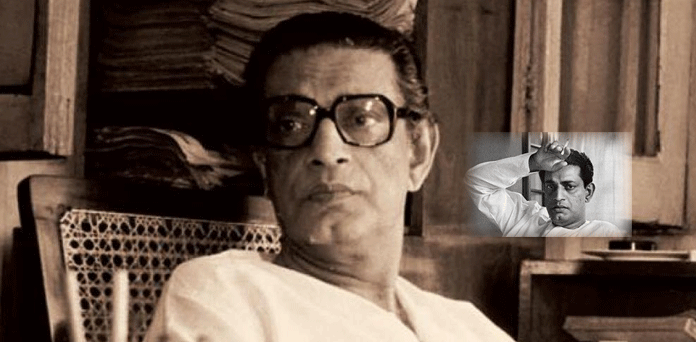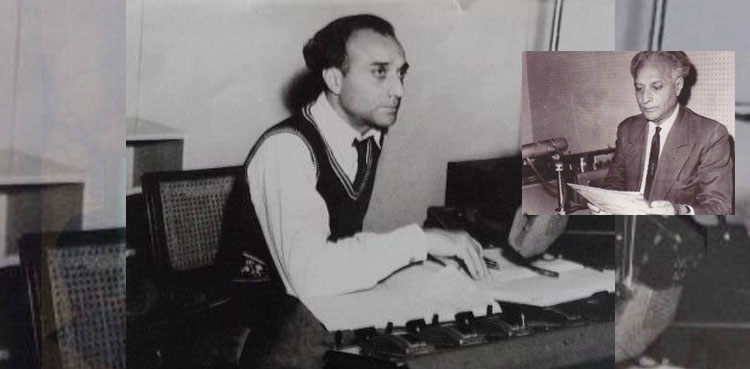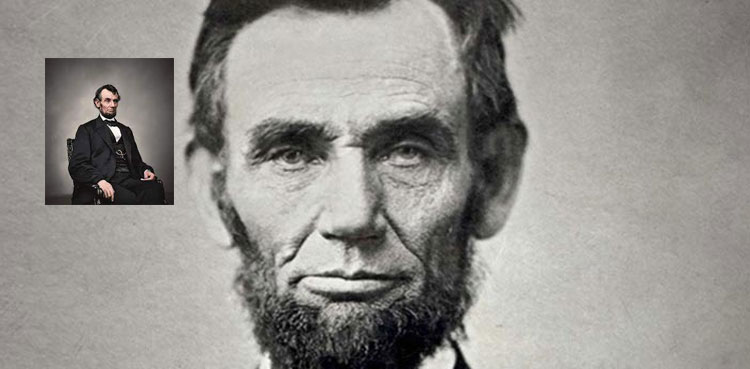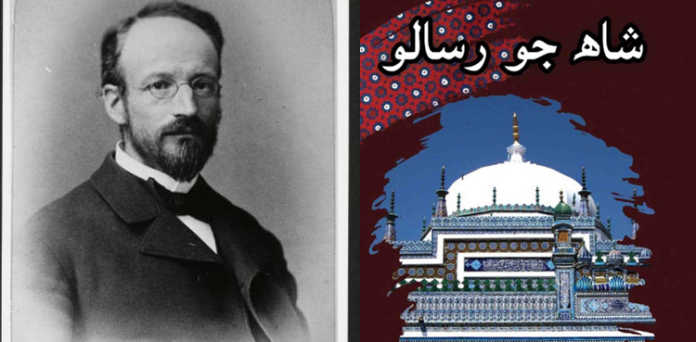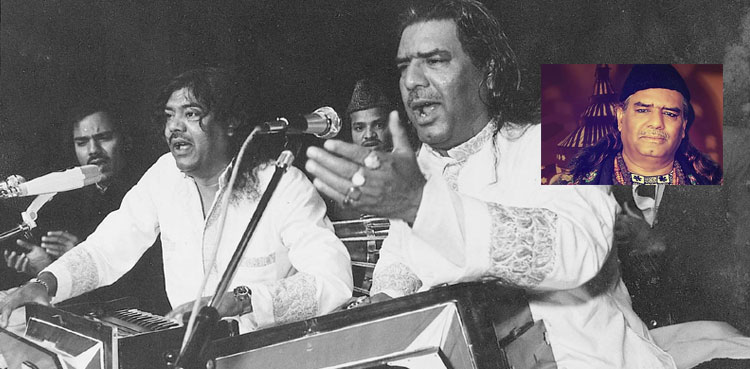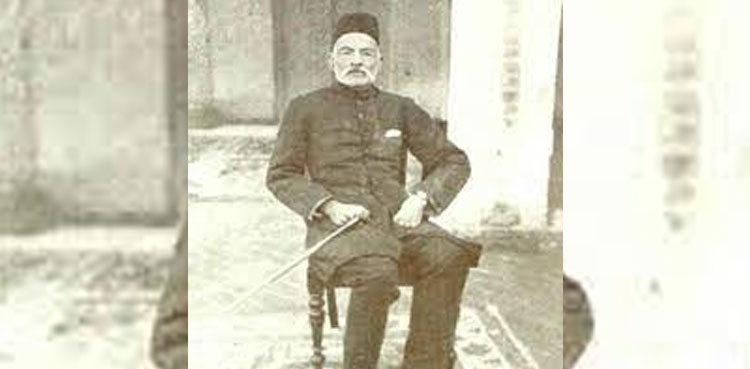متحدہ ہندوستان کی فلمی دنیا کا ایک نام شیام سندر چڈھا بھی ہے جنھیں بطور ہیرو ہی مقبولیت نہیں ملی بلکہ وہ اپنے رومانس اور اسکینڈلز کی وجہ سے بھی شہرت رکھتے تھے۔
25 اپریل 1951ء کو شیام نے ایک حادثے میں زندگی کی بازی ہار دی تھی۔ وہ ایک فلم کی شوٹنگ کے دوران گھوڑے سے گر کر زخمی ہوگئے تھے اور زندہ نہ بچ سکے۔ اس زمانے کے مقبول ترین فلمی جرائد نے اس افسوس ناک حادثے کی تفصیلات کے ساتھ شیام کی زندگی پر مضامین شایع کیے تھے۔ شیام کا خاندان تقسیم سے قبل راولپنڈی میں آباد تھا۔ ان کے دادا گاؤں کے پٹواری اور علاقے کے چند پڑھے لکھے اور صاحب ثروت لوگوں میں سے تھے۔ شیام نے فروری 1920 میں سیتا رام کے ہاں جنم لیا۔ والد ان کے فوج میں تھے۔ شیام کی والدہ چنن دیوی کا انتقال ہوگیا تو انھوں نے دوسری شادی کرلی جس نے شیام اور سارے بچوں کی پرورش کی۔ طالبِ علمی کے دور میں ڈرامہ اور مباحث نے شیام کو اپنی جانب کھینچ لیا تھا اور پھر اوائل جوانی میں وہ سوشلسٹ نظریات سے متاثر ہو گئے جس نے انھیں روشن خیال اور فن و ادب سے ان کا لگاؤ بھی بڑھا دیا۔ بعد میں وہ تھیٹر اور فلمی دنیا میں مشغول ہوگئے۔ شیام نے اپنی 10 سالہ فلمی زندگی میں بازار، کنیز، دل لگی، رات کی کہانی، چاندنی، مینا بازار نامی فلموں میں کام کیا تھا۔
اداکار شیام افسانہ نگار اور فلم رائٹر سعادت حسن منٹو کے گہرے دوستوں میں سے ایک تھے۔ معروف صحافی اور ادیب علی سفیان آفاقی لکھتے ہیں: وہ (شیام) اپنے رومان اور اسکینڈلوں کے لیے بہت مشور تھے۔ دراز قد، کھلتا ہوا رنگ، متناسب جسم، شوخ آنکھیں اور بات بات پر مسکرانا اور قہقہہ لگانا ان کی عادت تھی۔ ہندوستانی فلموں کے اداکار شیام کے مختلف فلمی ہیروئنوں کے ساتھ دوستیوں کے چرچے ہوتے رہتے تھے۔ ان کی کئی فلمیں بہت کام یاب ہوئی تھیں، اپنی دل کش شخصیت اور خوش مزاجی کی وجہ سے وہ فلمی دنیا میں بہت مقبول تھے۔ اس زمانے میں اخبارات میں فلمی دنیا کی خبریں شائع نہیں ہوتی تھیں۔ اس مقصد کے لئے بہت اچھے اور خوبصورت فلمی میگزین نکلا کرتے تھے جن سے فلمی دنیا اور فلمی لوگوں کے بارے میں معلومات حاصل ہوتی رہتی تھیں۔ ایک دن معلوم ہوا کہ شیام گھوڑے سے گر کر ہلاک ہو گئے۔ یہ سن کر بہت حیرت ہوئی کیونکہ شیام بہت اچھے گھڑ سوار تھے۔ بعد میں تفصیل معلوم ہوئی کہ شیام ایک فلم "شبستان” کی شوٹنگ کے لئے گھڑ سواری کر رہے تھے۔ اچانک گھوڑا بدک گیا اور شیام گھوڑے سے نیچے گر گئے۔ گرنے سے زیادہ چوٹ نہیں آئی لیکن المیہ یہ ہوا کہ ان کا پیر رکاب میں پھنس گیا تھا۔ گھوڑا مسلسل بھاگتا رہا یہاں تک کہ لوگوں نے اس کو پکڑ کر شیام کا پیر رکاب سے نکالا۔ مگر کافی دور تک زمین پر گھسیٹنے اور سَر کے زمین سے ٹکرانے کی وجہ سے شدید چوٹیں آئی تھیں۔ انہیں فوراً اسپتال لے جایا گیا لیکن وہ جاں بر نہ ہوسکے۔ اس طرح ایک ہنستا کھیلتا خوش باش اداکار چند لمحے میں زندگی سے رشتہ توڑ گیا۔
شیام جس وقت دنیا سے رخصت ہوئے اس وقت وہ شادی شدہ اور دو بچوں کے باپ تھے۔ شیام رنگین مزاج اور دل پھینک تو تھے ہی۔ اس زمانے میں ایک سوشل گرل ممتاز قریشی سے ان کی ملاقات ہوئی۔ یہ ملاقات پسندیدگی اور پھر پیار میں تبدیل ہو گئی۔ قیام پاکستان کے بعد جب شیام نے بمبئی میں رہائش اختیار کی تو ان کی شادی شدہ زندگی بہت خوشگوار تھی۔ شیام دنیا سے رخصت ہوگئے لیکن دو بچے اور ایک بیوی چھوڑ گئے۔ ایک لڑکا اور ایک لڑکی۔ شیام کی ہلاکت کے بعد تاجی اپنے بچوں کو لے کر بمبئی سے لاہور آ گئی۔ ان کا ایک بیٹا شاکر اور ایک بیٹی ساحرہ ساتھ تھی، ممتاز بیگم عرف تاجی نے روالپنڈی کے ایک بڑے عہدے دار سے شادی کرلی جس نے تاجی اور شیام کے بچوں کو اپنے حقیقی بچوں کی طرح پالا پوسا، اعلی تعلیم دلوائی اور انہیں ہر وہ سہولت فراہم کی جو ایک باپ اپنے بچوں کو دے سکتا ہے۔
شیام کا اصل نام شیام سندر چڈھا تھا۔ اس کے گھرانے کا تعلق راولپنڈی سے تھا۔ چڈھا پنجابی ہندو کتھری ذات سے تعلق رکھتے ہیں۔ شیام کی پرورش راولپنڈی میں ہوئی تھی۔ اس نے پنڈی کے مشہور گورڈن کالج میں تعلیم حاصل کی تھی۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد شیام نے فلمی صنعت میں کام کرنے کا ارادہ کیا۔ شیام نے اداکاری کا آغاز ایک پنجابی فلم "گوانڈی” سے کیا۔ یہ فلم 1942ء میں بنائی گئی تھی۔ اس کے بعد وہ بمبئی چلا گیا جہاں اداکار کی حیثیت سے اس کو بہت کامیابیاں حاصل ہوئیں اور وہ ایک مقبول ہیرو بن گیا۔
سعادت حسن منٹو نے اپنے ہم عصر اہلِ قلم اور فلم آرٹسٹوں کے واقعات اور شخصی خاکے لکھے ہیں اور شیام سے بھی ان کی گہری دوستی تھی۔ منٹو نے سندر شیام چڈھا کا بھی خاکہ لکھا ہے۔
1942ء میں جب شیام نے فلموں میں کام شروع کیا تھا تو منٹو بھی فلم کے لیے کہانیاں اور مکالمے لکھنے میں مصروف تھے اور وہیں ان کی دوستی کا آغاز بھی ہوا۔ منٹو اپنے ایک خاکے میں شیام سے متعلق لکھتے ہیں: شیام صرف بوتل اور عورت ہی کا رسیا نہیں تھا۔ زندگی میں جتنی نعمتیں موجود ہیں، وہ ان سب کا عاشق تھا۔ اچھی کتاب سے بھی وہ اسی طرح پیار کرتا تھا جس طرح ایک اچھی عورت سے کرتا تھا۔ اس کی ماں اس کے بچپن ہی میں مر گئی تھی مگر اس کو اپنی سوتیلی ماں سے بھی ویسی ہی محبت تھی، جو حقیقی ماں سے ہوسکتی ہے۔ اس کے چھوٹے چھوٹے سوتیلے بہن بھائی تھے۔ ان سب کو وہ اپنی جان سے زیادہ عزیز سمجھتا تھا۔ باپ کی موت کے بعد صرف اس کی اکیلی جان تھی۔ جو اتنے بڑے کنبے کی دیکھ بھال کرتی تھی۔
ایک عرصے تک وہ انتہائی خلوص کے ساتھ دولت اور شہرت حاصل کرنے کے لیے ہاتھ پاؤں مارتا رہا۔ اس دوران میں تقدیر نے اسے کئی غچے دیے مگر وہ ہنستا رہا، ’’جانِ من ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ تو میری بغل میں ہوگی۔‘‘ اور وہ کئی برسوں کے بعد آخر وہ دن آہی گیا کہ دولت اور شہرت دونوں اس کی جیب میں تھیں۔
موت سے پہلے اس کی آمدنی ہزاروں روپے ماہوار تھی۔ بمبے کے مضافات میں ایک خوبصورت بنگلہ اس کی ملکیت تھا اور کبھی وہ دن تھے کہ اس کے پاس سر چھپانے کو جگہ نہیں تھی، مگر مفلسی کے ان ایام میں بھی وہی ہنستا ہوا شیام تھا۔ دولت و شہرت آئی تو اس نے ان کا یوں استقبال نہ کیا جس طرح لوگ ڈپٹی کمشنر کا کرتے ہیں۔ یہ دونوں محترمائیں اس کے پاس آئیں تو اس نے ان کو اپنی لوہے کی چارپائی پر بٹھا لیا اور پٹاخ پٹاخ بوسے داغ دیے۔
میں اور وہ جب ایک چھت کے نیچے رہتے تھے تو دونوں کی حالت پتلی تھی۔ فلم انڈسٹری ملک کی سیاسیات کی طرح ایک بڑے ہی نازک دور سے گزر رہی تھی۔ میں بمبئی ٹاکیز میں ملازم تھا۔ اس کا وہاں ایک پکچر کا کنٹریکٹ تھا دس ہزار روپے میں۔ عرصے کی بیکاری کے بعد اس کو یہ کام ملا تھا۔ مگر وقت پر پیسے نہیں ملتے تھے۔ بہرحال ہم دونوں کا گزر کسی نہ کسی طور ہو جاتا تھا۔ میاں بیوی ہوتے تو ان میں روپے پیسے کے معاملے میں ضرور چخ چخ ہوتی، مگر شیام اور مجھے کبھی محسوس تک نہ ہوا۔ ہم میں سے کون خرچ کررہا ہے اور کتنا کررہا ہے۔
ایک دن اسے بڑی کوششوں کے بعد موٹی سی رقم ملی (غالباً پانچ سو روپے تھے) میری جیب خالی تھی۔ ہم ملاڈ سے گھر آرہے تھے۔ راستے میں شیام کا یہ پروگرام بن گیا کہ وہ چرچ گیٹ کسی دوست سے ملنے جائے گا۔ میرا اسٹیشن آیا تو اس نے جیب سے دس دس روپے کے نوٹوں کی گڈی نکالی۔ آنکھیں بند کر کے اس کے دو حصے کیے اور مجھ سے کہا، ’’جلدی کرو منٹو۔۔۔ ان میں سے ایک لے لو۔‘‘
میں نے گڈی کا ایک حصہ پکڑ کر جیب میں ڈال لیا۔ اور پلیٹ فارم پر اتر گیا۔ شیام نے مجھے’’ٹاٹا‘‘ کہا اور کچھ نوٹ جیب سے نکال کر لہرائے، ’’تم بھی کیا یاد رکھو گے سیفٹی کی خاطر میں نے یہ نوٹ علیحدہ رکھ لیے تھے۔۔۔ ہیپ ٹلا!‘‘ شام کو جب وہ اپنے دوست سے مل آیا تو کباب ہورہا تھا۔ مشہور فلم اسٹار’’کے کے‘‘ نے اس کو بلایا تھا کہ وہ اس سے ایک پرائیویٹ بات کرنا چاہتی ہے۔ شیام نے برانڈی کی بوتلیں بغل میں سے نکال کر اور گلاس میں ایک بڑا پیگ ڈال کر مجھ سے کہا، ’’پرائیویٹ بات یہ تھی۔ میں نے لاہور میں ایک دفعہ کسی سے کہا تھا کہ ’’کے کے‘‘ مجھ پر مرتی ہے۔ خدا کی قسم بہت بری طرح مرتی تھی۔ لیکن ان دنوں میرے دل میں کوئی گنجائش نہیں تھی۔ آج اس نے مجھے اپنے گھر بلا کر کہا کہ تم نے بکواس کی تھی۔ میں تم پر کبھی نہیں مری۔ میں نے کہا تو آج مر جاؤ۔ مگر اس نے ہٹ دھرمی سے کام لیا اور مجھے غصے میں آکر اس کے ایک گھونسہ مارنا پڑا۔‘‘ میں نے اس سے پوچھا، ’’تم نے ایک عورت پر ہاتھ اٹھایا؟‘‘ شیام نے مجھے اپنا ہاتھ دکھایا جو زخمی ہو رہا تھا، ’’کم بخت آگے سے ہٹ گئی۔ نشانہ چوکا اور میرا گھونسہ دیوار کے ساتھ جا ٹکرایا۔‘‘ یہ کہہ کر وہ خوب ہنسا، ’’سالی بیکار تنگ کررہی ہے۔‘‘
میں نے اوپر روپے پیسے کا ذکر کیا ہے۔ غالباً دو برس پیچھے کی بات ہے۔ میں یہاں لاہور میں فلمی صنعت کی زبوں حالی اور اپنے افسانے’’ٹھنڈا گوشت‘‘ کے مقدمے کی وجہ سے بہت پریشان تھا۔ عدالتِ ماتحت نے مجھے مجرم قرار دے کر تین مہینے قیدِ بامشقت اور تین سو روپے جرمانے کی سزا دی تھی۔ میرا دل اس قدر کھٹا ہوگیا تھا کہ جی چاہتا تھا، اپنی تمام تصانیف کو آگ میں جھونک کر کوئی اور کام شروع کردوں جس کا تخلیق سے کوئی علاقہ نہ ہو۔ چنگی کے محکمے میں ملازم ہو جاؤں اور رشوت کھا کر اپنا اور اپنے بال بچوں کا پیٹ پالا کروں، کسی پر نکتہ چینی کروں نہ کسی معاملے میں اپنی رائے دوں۔
ایک عجیب و غریب دور سے میرا دل و دماغ گزر رہا تھا۔ بعض لوگ سمجھتے تھے کہ افسانے لکھ کر ان پر مقدمے چلوانا میرا پیشہ ہے۔ بعض کہتے تھے کہ میں صرف اس لیے لکھتا ہوں کہ سستی شہرت کا دلدادہ ہوں اور لوگوں کے سفلی جذبات مشتعل کر کے اپنا الو سیدھا کرتا ہوں۔ مجھ پر چار مقدمے چل چکے ہیں۔ ان چار الوؤں کو سیدھا کرنے میں جو خم میری کمر میں پیدا ہوا، اس کو کچھ میں ہی جانتا ہوں۔
مالی حالت کچھ پہلے ہی کمزور تھی۔ آس پاس کے ماحول نے جب نکما کردیا تو آمدنی کے محدود ذرائع اور بھی سکڑ گئے۔ ایک صرف مکتبہ جدید، لاہور کے چودھری برادران تھے جو مقدور بھر میری امداد کررہے تھے۔ غم غلط کرنے کے لیے جب میں نے کثرت سے شراب نوشی شروع کی تو انہوں نے چاہا کہ اپنا ہاتھ روک لیں۔ مگر وہ اتنے مخلص تھے کہ مجھے ناراض کرنا نہیں چاہتے تھے۔
اس زمانے میں میری کسی سے خط کتابت نہیں تھی۔ دراصل میرا دل بالکل اچاٹ ہو چکا تھا۔ اکثر گھر سے باہر رہتا اور اپنے شرابی دوستوں کے گھر پڑا رہتا، جن کا ادب سے دور کا بھی واسطہ نہیں تھا۔ ان کی صحبت میں رہ کر جسمانی و روحانی خود کشی کی کوشش میں مصروف تھا۔ ایک دن مجھے کسی اور کے گھر کے پتے سے ایک خط ملا۔ تحسین پکچرز کے مالک کی طرف سے تھا۔ لکھا تھا کہ میں فوراً ملوں۔ بمبے سے انہیں میرے بارے میں کوئی ہدایات موصول ہوئی ہے۔ صرف یہ معلوم کرنے کے لیے یہ ہدایت بھیجنے والا کون ہے۔ میں تحسین پکچرز والوں سے ملا۔ معلوم ہوا کہ بمبے سے شیام کے پے در پے انہیں کئی تار ملے ہیں کہ مجھے ڈھونڈ کر 500 روپے دے دیے جائیں۔ میں جب دفتر میں پہنچا تو وہ شیام کے تازہ تاکیدی تار کا جواب دے رہے تھے کہ تلاشِ بسیار کے باوجود انہیں منٹو نہیں مل سکا۔ میں نے 500 روپے لے لیے اور میری مخمور آنکھوں میں آنسو آگئے۔
میں نے بہت کوشش کی کہ شیام کو خط لکھ کر اس کا شکریہ ادا کروں اور پوچھوں کہ اس نے مجھے یہ 500 روپے کیوں بھیجے تھے، کیا اس کو علم تھا کہ میری مالی حالت کمزور ہے۔ اس غرض سے میں نے کئی خط لکھے اور پھاڑ ڈالے۔ ایسا محسوس ہوتا کہ میرے لکھے ہوئے الفاظ شیام کے اس جذبے کا منہ چڑا رہے ہیں جس کے زیرِ اثر اس نے مجھے یہ روپے روانہ کیے تھے۔