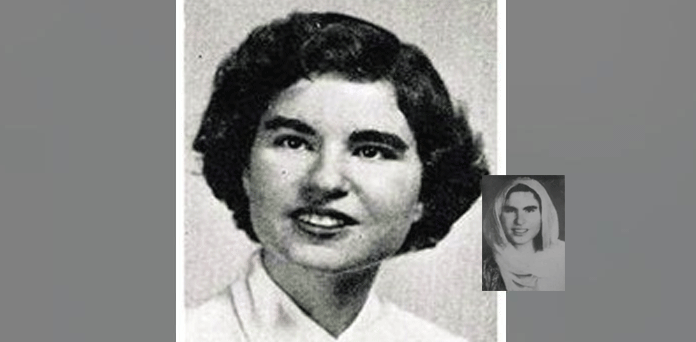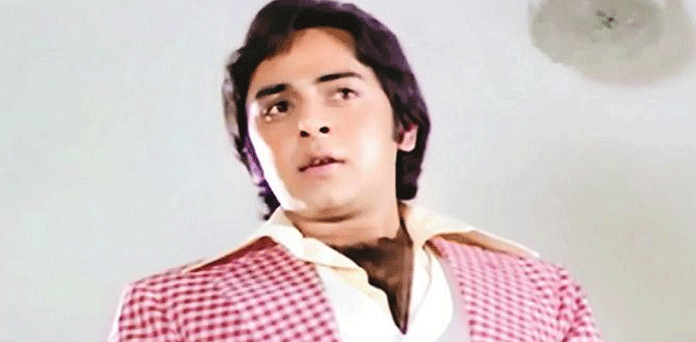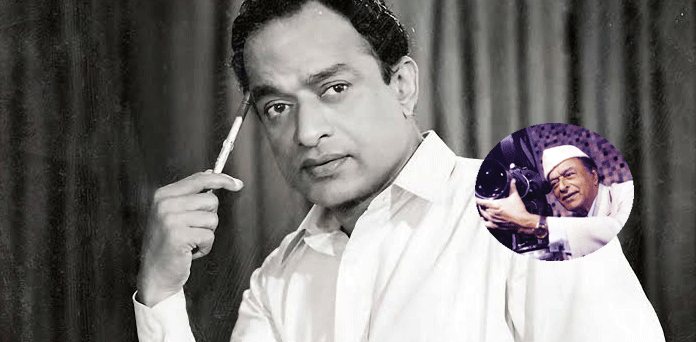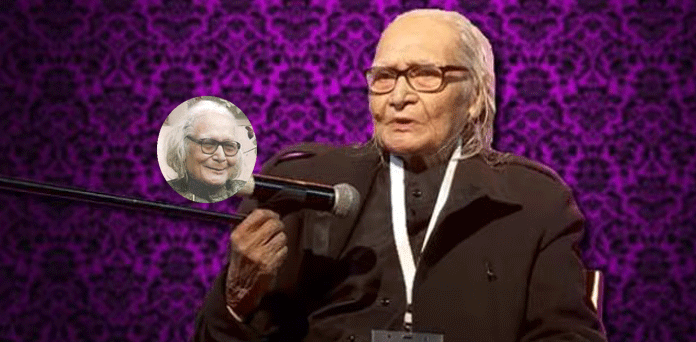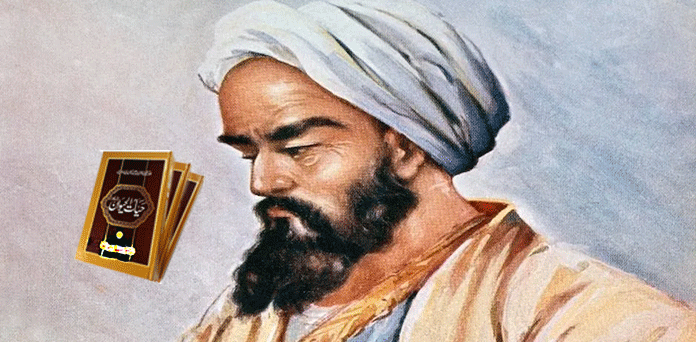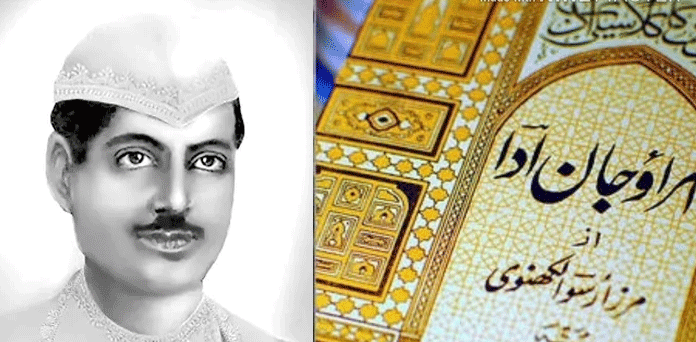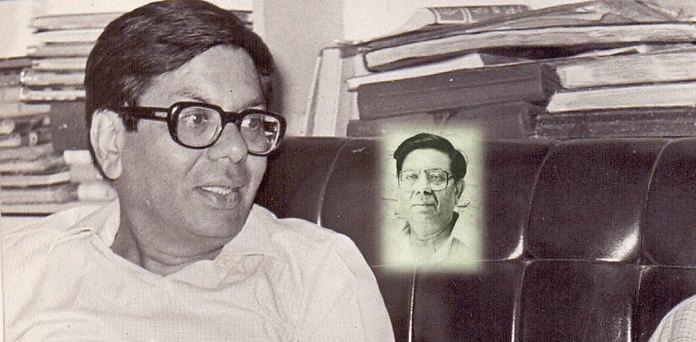مریم جمیلہ کا نام والدین نے مارگریٹ مارکیوس رکھا تھا۔ لیکن قبولِ اسلام کے بعد نوجوان مارگریٹ مارکیوس نے اپنا نام تبدیل کرلیا۔ مریم جمیلہ کا تعلق اس یہودی خاندان سے تھا جو جرمنی سے امریکہ ہجرت کرگیا تھا، لیکن 24 مئی 1961ء کو اللہ کی وحدانیت پر ایمان لانے اور پیغمبرِ اسلام کے آخری نبی ہونے کی گواہی دینے کے بعد مریم جمیلہ امریکہ سے پاکستان چلی آئیں اور یہیں 31 اکتوبر 2012ء کو وفات پائی۔ آج مریم جمیلہ کی برسی ہے۔
22 مئی 1934ء کو امریکہ میں پیدا ہونے والی مارگریٹ مارکیوس کے آبا و اجداد کا وطن جرمنی تھا۔ ان کے بزرگ امریکہ منتقل ہوگئے اور نیوروشیل میں سکونت اختیار کی۔ یہاں ان کے والد کی شادی ہوئی اور بیٹی مارگریٹ نے جنم لیا۔ وہ اسکول میں ذہین طالبہ مشہور تھیں۔ ہائی اسکول سے فارغ ہونے کے بعد جب یونیورسٹی میں داخلہ لیا تو پہلے سمسٹر کے آغاز پر مارگریٹ ایک بیماری کا شکار ہوگئیں اور مجبوراً تعلیم ادھوری چھوڑنا پڑی۔ اسی عرصہ میں انھوں نے مذاہب میں دل چسپی لینا شروع کی۔ 1953ء میں مارگریٹ نے نیویارک یونیورسٹی میں داخلہ لیا اور وہاں اسلام اور یہودیت کے موضوع میں ان کی دل چسپی بڑھتی چلی گئی۔ مارگریٹ اسلام کی بنیادی تعلیمات کو جاننے اور سمجھنے کی کوشش کرنے لگیں۔ انھوں نے دونوں مذاہب کی کتابوں کا مطالعہ کرنے کے علاوہ اسکالرز سے رجوع کیا اور کی مدد سے مذاہب کا تقابلی جائزہ لینا شروع کیا۔ 1956ء میں ایک مرتبہ پھر ان پر بیماری غالب آگئی اور مارگریٹ کو اسپتال میں داخل ہونا پڑا۔ اس بار طویل علالت کے سبب رسمی تعلیم کا سلسلہ ختم ہو گیا اور وہ ڈگری حاصل نہ کرسکیں لیکن ان کا مذاہب کا مطالعہ جاری رہا۔ والدین سے سوالات کرنے کے علاوہ وہ اپنے مذہب کے علما سے بھی ملتی رہیں، لیکن یہودیت اور اسلام کا موازنہ اور تقابلی مطالعہ کرنے کے دوران ان کی بے چینی بڑھتی جارہی تھی کہ انھیں ایک اور نومسلم مستشرق علّامہ محمد اسد کی کتاب’’ روڈ ٹو مکّہ‘‘ پڑھنے کا موقع ملا۔ مارگریٹ قرآن کے تراجم تو پہلے بھی پڑھ رہی تھیں۔ ایک موقع پر انھوں نے فیصلہ کیا کہ اسپتال سے نکل کر وہ اپنا مذہب ترک کر دیں گی۔ انھوں نے یہی کیا اور بعد میں نیویارک کے مسلمانوں سے میل جول بڑھاتے ہوئے اسلامک سینٹر جانے لگیں۔ اپنے والدین سے یہودی تعلیمات پر الجھنے اور اسلام کی جانب جھکاؤ دکھانے پر ان کا اپنے خاندان سے اختلاف ہوگیا تھا اور 1959ء والدین نے انھیں علیحدہ کر دیا۔ نوجوان مارگریٹ کو ملازمت کرنا پڑی تاکہ وہ اپنی ضروریات پوری کرسکیں۔ اسی زمانے میں انھیں مولانا مودودی کا ایک مقالہ ’’لائف آفٹر ڈیتھ‘‘ پڑھنے کا موقع ملا اور مارگریٹ اس سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکیں۔ 1960ء کے آخر میں انھوں نے مولانا سے خط کتابت کے بعد قبولِ اسلام کا فیصلہ کیا۔ مارگریٹ بروکلین میں نیویارک کے اسلامک مشن کے ڈائریکٹر شیخ داؤد احمد فیصل کے پاس گئیں اور کلمہ پڑھ کر مشرف بہ اسلام ہوئیں۔ ان کا اسلامی نام مریم جمیلہ رکھا گیا۔
قبولِ اسلام کے بعد مریم جمیلہ کو مغرب میں ایک مبلغ کے طور پر پہچانا گیا۔ بعد میں مریم جمیلہ نے پاکستان منتقل ہونے کا فیصلہ کیا اور یہاں آنے کے بعد وہ مکمل طور پر مسلم تہذیب اور پاکستانی معاشرت میں ڈھل گئیں۔ مریم جمیلہ نے اردو زبان بھی سیکھی۔ 1963ء میں ان کا نکاح محمد یوسف خاں صاحب سے پڑھایا گیا۔ شادی کے بعد وہ لاہور میں رہیں اور لاہور ہی میں انتقال ہوا۔
مریم جمیلہ نے یہاں تصنیف و تالیف کا سلسلہ بھی جاری رکھا تھا اور ان کا موضوع اسلام اور اس کی تعلیمات تھیں، اسلام کے مختلف پہلوؤں کو انھوں نے انگریزی زبان اجاگر کیا اور دوسروں کی راہ نمائی اور ہدایت کے لیے چھوٹی بڑی 34 کتابیں لکھیں۔ مریم جمیلہ کی تصنیف کردہ کتابوں میں اِز ویسٹرن سویلائزیشن یونیورسل، اسلام ان تھیوری اینڈ پریکٹس، اسلام اینڈ اورینٹل ازم، اسلام اینڈ موڈرن ازم اور اسلام ورسز دی ویسٹ سرفہرست ہیں۔