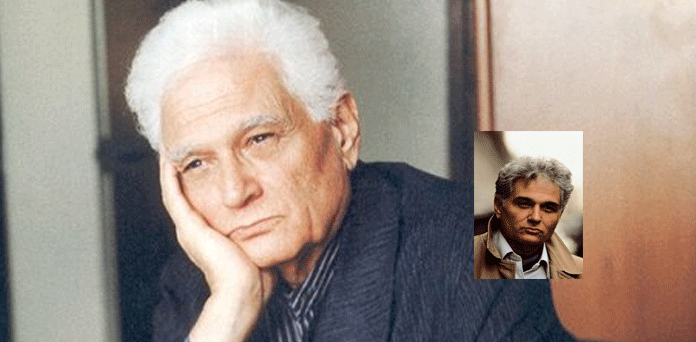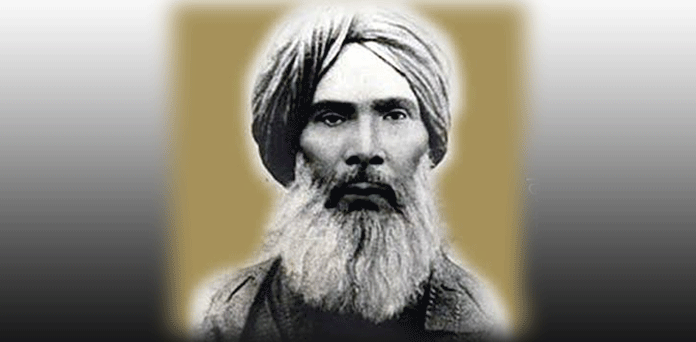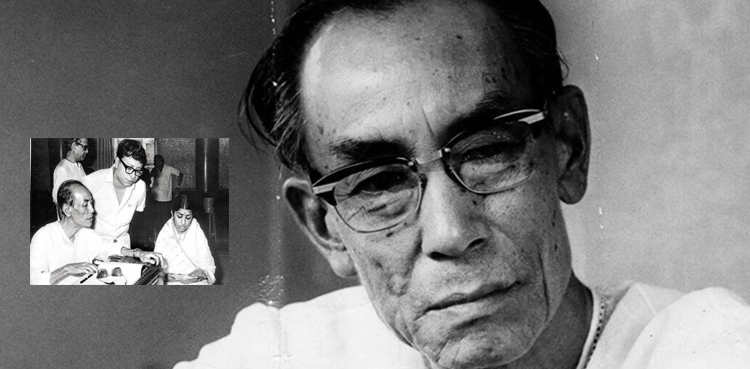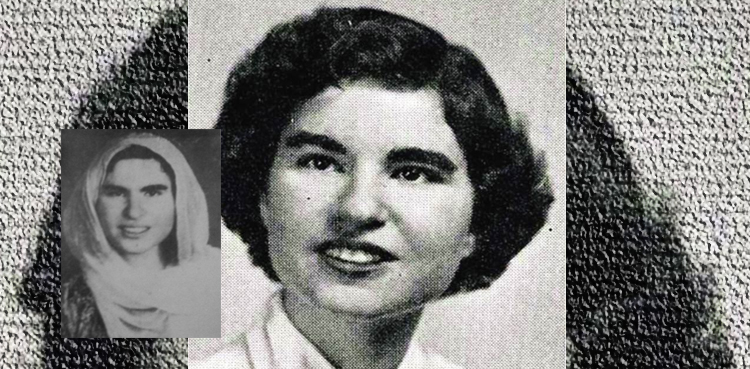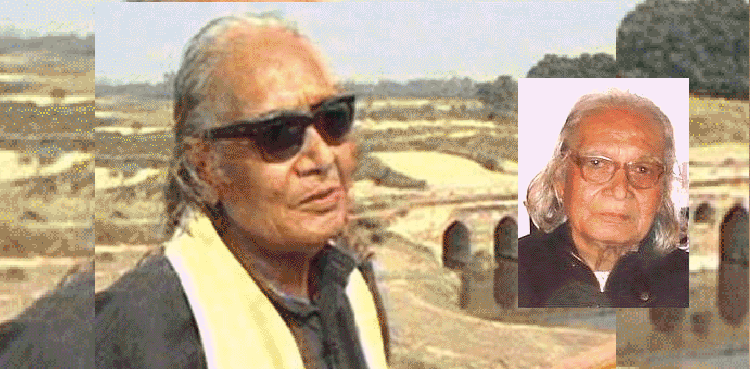فلسفہ، تنقید اور لسانیات کے یگانۂ روزگار کی حیثیت سے مشہور ژاک دریدا کو ردِ ساختیات (ڈی کنسٹرکشن) کا بانی بھی کہا جاتا ہے اور دریدا کے وطن فرانس میں اسے عظیم فلسفی اور دانش ور سارتر کے بعد سب سے زیادہ اہمیت دی جاتی ہے۔ دریدا کے فلسفے اور نظریات کی ہمہ گیری نے علم و ادب کے ہر شعبہ کو متأثر کیا اور اسے عالمی سطح پر شہرت ملی مگر اس فلسفی نے جس دور میں اپنے افکار اور خیالات کو بیان کیا، اس دور میں وہ صاحبِ علم شخصیات اور اہلِ قلم کی مخالفت اور تنقید کا نشانہ بنا۔ دریدا کے خیالات کو لایعنی اور اس کے فلسفے کو بے معنی کہہ کر مسترد کیا گیا۔ لیکن بعد میں دنیا نے اسے ایک دانش ور تسلیم کیا۔
علم و ادب کی دنیا کے بعض ناقدوں اور خاص طور پر برطانوی یونیورسٹی کیمبرج کے اساتذہ اس کے بعض مباحث کو لایعنی کہہ کر مسترد کرتے رہے تھے، جس میں دریدا کا یہ فلسفہ کہ معنیٰ، متن سے ماورا ایسی تہ داری رکھتے ہیں جو تہذیبی اور تاریخی عمل سے نمو پاتی ہے، بھی شامل تھا۔ بعد میں دریدا کے اسی فلسفے نے ادب، فن، اخلاقیات اور روایتی مابعدالطبعیات پر گہرے اثرات مرتب ہوئے۔ اس فلسفی کے لسانیات اور ادبیات پر اثرات کی مثال بہت کم ملتی ہے۔
ژاک دریدا الجزائر کے ایک یہودی خاندان کا فرد تھا، اس نے 1930ء میں آنکھ کھولی اور کینسر کے مرض میں مبتلا ہوکر 9 اکتوبر 2004 کو چل بسا۔ ژاک دریدا نے جس زمانے میں آنکھ کھولی اس وقت الجزائر پر فرانس کا غلبہ تھا اور وہاں ایک عرصہ تک آزادی کی تحریک بھی چلتی رہی تھی۔ ژاک دریدا کے افکار اور اس کا فلسفہ اکثر تورات کے زیرِ اثر نظر آتا ہے۔ ابتدائی تعلیم تو اس نے الجزائر میں مکمل کی تھی لیکن بعد میں فرانس منتقل ہوگیا اور وہاں تعلیم حاصل کرنے کے بعد وہ ہاورڈ اور سوربون میں فلسفہ پڑھانے لگا اور اسی زمانے میں باقاعدہ لکھنے کا آغاز کیا۔ اس کے افکار کو جرمن فلسفی مارٹن ہائیڈیگر، ایڈمنڈ ہسرل اور فرائڈ کے خیالات کی توسیع سمجھا جاتا ہے۔ رفتہ رفتہ وہ فرانس میں شہرت حاصل کرنے لگا اور اس کے افکار کو قبول کیا جانے لگا جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ کیمبرج ہی نے 1992ء میں دریدا کو اعزازی ڈگری دی۔ اس نے فرانس میں تارکینِ وطن کے حقوق اور چیکو سلواکیہ میں آزادی کی حمایت میں مہم بھی چلائی جب کہ جنوبی افریقہ کی نسل پرست حکومت کا مخالف اور نیلسن منڈیلا کا بڑا حامی رہا۔
2003ء میں دریدا کے نام ہی سے اس کی زندگی پر ایک فلم بنائی گئی تھی جس کا دورانیہ 84 منٹ تھا۔ اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ وہ شخص جس کے فلسفے اور افکار کو فرانس میں در و قبول کی مشکل پیش آرہی تھی، اپنا آپ منوا چکا تھا اور اس کے فلسفے کو علم و ادب کے مختلف شعبہ میں اہمیت حاصل ہوگئی تھی۔ اس نے اپنے ذہن و ذکاوت کو بروئے کار لاتے ہوئے نہ صرف افکارِ تازہ کے وسیلے سے جہانِ تازہ تک رسائی کے امکانات کو یقینی بنایا بلکہ اپنے انقلابی تصورات سے نئی نسل کو بھی متأثر کیا۔ اس کے متنوع افکار کی ہمہ گیری اور ان کے اثرات کا اندازہ اس امر سے لگایا جا سکتا ہے کہ یورپ میں ژاک دریدا کی حیات و خدمات اور فلسفیانہ تصوّرات پر پانچ سو سے زائد مفصل اور جامع تحقیقی مقالات لکھے گئے۔ ریسرچ اسکالرز نے چودہ ہزار سے زائد مقالات لکھ کر اس کے اسلوب کی تفہیم کی کوشش کی اور آج بھی یہ سلسلہ جاری ہے۔
ژاک دریدا کی ان تصانیف کے تراجم دنیا کی مختلف زبانوں میں کیے گئے اور ان پر تحقیق و تنقید کا سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ Husserl’s geometry 1962 میں، Speech and phenomena 1973 میں اور اس کے بعد دو مشہور تصانیف Of Grammatology اور Writing and Difference کے عنوان سے سامنے آئیں۔