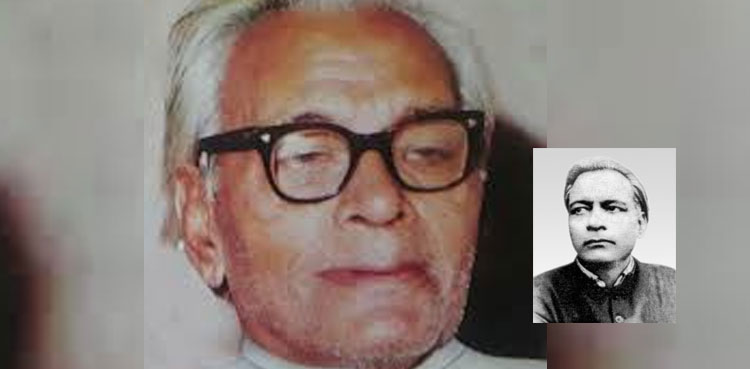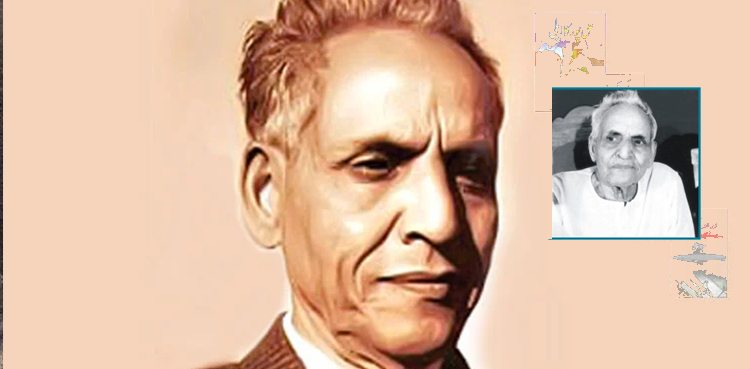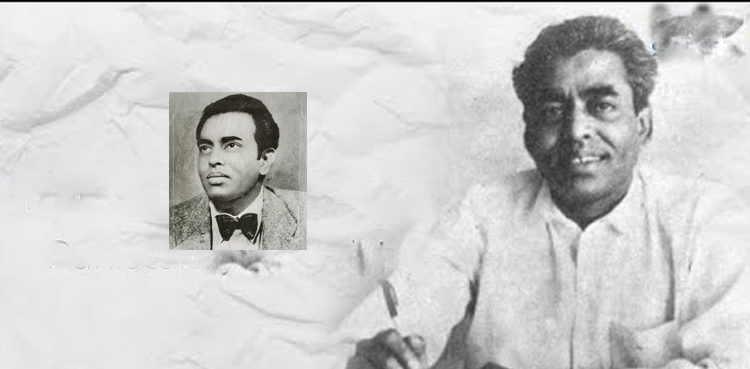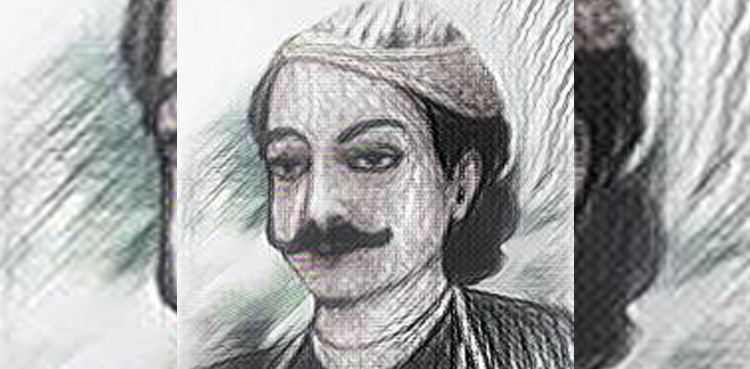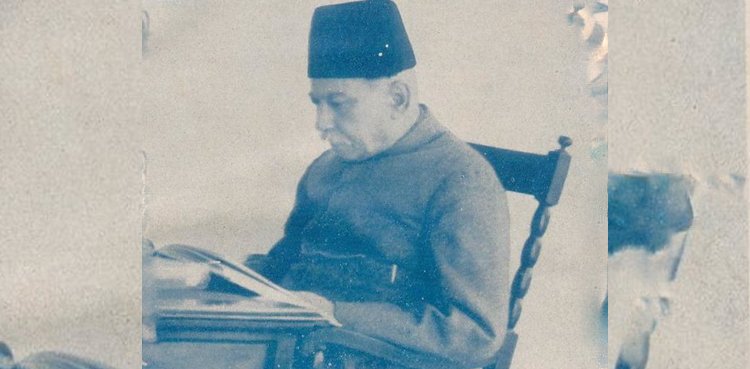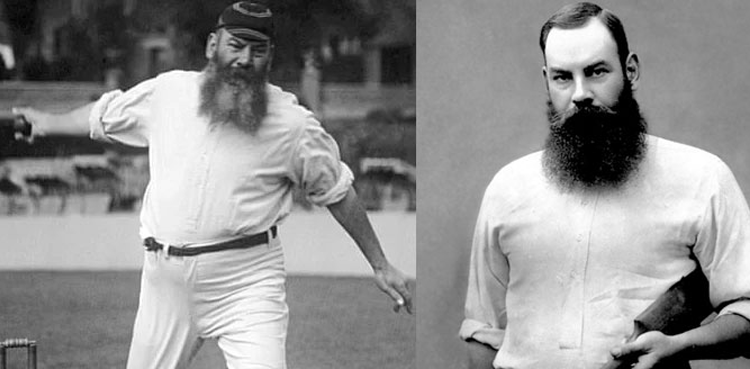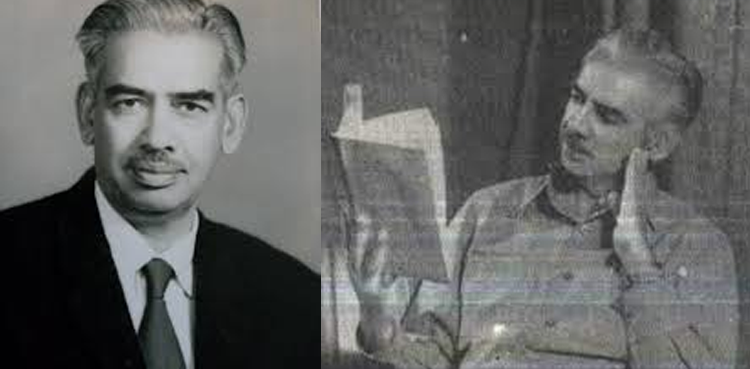شعروں میں مرا خونِ جگر بول رہا ہے
الفاظ ہیں خاموش ہنر بول رہا ہے
اس شعر کے خالق خواجہ محمد امیر المتخلص بہ صبا اکبر آبادی ہیں۔ صبا صاحب کی ساری عمر محبت کرنے اور بانٹنے میں بسر ہوئی۔ محض آپ کا طرزِ حیات ہی نہیں بلکہ وہ تمام اصنافِ سخن جن میں آپ نے طبع آزمائی کی گواہی دیتے ہیں کہ صباؔ اکبر آبادی سراپا محبت تھے اور یہ کہنے میں حق بجانب تھے کہ
محبت کے علاوہ ہے ہنر کیا
کیا ہے اور ہم نے عمر بھر کیا
لیکن اس کارِ محبت نے آپ کو ناکارہ بنانے کے بجائے ایسا فعال بنا دیا کہ اپنے پرائے سب یکساں اعتماد کے ساتھ آپ کے درِ دل میں داخل ہوتے اور بلا تخصیص فیض پاتے۔ بقول آپ کی والدہ سرفرازی بیگم ”محمد امیر تو مانگنے والوں کو اپنے جسم کے کپڑے تک دینے سے باز نہ آئے گا۔“ گویا صباؔ صاحب کے دل میں موجزن محبت کے جذبات نے اعلیٰ انسانی و اخلاقی اقدار کو خوب خوب فروغ دیا۔ یہی رویہ آپ نے اپنی شعری تخلیقات میں بھی اختیار کیا اور بے اختیار کیا۔
صبا صاحب اکبر آباد (آگرہ) میں ش 14 اگست 1908ء کو پیدا ہوئے۔ والد کا نام ڈاکٹر خواجہ علی محمد تھا۔ یہ 1920ء کی بات ہے جب ان کی محض بارہ برس تھی اور ایک مشاعرے میں شمعِ آزادی کے پروانوں کے درمیان خواجہ غیور اکبر آبادی کے نام سے فی البدیہ کلام سنانے کا موقع ملا۔ اُس روز آپ کے حصّے میں ایک نہیں تین اعزاز آئے تھے۔ اوّل نوعمری میں پہلا مشاعرہ پڑھ کر مشاعرہ لوٹنا وہ بھی رئیسُ الاحرار حسرت موہانی کی صدارت میں اور اُن سے داد وصول کرنا۔ دوم مشاعرے کے آخری شاعر جوش ملیح آبادی کے بعد پڑھنا اور سوم آپ کے والد ڈاکٹر خواجہ علی محمد کا آپ کا تخلیقی جوہر پہچان کر شاعری کی تربیت کے لیے آپ کو اخضرؔ اکبر آبادی کی شاگردی میں دینا۔
اخضرؔ صاحب نے اپنے شاگرد کا تخلص صباؔ رکھ دیا۔ صبا اکبر آبادی نے حمد، نعت، منقبت، مرثیہ، سلام، رباعی، نظموں اور غزل میں نہ صرف طبع آزمائی کی بلکہ قادر الکلام شاعر کہلائے۔
صبا اکبر آبادی کے حمدیہ اور نعتیہ کلام میں ایک عاشقِ صادق کا دل دھڑکتا ہُوا محسوس ہوتا ہے۔
خالقِ ارض و سما کی اوّلین تخلیق تھے
آخری پیغامِ رب دُنیا میں لائے مصطفیٰ
مشغلے دونوں بہت اچھے ملے ہیں اے صباؔ
حمدِ باری کر کے ہوتی ہے ثنائے مصطفیٰ
صبا اکبر آبادی کے نعتیہ مجموعۂ کلام ”دستِ دعا“ کا انتساب ”اذانِ بلال“ کے نام ہے۔ گویا ایک عاشق کا دوسرے عاشق کو خراجِ عقیدت۔ صبا صاحب کے لیے نعت محض صنفِ سخن نہ تھی آپ کے دل کی لگی اور وہ طلب تھی جس میں تڑپ ہی تڑپ تھی۔
رثائی ادب کی تخلیق میں صبا اکبر آبادی کی اصحابِ اہلِ بیت سے حقیقی محبت اور عقیدت کے تمام رنگ نمایاں ہیں۔
1936ء میں تخلیق کیا جانے والا صباؔ صاحب کا پہلا مرثیہ ”شکستِ یزید“ آپ کے جذبۂ ایمانی کی شدت اور قوت کی دلیل ہی نہیں مرثیہ نگاری کا نقطۂ آغازبھی تھا۔ جوش ؔملیح آبادی نے آپ کے مرثیوں کے بارے میں کہا تھا کہ ”صباؔ کے مرثیے سُن کر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ گویا میر انیسؔ کی روح بول رہی ہے۔“ مرثیوں پر مبنی آپ کے شعری مجموعے ذکر و فکر، سر بکف، خونناب، قرطاسِ الم، شہادت شائع ہو چکے ہیں۔
رباعی کی صنف پر صبا صاحب کو کمال دسترس تھی۔ آپ نے کئی موضوعات پر رباعیاں تخلیق کیں۔ یہی نہیں اپنی ترجمہ کی صلاحیت کو اپنی رباعیات میں بڑی چابک دستی سے بروئے کار لاتے ہوئے حضرت امیر خسروؔ، حافظؔ شیرازی، خیامؔ اور غالبؔ کی تمام رباعیات کا اُردو میں ترجمہ کیا۔ ڈاکٹر جمیل جالبی رقم طراز ہیں، ”اگر غالبؔ بھی اپنی رباعیات کا اُردو ترجمہ کرتے تو بالکل ایسا ہی ترجمہ کرتے جیسا کہ صبا ؔصاحب نے کیا ہے۔“
تضمین صبا ؔصاحب کی اعلیٰ شعری کاوش اور ”تضمینِ دیوانِ غالب“ ان کے شعری سفر کا بے مثال ادبی کارنامہ ہے جس کا آغاز 1938ء میں ہُوا اور اسی سال اس کی تکمیل ہوئی۔
زمزمۂ پاکستان کے نام سے آپ کی چار قومی و ملّی نظموں پر مشتمل پہلا مجموعہ 1945ء اور دوسرا مجموعہ 1946ء میں شائع ہوا۔ زمزمۂ پاکستان کو یہ امتیاز حاصل ہے کہ یہ پہلی کتاب ہے جس کا انتساب بانی پاکستان قائدِ اعظم محمد علی جناح کے نام ہے۔ پہلی مرتبہ اردو شاعری کا کوئی مجموعہ ساٹھ ہزار کی تعداد میں شائع ہوا اور فروخت کے بعد ملنے والی تمام رقم قائدِ اعظم کی موجودگی میں مسلم لیگ کے فنڈ کے لیے لیاقت علی خان کو پیش کی گئی۔ ڈاکٹر اسلم ؔفرخی تحریر کرتے ہیں کہ ”زمزمۂ پاکستان“ اپنے ادبی حسن، جوش اور ولولے کی وجہ سے بھی اہم ہے اور تحریکِ پاکستان کی تاریخ سے وابستگی کی بنا پر یہ قومی تاریخ کا جزو بن گئی۔“
صبا اکبر آبادی کی غزل میں اگر ایک جانب آپ کا طرزِ فکر اپنے پورے شعور کے ساتھ نمایاں ہے تو دوسری جانب احساس کی شدت، الفاظ کی ندرت اور غنائیت کا حسن بھی موجود ہے۔
چمن میں پھول کھلے ہیں بہار آئی ہے
ہمارے زخمِ محبت کی رونمائی ہے
یہ ایک داغِ محبت کہاں چھپا رکھوں
تمام عمر کا حاصل ہے کیا کیا جائے
بس ذرا مہلتِ تخیل میسر آجائے
کوئی مشکل ہے بیاباں کو گلستاں کرنا
صبا صاحب کی غزلوں پر مشتمل تین شعری مجموعے اوراقِ گل، چراغِ بہار اور ثبات شائع ہو چکے ہیں۔ ان کا ادبی سفر محض شاعری تک محدود نہ تھا بلکہ نثری ادب اور صحافت میں بھی انھوں نے اپنی خداداد صلاحیتوں سے خوب خوب کام لیا اور مولانا ابوالفرح کے قلمی نام سے کئی طنزیہ مزاحیہ اور سنجیدہ نوعیت کے مضامین سپردِ قلم کیے۔ 1991ء میں صبا اکبر آبادی آج ہی کے دن اس دارِ فانی سے ہمیشہ کے لیے رخصت ہوئے۔
یہاں ہم ایک تعزیتی خط نقل کررہے ہیں جو ڈاکٹر الیاس عشقی صبا صاحب کے سانحۂ ارتحال پر ان کے بیٹے جمیل نسیم کے نام ارسال کیا تھا۔ جمیل نسیم نے اسے اپنی کتاب میں شامل کرتے ہوئے لکھا ہے کہ عشقی صاحب کا خط سب سے الگ سب سے منفرد جیسے کوئی گلے لگا کر تسلی دے رہا ہو۔ ملاحظہ کیجیے۔
برادرم سلطان جمیل نسیم!
السلام علیکم!
ایسا خط بھی تم کو لکھنا پڑے گا اس کا خیال تک کبھی نہ آیا تھا۔ دو دن سے سوچ رہا تھا کیا لکھوں، لفظ نہیں ملتے۔ وہ لفظ جن میں اثر ہو اور جن سے تم کو اور سب گھر والوں کو سکون ملے صبر آ جائے۔ خود مجھے اپنی حالت دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ تمہارا حال کیا ہو گا۔ صبا صاحب میرے بزرگ تھے، تمہارے والد تھے۔ یہ خبر سنی تو اس وقت کئی لوگ موجود تھے کسی طرح ضبط کر لیا۔ تنہائی میں رویا اس محبت اور مروت کو جو اب میسر نہ ہو گی۔ جس دن کے تصور سے بھی خوف آتا تھا وہ گزر گیا۔ صبا صاحب کے چلے جانے سے والد کا غم بھی تازہ ہو گیا کہ محبت اور وضع داری میں یہ سب لوگ فردِ واحد کی طرح تھے۔
صبا صاحب کی موت نے ہم کو غریب کر دیا ہے۔ ایک شخص کی موت، ایک بڑے شاعر کی موت نے۔ ایک غزل گو، مرثیہ اور سلام نگار، نعت گو، تضمین نگار، رباعی گو، مترجم، نثر نگار، خاکہ نگار، مدیر اور ایسے انسان کو ہم سے چھین لیا جس کا ظاہر و باطن ایک تھا۔ رندِ پاکباز، مومنِ صادق، محفل آراء اب ان جیسا کون ہو گا۔ ان کی آواز کانوں میں گونج رہی ہے اور چہرہ آنکھوں کے سامنے ہے۔ ایسے لوگ دنیا میں کہاں ہوتے ہیں جن سے دور رہ کر بھی قرب کا احساس رہتا تھا کیسی محرومی ہے۔ ہائے۔
بات رسمی ہے مگر رسمی بات کی طرح نہیں کہہ رہا کہ صبر کرو اور سب کو صبر کی تلقین کرو۔ مناسب الفاظ میں تاجدار کو میری طرف سے پرسا دو کہ غم تو زندگی بھر کا ہے، یاد آتے رہیں گے مگر اب ان سے صرف دعا کا رشتہ باقی ہے۔ اس سے غافل نہ رہنا کہ اس سے دل کو سکون بھی ملتا ہے۔
تمہارا بھائی
الیاس عشقی 4 نومبر 1991ء
(شائستہ زریں کی تحریر)