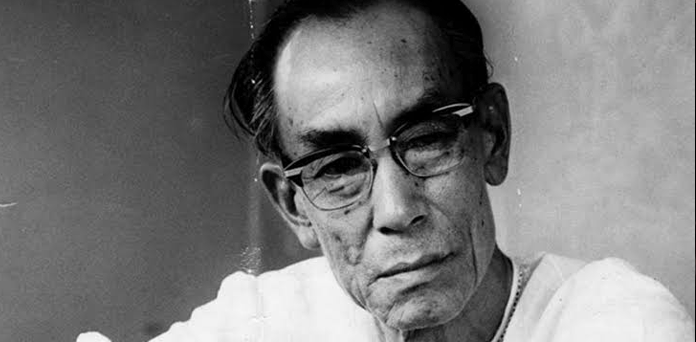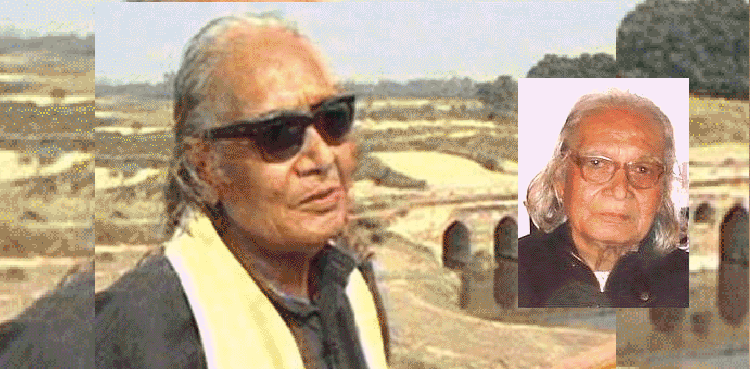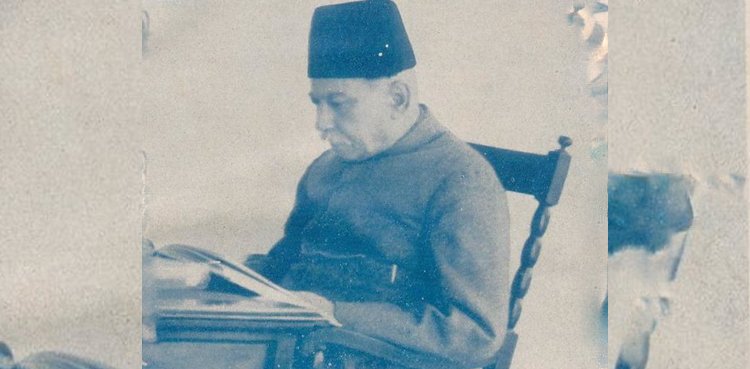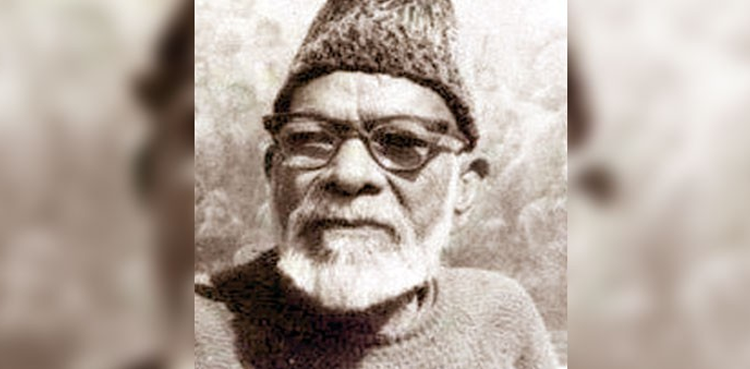اگر ہندوستان کی فلمی صنعت کے چند باکمال اور بے مثال موسیقاروں کا نام لیا جائے تو ان میں نوشاد، او پی نیر، کھیم چند پرکاش، سی رام چندر، انیل بسواس، شنکر جے کشن، سلیل چودھری، لکشمی کانت پیارے لال اور ایس ڈی برمن اس فہرست میں ضرور شامل ہوں گے۔
یہ تذکرہ ہے سچن دیو برمن (ایس ڈی برمن) کا جو ہندوستان کی فلم انڈسٹری کا ایک بڑا نام اور اپنے وقت کے عظیم سنگیت کار تھے۔ ایس ڈی برمن 1975ء میں آج ہی کے روز چل بسے تھے۔ موسیقار ایس ڈی برمن کے فلمی گیتوں کو آج بھی بہت شوق سے سنا جاتا ہے اور خاص طور پر موسیقار اور اس فن کی باریکیوں کو سمجھنے والے ایس ڈی برمن کے کمالِ فن کا اعتراف کرتے نظر آتے ہیں۔
موسیقار ایس ڈی برمن کی دھنوں میں مقبول ہونے والے کئی فلمی گیت ایسے تھے جن کو فلم کی کام یابی کی بڑی وجہ قرار دیا گیا۔ ایس ڈی برمن کی وجہ سے کئی نغمہ نگاروں اور گلوکاروں کو مقبولیت حاصل ہوئی۔ موسیقار ایس ڈی برمن کو بھارتی فلمی صنعت کا اہم ستون بھی کہا جاتا ہے۔
ایس ڈی برمن کا تعلق بنگال سے تھا۔ وہ یکم اکتوبر 1906ء کو پیدا ہوئے۔ ایس ڈی برمن تری پورہ کے شاہی خاندان کے رکن تھے۔ ان کا فلمی دنیا میں سفر 1937ء میں بنگالی فلموں سے شروع ہوا اور مجموعی طور پر ایس ڈی برمن نے سو ہندی اور بنگالی فلموں کی موسیقی ترتیب دی۔ وہ ایک ورسٹائل موسیقار مشہور تھے۔ ایس ڈی برمن نے موسیقی کے ساتھ گلوکاری بھی کی اور کئی بنگالی لوک گیت گائے۔ ان کی ترتیب دی ہوئی موسیقی پر لتا منگیشکر، محمد رفیع، گیتا دت، منّا ڈے، کشور کمار، آشا بھوسلے، شمشاد بیگم، مکیش اور طلعت محمود جیسے گلوکاروں نے اپنی آواز کا جادو جگایا اور خوب شہرت حاصل کی۔
ابتدائی تعلیمی درجات طے کرنے کے بعد ایس ڈی برمن نے میٹرک کا امتحان پاس کیا اور پھر وہ کومیلا کے وکٹوریہ کالج سے 1924ء میں بی اے کی سند لینے میں کام یاب ہوگئے، مگر موسیقی کے شوق نے ان کو آگے پڑھنے نہ دیا۔ ایس ڈی برمن ایم اے نہ کر سکے اور 1925ء سے 1930ء تک موسیقار کے سی ڈے سے موسیقی کی تربیت حاصل کرتے رہے۔ بعد میں بشما دیو، خلیفہ بادل خان اور استاد علاءُ الدین خان سے بھی راہ نمائی لی۔ ایس ڈی برمن نے 1920ء کی دہائی کے آخر میں کلکتہ ریڈیو اسٹیشن پر کچھ عرصہ گلوکاری بھی کی اور آہستہ آہستہ ان کی موسیقی مقبولیت حاصل کرنے لگی۔ یہ موسیقی بنگالی لوک دھنوں اور لائٹ ہندوستانی کلاسیکی موسیقی کا بڑا شان دار امتزاج تھی۔ ایس ڈی برمن کا ریکارڈ 1932ء میں پہلی مرتبہ ریلیز ہوا۔ اس کے بعد وہ گلوکار کی حیثیت سے پہچانے گئے اور کئی بنگالی گانے گائے۔ 1934 میں ایس ڈی برمن نے الہٰ آباد یونیورسٹی کی دعوت پر آل انڈیا میوزک کانفرنس میں شرکت کی جہاں انھوں نے بنگالی ٹھمری پیش کی۔ اس کانفرنس میں وجے لکشمی پنڈت اور کیرانہ گھرانے کے عبدالکریم خان بھی موجود تھے۔ اسی سال انھوں نے بنگال میوزک کانفرنس کلکتہ میں شرکت کی۔ اس کانفرنس کا افتتاح رابندر ناتھ ٹیگور نے کیا تھا۔ یہاں بھی انھوں نے بنگالی ٹھمری گائی اور گولڈ میڈل حاصل کیا۔
40ء کی دہائی میں ایس ڈی برمن نے بنگالی فلموں کے لیے بطور موسیقار کام کیا اور پھر ممبئی چلے گئے اور وہاں بھی بطور موسیقار کام شروع کیا۔ لیکن ان کی شہرت کا سفر 1947ء میں شروع ہوا جب فلم ’’دو بھائی‘‘ کا یہ گیت مقبول ہوا ’’میرا سندر سپنا بیت گیا‘‘۔ اس کے بعد انھوں نے فلم ’’شبنم‘‘ کی موسیقی ترتیب دی۔ ان کے چند یادگار گیتوں میں کھویا کھویا چاند ہے، دیوانہ مستانہ ہوا دل، آج پھر جینے کی تمنا ہے شامل ہیں۔
ایس ڈی برمن نے میرا داس گپتا سے شادی کی، اور ان کا بیٹا راہول دیو برمن (آر ڈی برمن) بھی موسیقار بنا اور اس دنیا میں بے پناہ شہرت اور مقبولیت حاصل کی۔