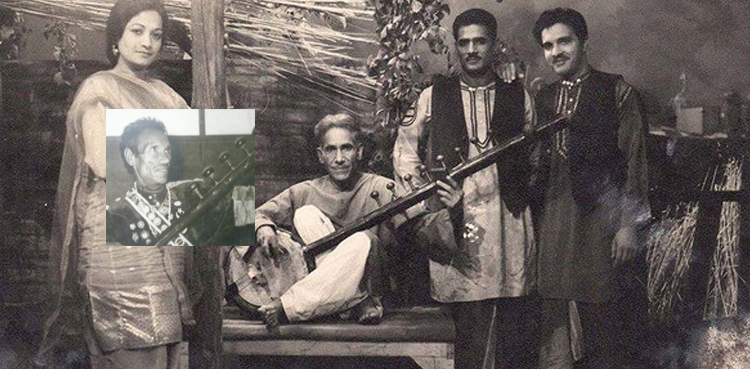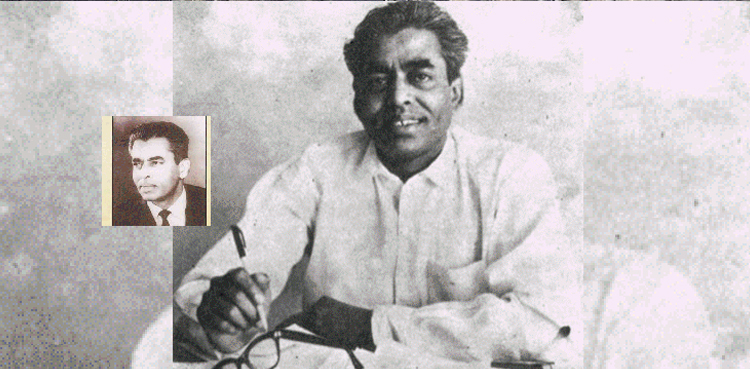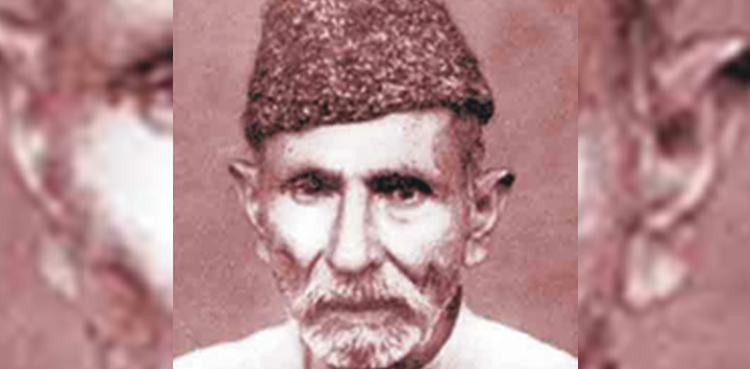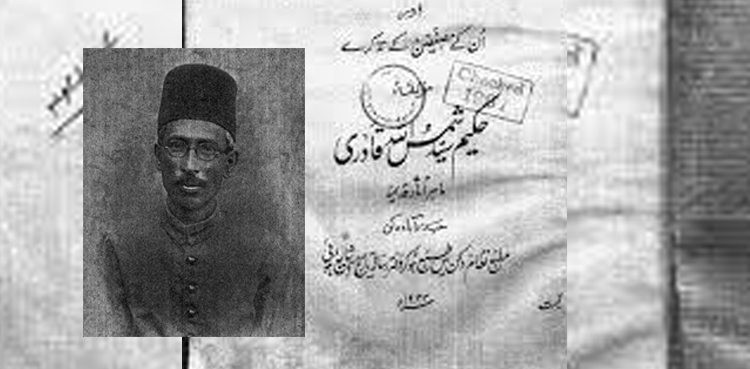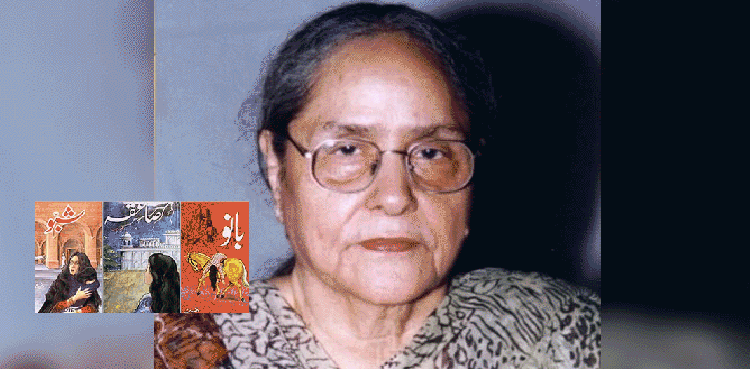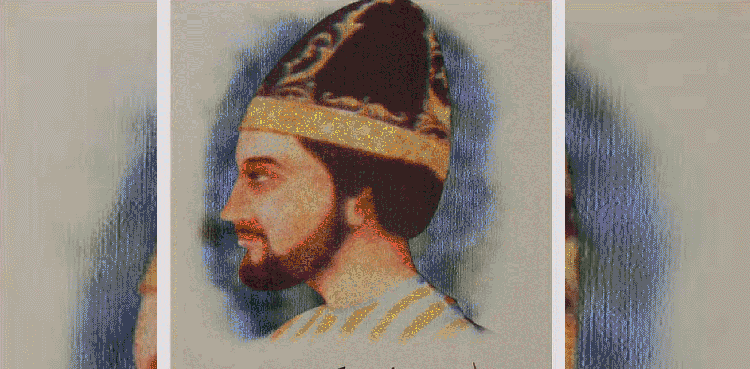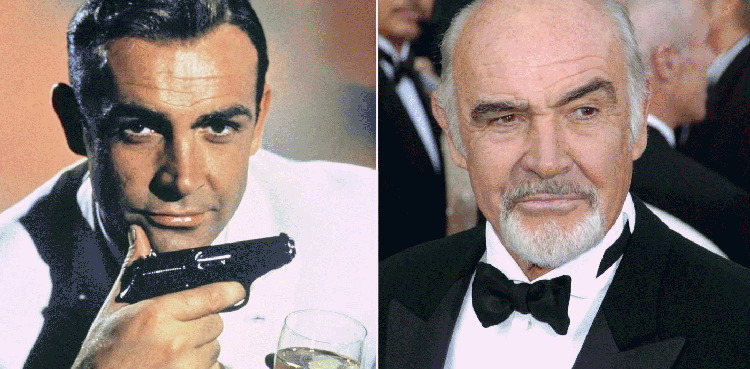برصغیر پاک و ہند میں لوک موسیقی اور فن کاروں کے بارے میں اب صرف کتابوں میں پڑھا جاسکتا ہے اور قدیم روایتی سازوں کو میوزیم میں ایک یادگار کے طور پر ہی دیکھا جاسکتا ہے۔ سائیں مرنا کا نام بھی رفتگاں کے تذکرے میں اکتارہ کو بڑی نفاست اور مہارت سے حرکت دے کر سماں باندھ دینے کے لیے محفوظ ہے۔ وہ پاکستان میں لوک موسیقی اور ساز و انداز کی دنیا کے ایک باکمال تھے جن کی آج برسی منائی جارہی ہے۔
سائیں مرنا کو اکتارہ جیسے روایتی ساز نے ملک گیر شہرت عطا کی تھی۔ ان کا انتقال 27 اکتوبر 1961ء کو ہوا تھا۔ سائیں مرنا کا اصل نام تاج الدّین تھا۔ وہ 1910ء میں امرتسر کے ایک گاؤں میں پیدا ہوئے تھے۔ مشہور ہے کہ سائیں مرنا نے عشق میں ناکامی کے بعد اکتارہ کو غمِ جاناں اور تنہائی کا کرب مٹانے کے لیے اپنا لیا تھا۔ وہ فقط سازندے نہیں تھے بلکہ اس ساز میں انھوں نے اختراعات بھی کیں اور اسے وچتر وینا کی طرح بجانے لگے۔ اکتارہ بجانے میں ان کو وہ کمال حاصل ہوا کہ سائیں مرنا ملک بھر میں پہچانے گئے۔
1946ء میں سائیں مرنا کو ریڈیو، لاہور پر پہلی مرتبہ اکتارہ بجانے کا موقع ملا تھا۔ انھیں ریڈیو تک پہنچانے والے محمود نظامی تھے اور ان کی بدولت سائیں مرنا کا فن دنیا کے سامنے آیا۔ اس سے پہلے سائیں مرنا بس اسٹاپوں اور میلوں ٹھیلوں میں اکتارا بجا کر لوگوں کو محظوظ کرتے تھے۔ سائیں مرنا اکثر بزرگانِ دین کے مزارات خصوصاً حضرت داتا گنج بخشؒ کے مزار پر بھی اکتارا بجاتے نظر آتے تھے۔ اس موقع پر جمع ہونے والے لوگ انھیں اپنی خوشی سے کچھ پیسے دے دیتے تھے اور یوں ان کا گزر بسر ہوتا تھا۔ وہ ایک باکمال اکتارا نواز تھے اور انھیں واقعی سننے والا مسحور ہو کر رہ جاتا تھا۔
کسی طرح وہ نظامی صاحب کی نظر میں آئے اور انھوں نے سائیں مرنا کو لاہور میں ریڈیو پر اپنے فن کا مظاہرہ کرنے پر آمادہ کر لیا۔ ریڈیو کے سامعین لوک موسیقی کے پروگرام بہت شوق سے سنتے تھے اور جب سائیں مرنا نے اس ساز کو بجایا تو ہر کوئی جھوم اٹھا۔ ان کی شہرت پورے پاکستان میں پھیل گئی۔ انہی دنوں ریڈیو پر آج کا آرٹسٹ کے نام سے نظامی صاحب نے موسیقی کا ایک پروگرام شروع کیا جس میں گلوکار، موسیقار یا کسی لوک فن کار کو مدعو کیا جاتا تھا۔ ایک مرتبہ سائیں مرنا کو بھی اس پروگرام کے لیے مدعو کیا گیا مگر وہ مقررہ دن ریڈیو اسٹیشن نہیں پہنچے اور پروڈیوسر نے وقت دیکھا تو گھبرا گیا۔ اس نے نظامی صاحب کو جا کر بتایا تو وہ بھی سر پکڑ کر بیٹھ گئے کیوں کہ سائیں مرنا کا کوئی ایک ٹھکانہ نہیں تھا۔ انھیں کہاں سے پکڑ کر لایا جاتا اور پروگرام کیا جاتا۔ اس دن کسی اور فن کار کو بلوا کر پروگرام نشر کر دیا گیا۔ دو دن بعد سائیں مرنا لاہور ریڈیو اسٹیشن پہنچے تو اسٹیشن ڈائریکٹر نے انھیں سخت باتیں کہہ دیں۔
اس ڈانٹ ڈپٹ نے سائیں کو آزردہ کردیا اور وہ بھی اب وہاں دوبارہ نہ آنے کا عہد کر کے پلٹ گئے۔ نظامی صاحب نے بعد میں انھیں کسی طرح منا لیا تھا مگر یہ بھی سچ تھا کہ وہ ایک فقیر منش اور سیدھے سادے انسان تھے اور یہ سمجھنا ان کے لیے مشکل تھا کہ وقت مقررہ پر پروگرام کی ریکارڈنگ یا اس کا نشر ہونا کتنا ضروری ہوتا ہے۔
یہ لوک فن کار جڑانوالہ، ضلع فیصل آباد کے ایک قبرستان میں آسودۂ خاک ہے۔ سائیں مرنا کے ساتھ ہی گویا یہ خوب صورت ساز اور اس کے وجود سے پھوٹنے والی ترنگ بھی ہمیشہ کے لیے دم توڑ گئی۔