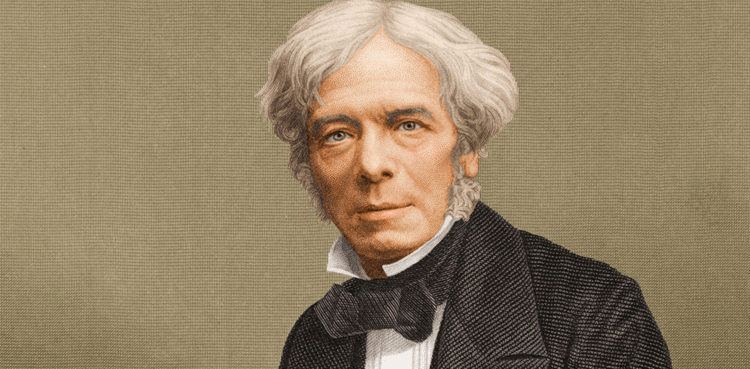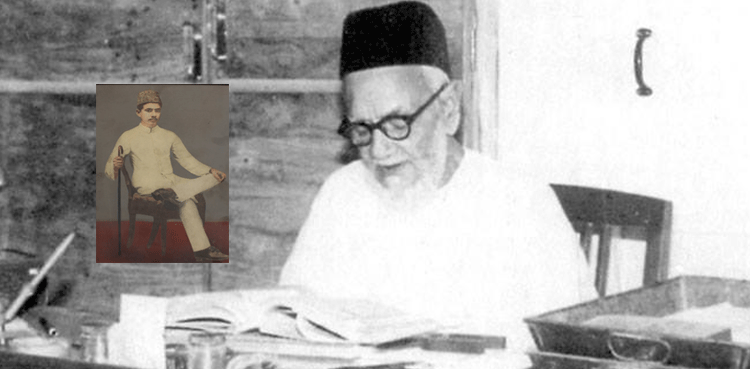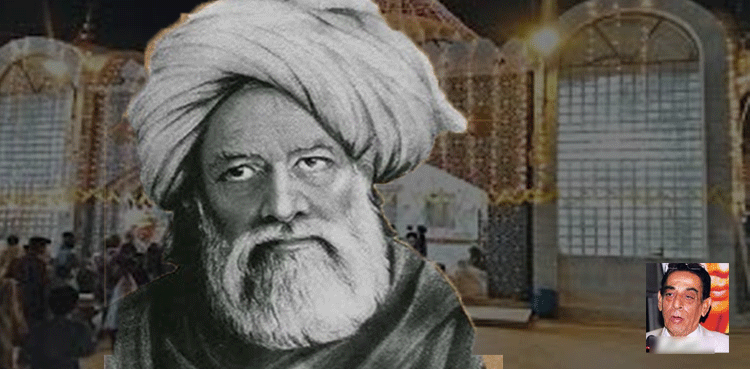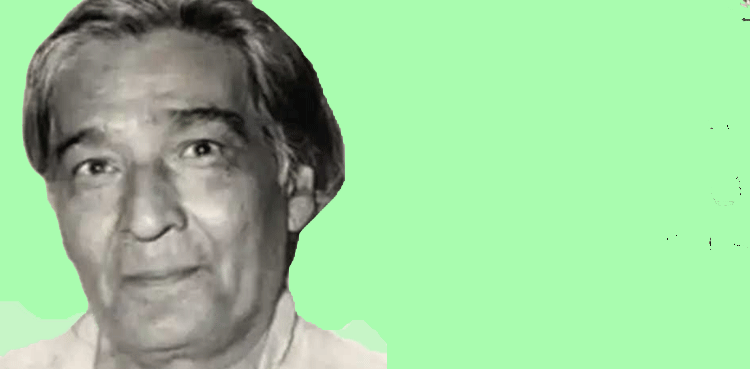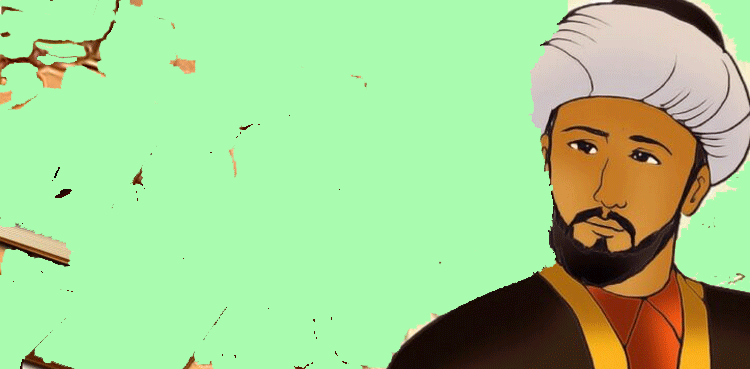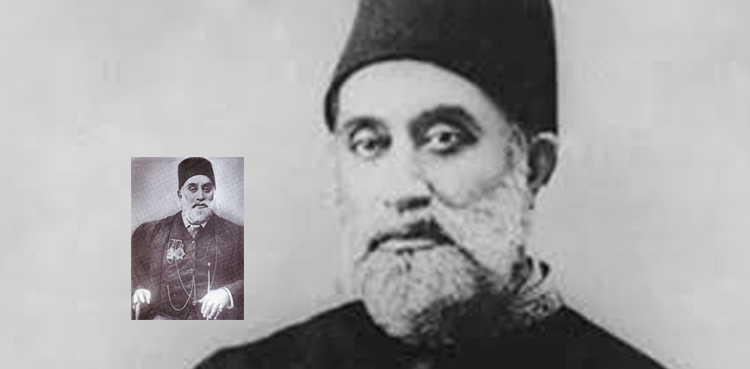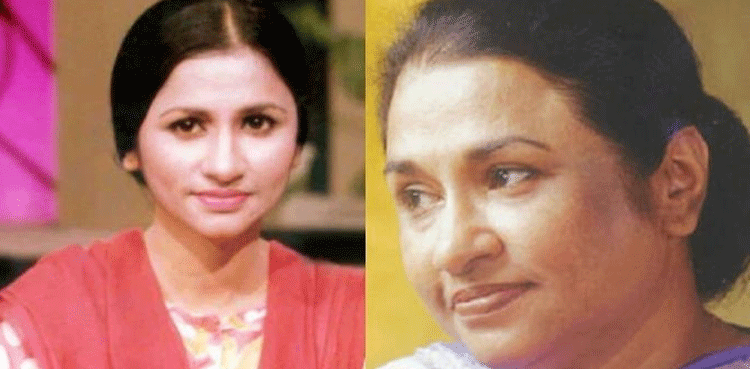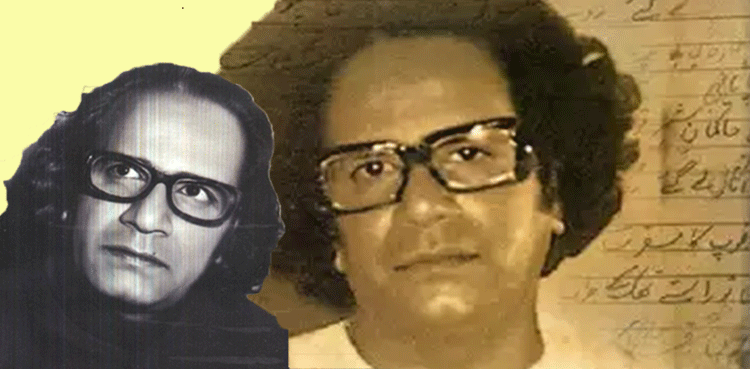حضرت بابا بلھے کو ہندوستان میں صوفی شاعر ہی نہیں صاحبِ کرامت شخصیت کے طور پر بھی پیش کیا جاتا ہے جن کا پیغام آفاقی جذبہ سے معمور اور بُلھے شاہ کا دربار بھی آفاقی فکر کا علم بردار ہے۔ ان کے عرس کے موقع پر ہر مذہب کو ماننے والے جمع ہوتے ہیں۔ بھانت بھانت کے عقائد اور فکر و خیال کے یہ لوگ یہاں روحانی سکون کی غرض سے اکٹھے ہوتے ہیں اور اسے روحانی سکون کا ذریعہ تصور کرتے ہیں۔
بلھے شاہ 22 اگست 1757ء کو اس دارِ بقا کی جانب لوٹ گئے تھے۔ آج ان کی برسی ہے۔ ممتاز پاکستانی شاعر، فکشن نگار، نقّاد اور تذکرہ و تحقیق پر مبنی کتب کے مصنّف انیس ناگی کا یہ مضمون بابا بلھے شاہ کی حیات اور ان کی شاعری پر معلوماتی اور نہایت مفید ہے۔ ملاحظہ کیجیے۔
حضرت بابا بلھے شاہ کی حیات کے بارے میں مصدقہ معلومات بہت کم دستیاب ہیں۔ ابھی تک جو باتیں اس کے بارے میں منظر عام پر آئی ہیں ان میں سے بیشتر کا تعلق زبانی روایت سے ہے۔ ان زبانی معلومات کا تعلق بھی حضرت بابا بلھے شاہ کی صوفیانہ زندگی اور کرامات سے ہے شاعری سے بہت کم ہے۔ ان کی زندگی کے بہت سے ایسے واقعات ہیں جن کو مختلف طریقوں سے بیان کیا گیا ہے۔ یہ معلومات جیسی کیسی بھی ہیں ان سے حضرت بلھے شاہ کی شخصیت کا ایک نقش قائم کیا جا سکتا ہے۔
حضرت بابا بلھے شاہ کی جیون کہانی میں تسلسل نہیں ہے، اس کمی کو قیاسات اور کہیں کہیں ان کی شاعری کے حوالے سے پورا کیا جا سکتا ہے۔ پرانے تذکروں میں خزینہ الاصفیا، نافع السالکین میں حضرت بلھے شاہ کے بارے میں چند ایک معلومات ہیں لیکن ان میں بھی تضاد ہے۔
حضرت بابا بلھے شاہ کے والد کا نام سخی شاہ محمد درویش تھا جن کا خاندانی سلسلہ شیخ عبدالقادر جیلانی سے جاملتا تھا۔ حضرت بلھے شاہ کے اجداد چوتھی صدی میں حلب سے ہجرت کرکے اُچ گیلانیاں میں آباد ہوگئے تھے۔ اُچ گیلانیاں بہاولپور کی تحصیل شجاع آباد کی سب تحصیل جلال پور پیر والا میں واقع ہے جو آج بھی اتنا ہی پسماندہ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت بلھے شاہ کے والد ایک متقی درویش تھے اور اچ گیلانیاں کی مسجد کے امام تھے۔
روایت ہے کہ بعض برے حالات کی وجہ سے وہ اچ گیلانیاں سے نقل مکانی کر کے ملک وال چلے گئے۔ وہاں بھی ان کی درویشی اور صوفیانہ مسلک کی وجہ سے انہیں امام مسجد بنا دیا گیا۔ انہوں نے وہاں مذہبی اور روحانی تعلیمات کا سلسلہ شروع کیا۔ روایت ہے کہ موضع پانڈو کے کا ایک بڑا زمیندار پانڈو خان جس کی بیٹی ملک وال میں بیاہی ہوئی تھی وہ ملک وال میں حضرت بلھے شاہ کے والد سید سخی سے ملا۔ ان کی پرہیز گاری اور معزز شخصیت سے متاثر ہوکر ان سے درخواست کی کہ وہ موضع پانڈو کے مسجد کے امام بن جائیں کیونکہ وہاں کوئی سید نہیں ہے۔ پانڈو خاں کی اس فرمائش پر حضرت بلھے شاہ کے والد پانڈو کے میں مع خاندان کے منتقل ہوگئے۔ کچھ کا خیال ہے کہ حضرت بلھے شاہ کی پیدائش اچ گیلانیاں میں ہوئی تھی جبکہ دوسرے یہ اصرار کرتے ہیں کہ حضرت بلھے شاہ کی پیدائش پانڈو کے میں ہوئی تھی۔ یہ بات زیادہ قرین قیاس معلوم ہوتی ہے کیونکہ حضرت بلھے شاہ کے مرشد حضرت شاہ عنایت نے ایک کتاب نافع السالکین مرتب کی تھی جس میں بلھے شاہ کے بارے میں قدرے تفصیلی نوٹ ہے جس کے مطابق حضرت بلھے شاہ کی پیدائش اچ گیلانیاں میں ہوئی تھیں۔ حضرت عنایت شاہ سے حضرت بلھے شاہ کا تعلق بہت قریبی تھا اس لئے ان کے ورژن کو قبول کرنے میں کوئی تعرض نہیں ہونا چاہئے۔
اسی قسم کا ابہام حضرت بلھے شاہ کے سال پیدائش کے بارے میں بھی ہے۔ کسی نے تاریخ کا حتمی تعین نہیں کیا…. خزینہ الاصفیا 1858 میں شائع ہوئی تھی، اس کے مصنف مفتی غلام سرور لاہوری نے حضرت بلھے شاہ کے حالات کے بیانات میں ان کی تاریخ پیدائش کے بارے میں خاموشی اختیار کی ہے لیکن 1750 ان کا سن وفات بتایا ہے۔ سب سے پہلے ایک انگریز افسر سی ایف آسبورن نے حضرت بلھے شاہ کی زندگی اور شاعری پر ایک کتابچہ جس میں ان کا سن پیدائش 1680 اور سن وفات1753 بتائی ہے۔ کلیات بلھے شاہ کے مرتب ڈاکٹر فقیر محمد فقیر اس کے دیباچے میں لکھتے ہیں ” بلھے شاہ تے پمفلٹ دے منصف مسٹر آسبورن نیں اوہدی تاریخ پیدائش 1680 تے تاریخ وفات 1785 لخی اے ایس حساب نال اوہدی عمر اک سوپنج ورہے بن دی اے پر آسبورن صاحب کول ایس دعوے دا کوئی ثبوت نہیں“۔
فقیر احمد فقیر نے اوسبورن کا اصل انگریزی متن نہیں دیکھا کیونکہ اصل متن میں حضرت بلھے شاہ کا سن وفات 1753 لکھا ہے جس کے مطابق حضرت بلھے شاہ کی عمر 78 سال بنتی ہے۔
جہاں تک حضرت بلھے شاہ کی جائے پیدائش کا تعلق ہے اس بارے میں دو ورژن ہیں۔ اوسبورن اور لاجونتی راما کرشنا کے نزدیک بلھے شاہ پانڈو کے میں پیدا ہوا تھا۔ پانڈو کے میں بلھے شاہ کے ڈیرے پر قابض 103 سالہ متولی درباری بیانی ہے کہ اس کے اجداد بلھے شاہ کے والد سخی شاہ کے مرید تھے وہ جھنگ کے رہنے والے تھے۔ ان کی حضرت بلھے شاہ کے والد سے ملاقات ملک وال میں ہوئی تھی، وہ پشت در پشت بلھے شاہ کے خاندان سے منسلک رہے ہیں پہلے وہ قصور میں حضرت بلھے شاہ کے مزارکے مجاور تھے جہاں سے محکمہ اوقاف نے انہیں بے دخل کردیا تھا اور وہ وہاں سے پانڈو کے آگئے تھے۔اس نے بڑے وثوق سے بتایا کہ اس کی خاندانی روایت کے مطابق حضرت بلھے شاہ اس کی دو بہنوں کی ولادت پانڈو کے میں ہوئی تھی۔ اس نے حضرت بلھے شاہ کی ابتدائی زندگی کی کرامتوں کو پانڈو کے کے حوالے سے بیان کیا جبکہ یہی باتیں اُچ گیلانیاں کے حوالے سے بھی بیان کی جاتی ہیں۔
پانڈو کے لاہور سے 28 کلو میٹردور قصور کی طرف جاتی ہوئی سڑک سے دائیں جانب چار پانچ کلو میٹر اندر واقع ایک چھوٹا سا گاﺅں ہے جو آج بھی اتنا ہی پسماندہ ہے جتنا حضرت بلھے شاہ کے زمانے میں ہوگا، آج بھی لوگ کھیتوں کی منڈیروں پر بیکار بیٹھے ہوتے ہیں یا نوجوان مویشی چراتے ہیں۔ گاﺅں کے وسط سے قدرے ہٹ کے حضرت بلھے شاہ کا موروثی گھر ہے جس کی شکل بدلی ہوئی ہے۔ ایک بڑا سا طویلہ ہے جسے دو تین کمروں میں تقسیم کیا گیا ہے اس میں 103 سالہ متولی درباری رہتا ہے جو بلھے شاہ کے خاندان کے بارے میں بہت سی کہانیاں بیان کرتا ہے جو اس نے بڑوں سے سنی تھیں۔
حضرت بلھے شاہ کی وجہ سے یہ گمنام قصبہ تاریخ کا ایک حصہ بن چکا ہے۔ اس کی اہمیت کی کئی ایک وجوہات ہیں۔ یہاں حضرت بلھے شاہ کی جوانی کا کچھ حصہ بسر ہوا تھا، یہاں وہ مسجد بھی موجود ہے جس کے امام حضرت بلھے شاہ کے والد تھے اور جس کی تعمیر پانڈو خاں نے کی تھی حضرت بلھے شاہ اور اس کی دونوں بہنوں نے شادی نہیں کی تھی اس لئے اس کے خاندان کا کوئی وارث نہیں ہے۔ پانڈو کے میں ایک چھوٹا سا عماراتی کمپلیکس ہے۔ قدرے بلند جگہ پر ایک بڑا سا ہال ہے جس کے اندر تین قبریں ہیں، درمیان کی قبر حضرت بلھے شاہ کے والدہ کی ہے جس کا نام فاطمہ بی بی تھا اس کے دائیں اور بائیں اس کی دو بہنوں صغراں بی بی اور سکینہ بی بی کی قبریں ہیں ۔حضرت بلھے شاہ کی مسجد کے عقبی جانب ایک سبز گنبد ہے جس کے نیچے بلھے شاہ کے والد دفن ہیں۔ اس سے ملحقہ پانڈو خاں کی مسجد ہے جس کے امام حضرت بلھے شاہ کے والد تھے۔ مسجد کے احاطے میں چھوٹی اینٹ کا بنا ہوا ایک خستہ سا کنواں ہے جو اب بھی جاری ہے۔
حضرت بلھے شاہ پانڈو کے کو پسند نہیں کرتے تھے۔ کہا جاتا ہے ایک اجنبی سکھ گھوڑے پر سوار پانڈو کے میں سے گزر رہا تھا کہ اہل دیہہ نے اعتراض کیا کہ وہ گھوڑے سے نیچے اتر کر گاﺅں میں سے گزرے۔ اس بات پر تکرار شروع ہوگئی حضرت بلھے شاہ نے مصالحت کرانے کی کوشش کی تو اہل دیہہ نے حضرت بلھے شاہ پر پتھراﺅ شروع کردیا، اس سکھ اور حضرت بلھے شاہ نے ایک قریبی گاﺅں دفتور کے گردوارے میں جان بچائی۔ بعد میں سکھوں نے پانڈوکے پر حملہ کر کے اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ اہل دیہہ نے حضرت بلھے شاہ کی منت سماجت کی کہ وہ اپنے گاﺅں واپس آجائیں لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔
حضرت بلھے شاہ نے اپنی ابتدائی تعلیم اپنے والد سے حاصل کی تھی جس کے بعد انہیں مزید تعلیم کیلئے قصور بھیج دیا گیا جہاں وہ اس علاقے کے مشہور عالم حافظ غلام مرتضیٰ کے شاگرد بن گئے جن سے حضرت بلھے شاہ نے مذہبی تعلیم کے علاوہ عربی فارسی اور تصوف کی تعلیم حاصل کی۔ حافظ غلام مرتضیٰ سے حضرت بلھے شاہ کے علاوہ وارث شاہ نے بھی تعلیم حاصل کی تھی۔ روایت ہے کہ حافظ غلام مرتضیٰ نے ان دونوں کے بارے میں کہا تھا۔
مجھے دو شاگرد عجیب ملے ہیں، ان میں ایک بلھے شاہ ہے جس نے علم حاصل کرنے کے بعد سارنگی ہاتھ میں پکڑ لی، دوسرا وارث شاہ ہے جو عالم بن کے ہیر رانجھا کے گیت گانے لگا۔
حضرت بلھے شاہ کا حقیقی نام سید عبداللہ شاہ تھا لیکن عرف عام میں وہ بلھے شاہ کے nick name سے جانے پہنچانے جاتے ہیں۔ پنجابی کلچر میں اصل ناموں سے عرف بنانا ایک عام سی بات ہے، بلھے شاہ نے یہ نام اپنے لئے خود تجویز کیا تھا یا ان کے جاننے والوں نے یہ نام رکھا تھا اس بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ اگر حضرت بلھے شاہ نے اپنی شاعری میں اسے ایک تخلص کے طور پر استعمال کیا۔اس کی ایک اور صوفیانہ تاویل کی جاسکتی ہے۔ بُھلا سے مراد بھولا ہوا بھی ہے، یعنی وہ اپنی ذات کو بھول چکا ہے۔ بلھے شاہ کا nick name اتنا مشہور ہوا کہ لوگ ان کے اصل نام سید عبداللہ شاہ کو بھول گئے ہیں۔
یہ معلوم نہیں کہ حضرت بلھے شاہ کتنا عرصہ قصور میں زیر تعلیم رہے اور وہ کب واپس اپنے گاﺅں گئے اور وہاں ان کی مصروفیات کیا تھیں۔ حضرت بلھے شاہ امام مسجد کے بیٹے تھے اور دن بھر وہ مویشی چراتے رہتے۔ حضرت بلھے شاہ نے کس عمر میں شاعری کا آغاز کیا اور ان کا روحانی سفر کس طرح شروع ہوا یہ حقائق پوشیدہ ہیں۔ حضرت بلھے شاہ کی شاعری میں بھی ان کی شخصی زندگی کے بارے میں کوئی اشارہ نہیں دیتی۔ اس صورتحال میں حضرت بلھے شاہ کی سوانح کو چند ایک حقائق اور بہت سے مفروضات اور قیاسات کے ذریعے ہی مکمل کیا جا سکتا ہے۔ حضرت بلھے شاہ کے بارے میں قصے کہانیوں میں بھی ان کی کرامتوں اور غیر معمولی روحانی طاقت کو اجاگر کیا گیا ہے۔ ان کی شاعری کے شارحین نے بھی ان کی شاعری کی وضاحت اسی نقطۂ نظرسے کی ہے۔
بلھے شاہ کی زندگی کے چند ایک واقعات کا بیان بھی ضروری ہے جن سے کم سے کم ان کی افتاد طبع کے بارے میں کچھ پتہ چلتا ہے۔ حضرت بلھے شاہ ایک حد تک erratic بھی تھے۔ وہ اپنے عہد کی زندگی سے منحرف تھے اور اس انحراف کی ایک وجہ شریعت سے دوری تھی، وہ اپنے عہدے کے مولویوں، پارساﺅں اور مفتیوں کا تمسخر اڑاتے تھے کہ انہوں نے منافقت کا لبادہ اوڑھا ہوا تھا، یوں لگتا ہے کہ حضرت بلھے شاہ اپنے گاﺅں یا شہر کے لوگوں کے تعصب، مذہبی رجعت پسندی اور منافقت سے کافی بیزار تھے۔ وہ نہ صرف پانڈو کی سے بلکہ قصور سے بھی ناخوش تھے۔
حضرت بلھے شاہ کا قصور کی ایک طوائف سے رقص سیکھنا پھر گوالیار کی ایک طوائف سے رقص کی تربیت حاصل کرنا، قصور کی ایک متمول بیوہ کا بلھے شاہ پر فریفتہ ہوتا، پھر ہیجڑوں کے ساتھ رقص کرنا، لاہور میں اچی مسجد کے باہر حضرت شاہ عنایت کے انتظار میں عورتوں کے کپڑے پہن کر عالم سکر میں رقص کرنا، گدھے خرید کر ان پر سوار ہو کر گاﺅں میں پھرنے کا مقصد لوگوں کو زچ کرنا تھا جو حضرت بلھے شاہ کو پسند نہیں کرتے تھے۔ وہ امام مسجد کے بیٹے تھے اور ان سے بہتر رویے کی توقع کی جاتی تھی۔ حضرت بلھے شاہ اپنے گاﺅں کے لوگوں کیلئے odd man out تھے۔ حضرت بلھے شاہ کے وقائع نگار اس کی زندگی کے ہر پہلو کو معجزہ یا کرامت ثابت کرنے کیلئے اسے انسانی خصائص سے محروم کر دیتے ہیں۔ حضرت بلھے شاہ کی حیات کے بارے میں بہت قلیل مواد کے باوجود ان کے بعض رجحانات کی نشاندہی کی جاسکتی ہے۔ حضرت بلھے شاہ ایک امام مسجد کی واحد نرینہ اولاد تھے۔ اس لئے اپنے باپ کی گدی سنبھالنی کوئی مشکل نہیں تھی لیکن وہ کسی اور راہ کے مسافر تھے۔
وہ مذہب کو اپنے وجدانی تجربے کے ذریعے دریافت کرنا چاہتے تھے۔ چنانچہ وہ ایک مرشد کی تلاش میں قصور چلے گئے۔ اس زمانے میں قصور کا حاکم ایک پٹھان نواب تھا جس کی بد اعمالیوں کی وجہ سے قصور ایک بے برکت شہر تھا جہاں بد امنی تھی۔ وہاں حضرت بلھے شاہ کس کام میں مصروف رہے اس کے بارے میں ان کی سوانح حیات خاموش ہے….
حضرت بلھے شاہ کی ابتدائی زندگی کے بارے میں جو واقعات ہم تک پہنچتے ہیں ان کے مطابق اس میں انسانی برابری، لوگوں کی مدد، طبیعت میں درویشی کے رجحانات نمایاں تھے۔ اسی ناطے ان کی ابتدائی کرامتوں کا ذکر بھی کیا جاتا ہے۔