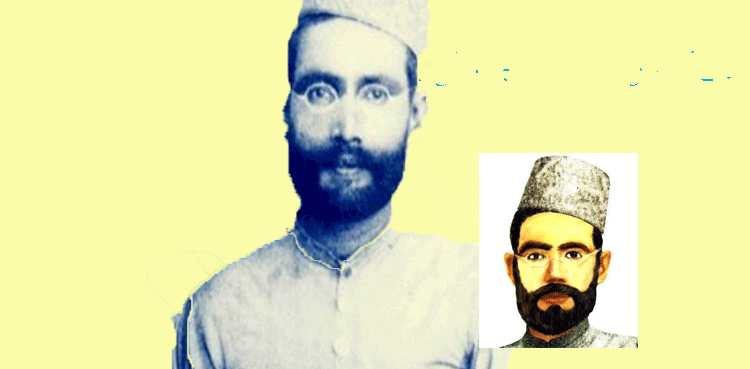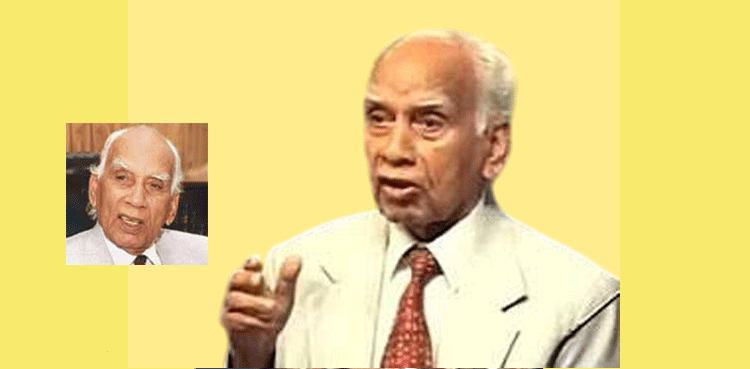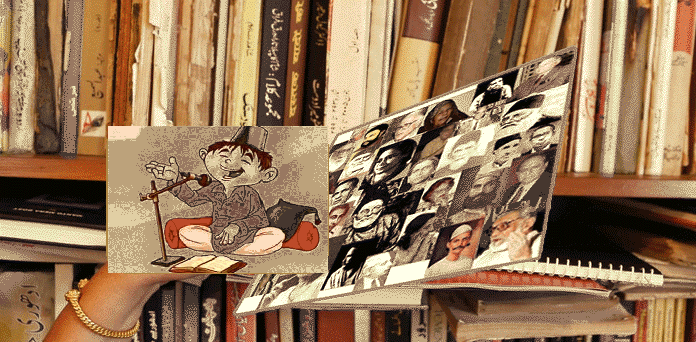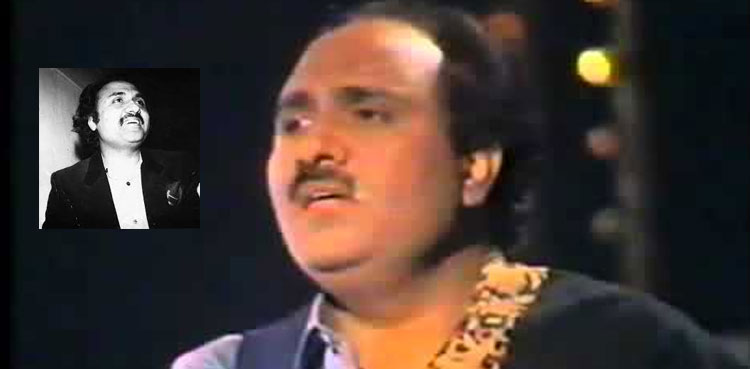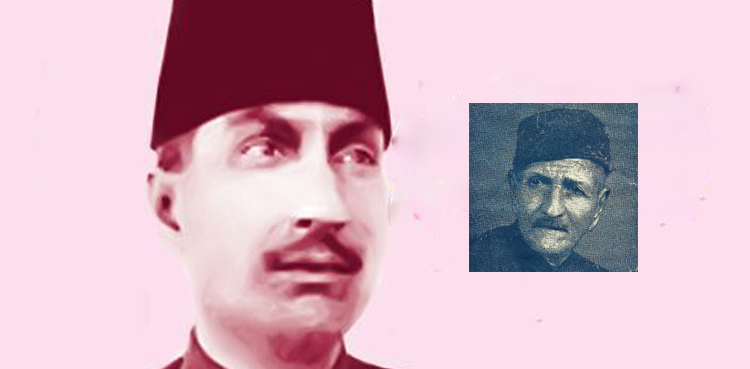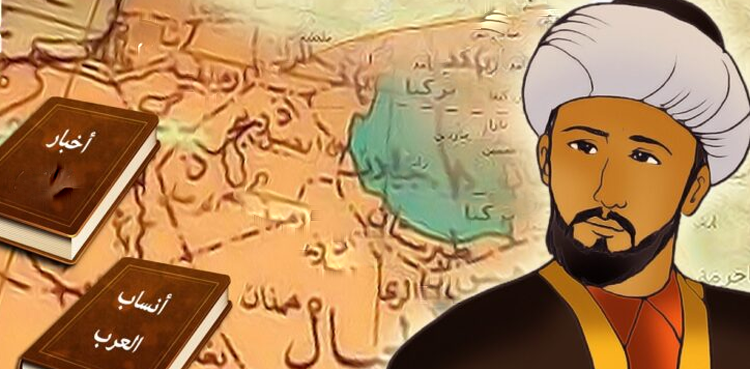1941ء میں آج ہی کے روز اردو کے نام وَر شاعر شوکت علی خان جو فانیؔ بدایونی کے نام سے مشہور ہیں، یہ دنیا چھوڑ گئے تھے۔ فانی بدایونی اپنی حزنیہ شاعری کے لیے مشہور ہیں۔ ان کا کلام ہجر کی وارداتوں، غمِ روزگار، رنج و الم کے موضوعات سے بھرا ہوا ہے۔
کہتے ہیں کہ فانیؔ نے اردو شاعری میں شدّتِ غم کو درجۂ کمال تک پہنچایا۔ وہ 1879ء میں پیدا ہوئے۔ اپنے شہر کی نسبت بدایونی کا لاحقہ استعمال کیا۔ ابتدائی تعلیم گھر پر حاصل کی اور بعد میں مکتب گئے۔ 1892ء میں گورنمنٹ اسکول میں داخلہ لیا اور انٹرنس کا امتحان پاس کرنے کے بعد بی اے کی ڈگری حاصل کی۔ فانی نے گیارہ بارہ سال کی عمر میں شاعری شروع کر دی تھی۔
کالج کے زمانے میں شغل جاری رہا اور احباب و مختلف حلقوں میں کلام سنانے لگے۔ بعد میں وکالت پڑھ کر لکھنؤ میں پریکٹس کرنے لگے، لیکن پھر والد اور چند اعزّہ کے انتقال کے بعد ان کا ہر کام سے گویا دل اچاٹ ہوگیا اور معاش کے حوالے سے تنگی کا سامنا رہنے لگا جس نے انھیں یاسیت کی طرف دھکیل دیا۔ اسی عرصے میں غمِ جاناں نے بھی آ گھیرا اور ناکامی کے بعد بری طرح ٹوٹ گئے۔
فانی نے شہر شہر کی خاک چھانی اور معاش کی خاطر جگہ جگہ قسمت آزماتے رہے۔ آخر فانی حیدر آباد دکن پہنچ گئے جہاں دربار سے اداروں تک عالم فاضل شخصیات کی قدر افزائی کی جاتی تھی اور نظام دکن کی جانب سے وظیفہ دیا جاتا تھا دکن میں فانی اچھے برے دن کاٹ کر دنیا سے چلے گئے۔
ممتاز نقاد اور ادیب آل احمد سرور ان کے بارے میں اپنے مضمون میں لکھتے ہیں:
"فانیؔ کے والد بڑے سخت گیر تھے۔ فانی کو اپنے پہلے عشق میں ناکامی ہوئی۔ ملازمت انہیں راس نہ آئی۔”
"ان کے والد ان کی شاعری کے بہت خلاف تھے۔ انہیں کچھ آزادی بریلی کالج میں ملی، مگر دراصل ان کی ادبی شخصیت علی گڑھ کے قیام کے زمانے میں بنی جب وہ حسرت اور ان کی اردوئے معلیٰ سے قریب آئے۔ انہوں نے ملازمت پر وکالت کو ترجیح دی جس طرح اقبالؔ نے دی۔ اقبالؔ کو بھی اپنا پیشہ پسند نہ تھا، مگر وہ فانیؔ سے زیادہ لطافت کی خاطر کثافت کو گوارا کر سکتے تھے۔ فانیؔ اچھے وکیل ہو سکتے تھے کیوں کہ وہ ذہین آدمی تھے، مگر ان کی شاعرانہ شخصیت ان پر اتنی حاوی ہو گئی تھی کہ وہ وکالت کے پیشے کی پستی اور زمانہ سازی گوارا نہ کر سکتے تھے۔ ایک شاہانہ انداز سے زندگی گزارنے میں انہیں لطف آتا تھا۔”
"کلکتے اور بمبئی کے سفر، لکھنؤ میں کچھ دن کے ٹھاٹھ، حیدرآباد میں شروع میں ان کی فضول خرچیاں، فانیؔ کے مزاج کے ایک خاص پہلو کو ظاہر کرتی ہیں۔”
"فانیؔ کو ادبی شہرت جلد حاصل ہو گئی اور آخر تک وہ معاصرین میں ممتاز رہے۔ لکھنؤ، اٹاوے، مین پوری علی گڑھ اور آگرے میں مشاعروں میں ان کی غزلیں حاصلِ مشاعرہ سمجھی جاتی تھیں جب کہ ان میں یگانہ، جگر جیسے قابلِ قدر شاعر بھی موجود ہوتے تھے۔ ان کی ادبی شہرت 1920ء سے شروع ہوئی اور 1930ء میں عروج کو پہنچ گئی۔”
"فانیؔ پُر گو نہ تھے۔ ماہر القادری کا بیان ہے کہ ان کی غزل کئی کئی دن میں مکمل ہوتی تھی۔ ان کے تمام دوستوں نے بیان کیا ہے کہ ان پر ایک استغراق کی کیفیت طاری رہتی تھی۔ ان کی مایوسیوں اور ناکامیوں، تلخیوں اور محرومیوں کی داستان ان کے چہرے پر لکھی ہوئی تھی۔”
"فانیؔ بہت پریشاں رہے مگر انہوں نے کبھی کسی سے ان پریشانیوں کا اظہار نہ کیا۔ جب وہ بدایوں میں اپنے ایک وسیع اور کشادہ مکان کو رہن رکھ رہے تھے تو ان کے ایک ملنے والے آگئے اور انہوں نے تازہ کلام کی فرمائش کی۔ فانیؔ نے انہیں اپنا ایک شعر یہ کہہ کر سنایا کہ آج ہی موزوں ہوا ہے۔”
اپنے دیوانے پہ اتمامِ کرم کر یارب
درو دیوار دیے اب انہیں ویرانی دے
"وہ اگرچہ ہنگامے سے گھبراتے تھے اور نمود و نمائش سے دور بھاگتے تھے مگر دوستوں کی محفل میں ہنستے بولتے بھی تھے۔ گو کسی نے انہیں قہقہہ لگاتے نہیں سنا۔ دوسروں کے کلام کی تعریف کرتے تھے مگر ان اشعار کی، جو انہیں پسند آتے تھے۔ جب ماہرُ القادری نے ان کی اس غزل کی تعریف کی جس کا مطلع ہے۔”
پھر فریبِ سادگی ہے رہ نمائے کوئے دوست
مٹنے والی آرزو ہی لے چلیں پھر سوئے دوست
تو کہنے لگے لیکن آتشؔ کے اس مصرع کا جواب کہاں
دل سوا شیشے سے نازک دل سے نازک خوئے دوست
"ماہر القادری نے ایک اور واقعہ کا ذکر کیا ہے۔ پڑوس میں ریڈیو تھا۔ کہیں سے کوئی مشاعرہ نشر ہورہا تھا۔ فانیؔ وہاں پہنچے۔ جگرؔ کی غزل سنی اور کئی اشعار پر رانوں پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا۔ ارے ظالم مار ڈالا۔ جب غزل ختم ہوئی تو اٹھ کھڑے ہوئے۔ لوگوں نے کہا مشاعرہ تو ابھی جاری ہے مگر وہ یہ کہتے ہوئے چلے ’’مشاعرہ تو ہو چکا۔‘‘ یہی نہیں کہ فانیؔ کے مزاج میں تعلی بالکل نہ تھی۔ وہ اس زمانے کے تہذیبی اور مجلسی آداب کے مطابق اپنے اور اپنے کلام کے متعلق ایسے انکسار سے کام لیتے تھے کہ آج کے ظاہر بین اس سے غلط فہمی میں مبتلا ہو جائیں تو تعجب کی بات نہ ہو گی۔”
"1922ء میں علی گڑھ میگزین کے ایڈیٹر رشید احمد صدیقی کو غزل کی فرمائش پر لکھا ہے، ’’میری بکواس نہ پڑھنے کے لائق ہے نہ سننے کے قابل۔ دامنِ اردو پر ایک بدنما داغ کے سوا کچھ نہیں۔ کوشش کیجیے کہ مٹ جائے۔ یہ آپ کا پہلا فرض ہے۔ میگزین کے بیش بہا صفحات پر میری غزل کا وجود باعثِ ننگ ہے۔ زبان اردو کے نادان دوست نہ بنیے۔’‘ یہ انکسار اس زمانے میں شرفاء کا دستور تھا۔ غالباً اس کے پیچھے یہ جذبہ تھا کہ اپنی تعریف آپ کرنا معیوب ہے۔ ہاں دوسرے تعریف کریں تو اور بات ہے۔”
فانی بدایونی کے کئی اشعار ضرب المثل کا درجہ رکھتے ہیں۔
ہر نفس عمرِ گزشتہ کی ہے میّت فانیؔ
زندگی نام ہے مر مر کے جیے جانے کا
یہ مقطع ان کی پیشِ نظر غزل کا حاصل ہے۔ اسی غزل میں ایک اور مقطع بھی شامل ہے جو بہت مشہور ہے، ملاحظہ کیجیے
اِک معما ہے سمجھنے کا نہ سمجھانے کا
زندگی کاہے کو ہے خواب ہے دیوانے کا
زندگی بھی تو پشیماں ہے یہاں لا کے مجھے
ڈھونڈتی ہے کوئی حیلہ مرے مَر جانے کا
ہڈیاں ہیں کئی لپٹی ہوئی زنجیروں میں
لیے جاتے ہیں جنازہ ترے دیوانے کا
ہم نے چھانی ہیں بہت دیر و حرم کی گلیاں
کہیں پایا نہ ٹھکانا ترے دیوانے کا
کہتے ہیں کیا ہی مزے کا ہے فسانہ فانیؔ
آپ کی جان سے دور آپ کے مر جانے کا