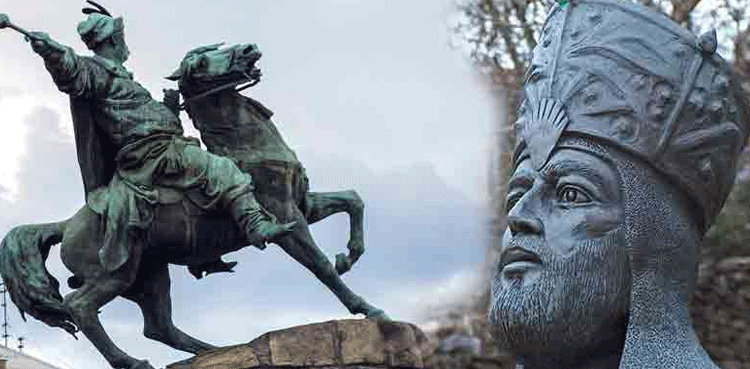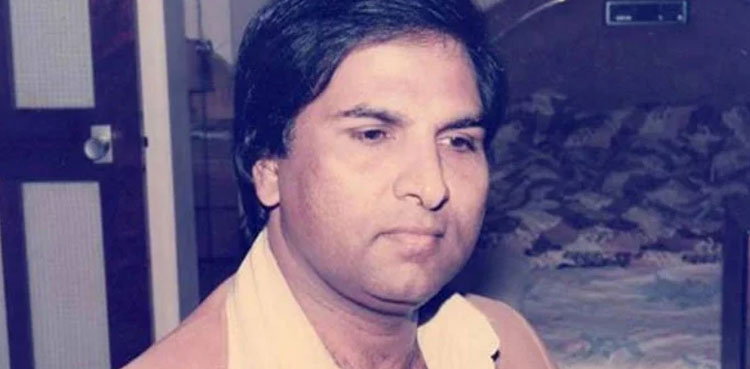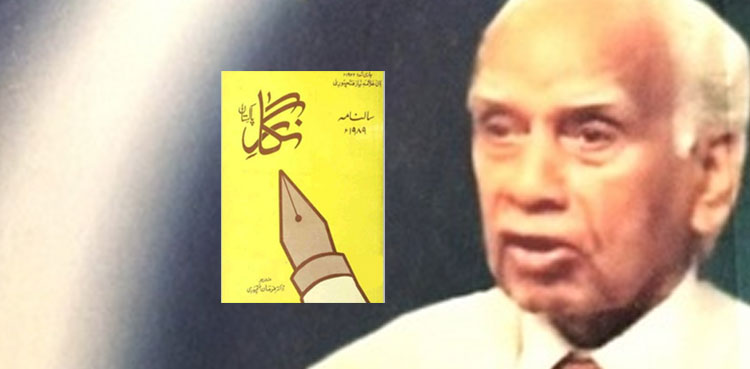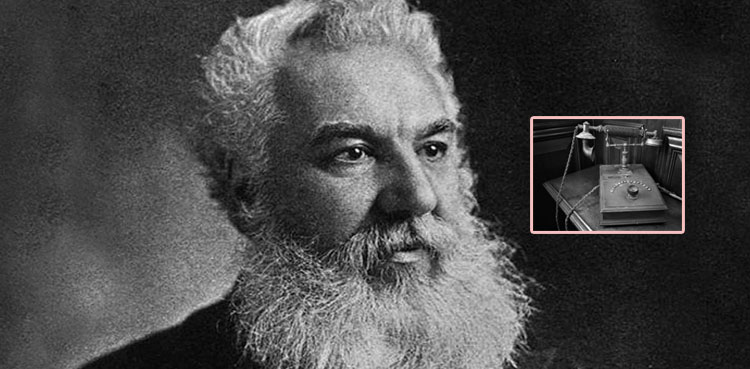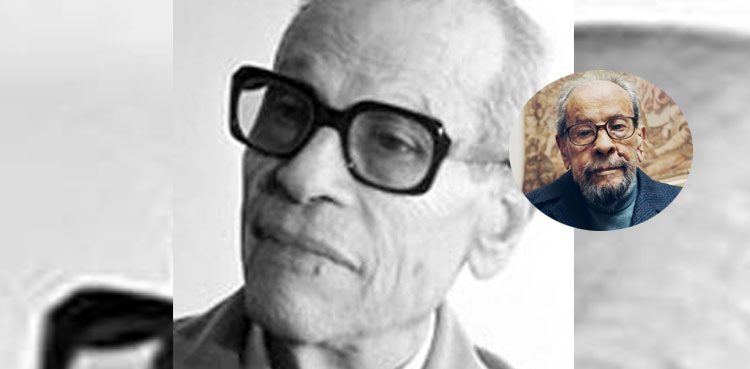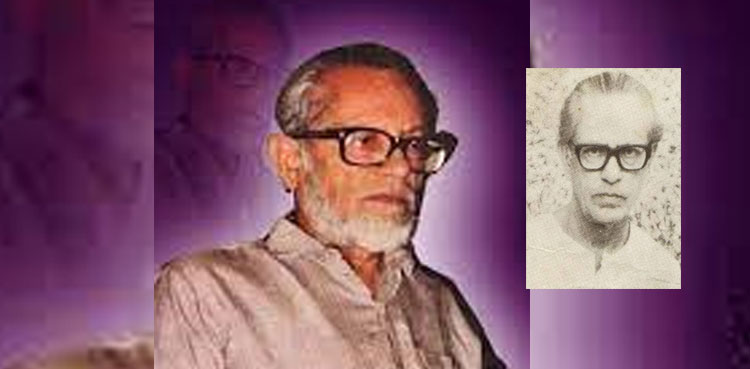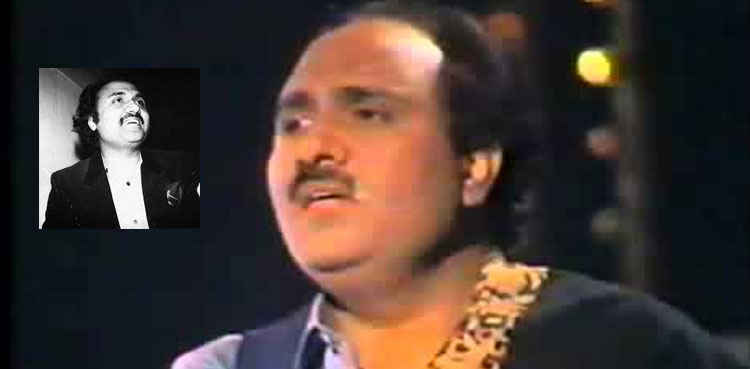محمد بن ابی عامر نے اندلس کی حکم رانی کا خواب اُس عمر میں دیکھا تھا جس میں ان کے ساتھی گپ شپ اور تفریحی مشاغل میں مصروف رہتے تھے۔ ماہ و سال کی گردش نے جب ان کے خواب کو حقیقت میں بدلا تو وہ محمد بن ابی عامر الحاجب المنصور کے نام سے مشہور ہوئے۔ وہ اندلس کے بہترین منتظم جب کہ عالمِ اسلام کے بہادر اور فاتح سپاہ سالار بنے۔
اندلس کی تاریخ کے اس فرماں روا کے بارے میں کم ہی پڑھنے کو ملتا ہے، لیکن کئی معتبر مؤرخین اور تذکرہ نویسوں کے علاوہ مشہور سیاحوں نے ان کے عہد کا مختصر احوال رقم کیا ہے۔ آج ان کا یومِ وفات ہے۔ محمد بن ابی عامر المنصور کے حالاتِ زندگی اور تخت سے فتوحات تک تفصیل میں جائیں تو ہمیں کئی روایات اور ان سے منسوب قصائص پڑھنے کو ملیں گے جن سے ان کی سیرت و کردار اور عہدِ حکم رانی کے بارے میں معلوم ہوتا ہے۔ آئیے حالاتِ زندگی سے انھیں جاننے کا آغاز کرتے ہیں۔
ان کا آبائی وطن جنوبی اسپین بتایا جاتا ہے جہاں انھوں نے ایک ساحلی شہر الخضرا کے متوسط گھرانے میں آنکھ کھولی تھی۔ مؤرخین کی اکثریت متفق ہے کہ ان کا سنِ پیدائش 937ء رہا ہوگا۔ ابن ابی عامر کے جدامجد کا نام عبدالمالک المعفری تھا جو اندلس کی پہلی فتح کے زمانے میں طارق بن زیاد کے سپاہیوں میں سے ایک تھا اور یہاں الخضرا کے قریب آباد ہوا تھا۔ اسی سپاہی کی آٹھویں نسل میں محمد بن ابی عامر پیدا ہوئے۔
ابتدائی تعلیم آبائی علاقے میں اس دور کے دستور کے مطابق مکمل کرکے مزید تعلیم حاصل کرنے کے لیے قرطبہ آنے والے محمد بن ابی عامر کو دورانِ تعلیم بڑا آدمی بننے کا شوق پیدا ہوا اور انھوں نے حاجبُ السّلطنت (وزیر اعظم) بننے کا خواب دیکھنا شروع کردیا۔ یہی نہیں بلکہ وہ سنجیدگی سے اس کے لیے منصوبہ بندی کرنے لگے کہ اس منصب پر فائز ہوکر کیسے ملکی معاملات کو سدھار سکتے ہیں۔ جب وہ یہ باتیں اپنے دوستوں سے کرتے تو وہ ان کا مذاق اڑاتے اور انھیں بے وقوف اور دیوانہ کہتے، لیکن ان کی یہ خواہش اور جستجو ختم نہ ہوئی۔ اس حوالے سے ایک روایت مختلف انداز سے بیان کی جاتی ہے جس میں سے ایک کچھ یوں ہے: قرطبہ کی مسجد میں محمد بن ابی عامر اور ان کے ساتھی اپنے اپنے مستقبل کے بارے میں بات کررہے تھے۔ ابن ابی عامر نے خود کو مستقبل میں سلطنت کا وزیرِاعظم بتایا تو دوست بے ساختہ ہنسنے لگے۔ ایک شوخ لڑکے نے طنزیہ شعر بھی چُست کر دیا۔ محمد بن ابی عامر کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ انھوں نے کہا: ’’یہ تو ہو کر ہی رہے گا۔ ابھی وقت ہے، اپنے لیے جو مانگنا ہے، مانگ لو‘‘۔ یہ سن کر ایک دوست نے استہزائیہ انداز میں کہا: ’’اے ابن ابی عامر! مجھے قاضی بننے کا شوق ہے، تم مجھے میرے آبائی شہر مالقہ کا قاضی بنا دینا۔‘‘ دوسرے نے پولیس کا اعلیٰ کا عہدہ مانگا۔ تیسرے نے کہا کہ مجھے شہر کے تمام باغات کا نگران بنا دینا۔ جس لڑکے نے طنزیہ شعر پڑھا تھا، اس نے حقارت سے کہا: ’’تمہاری اگلی سات نسلوں میں بھی کوئی وزیرِ اعظم بن گیا تو میرا منہ کالا کر کے گدھے پر شہر میں گشت کرانا۔‘‘ اور پھر لڑکا پچھتایا۔
ابن عامر نے قرطبہ سے قانون اور ادب کی تعلیم مکمل کرنے کے بعد اسی شہر کی کچہری میں بطور عرضی نویس کام شروع کر دیا۔ اپنی سنجیدگی، دل جمعی، قابلیت اور نکتہ سنجی کے باعث وہ شاہی حکام کی نظروں میں آئے اور ان کے توسط سے شاہی خاندان کے ساتھ تعلق قائم ہو گیا۔ بعض تذکروں میں آیا ہے کہ خلیفۂ وقت کو اپنے دونوں شہزادوں کے لیے اتالیق اور جائیداد کا حساب رکھنے کے لیے محرّر چاہیے تھا اور محمد بن ابی عامر اس کے لیے منتخب ہوگئے۔ قسمت ان کے خواب اور عزم و ارادے کے ساتھ تھی اور وقت نے کچھ اس تیزی سے کروٹ بدلی کہ ابنِ عامر وہ شخص بن گئے جس کے تعاون اور مدد سے خلیفہ ہشام اوّل کے انتقال کے بعد بارہ سالہ ولی عہد ہشام دوم مسندِ خلافت تک پہنچے۔ اور پھر اسی نو عمر خلیفہ نے اپنے محسن کو حاجب جیسے اہم ترین عہدے پر فائز کیا۔ ابنِ عامر کا یہ عہد چھتیس سال تک رہا جس میں انھوں نے عیسائی لشکروں سے باون جنگیں لڑیں اور ہر بار میدان سے فاتح بن کر لوٹے۔ وہ المنصور کے لقب سے مشہور ہوئے۔ اس سے قبل وہ قاضی کے عہدے پر بھی فائز رہے تھے
مشہور برطانوی مؤرخ اور ماہرِ آثارِ قدیمہ اسٹینلے لین پول نے المنصور کے بارے میں لکھا: ’’عبدالرحمٰن سوئم نے جس عظیم اندلس کا خواب دیکھا تھا، اس کی تعبیر المنصور کے عہد میں ہوئی‘‘۔ ابنِ ابی عامر المنصور نے اندلس میں اعلیٰ پائے کا انتظام رائج کیا اور ہر شعبے میں قاعدہ مقرر کیا۔ اس عہد میں رشوت اور بدعنوانی کی سختی سے بیخ کنی کی گئی جب کہ اہلِ علم و ادب کی بڑی قدر افزائی اور ان کے لیے وظیفے مقرر کیے۔
مشہور ہے کہ ابنِ ابی عامر نے اپنی موت سے کچھ عرصہ قبل اپنے وزرا کو بتایا: ’’میں زمانۂ طالبِ علمی سے سوچتا تھا کہ اگر تقدیر مجھے اندلس کا طاقتور ترین شخص بنا دے تو میں اس سلطنت کو عظمت کی ان بلندیوں تک پہنچا دوں گا کہ یہاں کے شہری ہونے پر سب فخر کریں گے۔‘‘ مؤرخین نے لکھا ہے کہ ان کے عہد میں عوام خود کو بہت محفوظ خیال کرتے تھے۔ دوسری طرف وہ اسلام کے ایک بہادر سپاہی اور اپنے دین کے محافظ بھی تھے جس نے میدانِ جنگ میں عیسائیوں کو بدترین شکست دی تھی جس کی بنا پر وہ المنصور سے سخت نفرت کرتے تھے، لیکن بعد کے ادوار میں عیسائی مؤرخین نے بھی لکھا کہ اس مسلمان منتظم کے دور میں اندلس کو جو عروج نصیب ہوا، وہ دوبارہ نہ مل سکا۔ انھوں نے کئی علاقوں کو فتح کے بعد مرکز کے صوبے کے طور پر اپنی سلطنت سے جوڑا اور خراج وصول کرکے اسے مالی طور پر مستحکم کیا۔
ابنِ ابی عامر اندلس اور مسلم تاریخ کا ایک ایسا جگمگاتا کردار ہے، جس کی آب و تاب کئی سو سال گزرنے جانے کے بعد بھی ماند نہیں پڑی۔ تاریخ کی کتب میں آیا ہے کہ وہ الحاجب المنصور کے نام سے یاد کیے جاتے تھے جس میں حاجب ان کا عہدہ اور المنصور ان کی غیرمعمولی فتوحات کے لیے دیا گیا نام تھا۔ 10 اگست 1002ء کو وفات پانے والے اس مشہور مسلمان منتظم اور جرنیل کی یادگار کے طور پر وسطی اسپین میں ایک پہاڑ کی سب سے بلند چوٹی کو ان سے موسوم ہے۔ اسپین میں کئی مقامات پر ان کے مجسمے نصب ہیں اور آج بھی دسویں صدی کے اس نام ور مسلمان جرنیل کی بہادری اور شان دار عہد کی یاد دلاتے ہیں۔