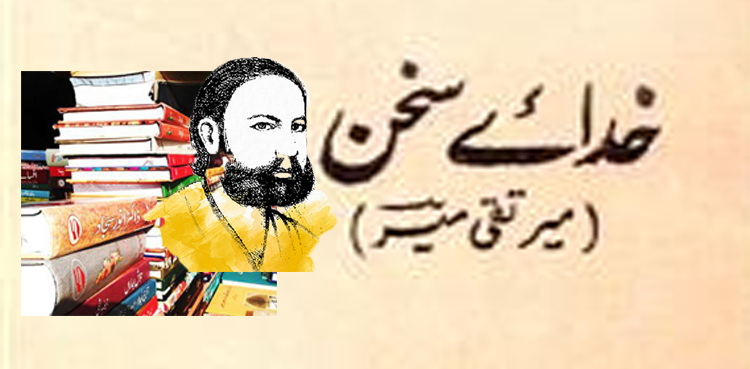میں نہ تو غالب کا ماہر ہوں اور نہ ہی میں نے غالیبات کے سلسلے میں لکھی گئی ساری کتابیں اور مضامین پڑھے ہیں، ہاں چند کتابوں اور چند مضامین کا مطالعہ کیا ہے اور کلیات غالب (ڈاکٹر گیان چند نسخہ عرشی کو اسی نام سے یاد کرتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ صحیح بھی ہے) کا مطالعہ کرنے کا شرف ضرور حاصل ہے، اس لیے میں اپنے ’’پراگندہ ذہن‘‘ کی مدد سے چند باتیں لکھنے کی جرأت کر رہا ہوں۔
غالب کے ماہرین اور محققین سے بہ صد عجز عرض ہے کہ دیوانے کی ہو بھی کبھی کبھی قابل توجہ ہوتی ہے۔
مجھے ہمیشہ کی طرح غالب کی شخصیت کا مطالعہ ایک ایسے ڈیلیما سے دوچار کرتا ہے جس کا حل آسان نہیں ہے۔ غالب کے محققین نے ان کی شخصیت کے اتنے ایکسرے پیش کیے ہیں کہ ان کی زندگی کے شب و روز کبھی دھوپ اور کبھی چاندنی کی طرح تیز گرم، روشن اور ٹھنڈے دھندلے عکس نظر آتے ہیں مگر محققین کی اس ’’کام یابی‘‘ کے باوجود غالب کی شخصیت کے سارے پیچ و خم کھل کر سامنے نہیں آتے ہیں۔ غالب سے مکمل تعارف بھی ایک قسم کی پراسراریت کو قائم رکھتا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان کا مکمل تجزیہ ہمیشہ تشنہ ہی رہے گا۔ غالب اپنے اشعار اور خطوط میں اتنا عریاں نہیں ہیں جتنا کہ قیس تصویر کے پردے میں تھا، اس لیے کہ قیس تو ایک یک رخا عاشق اور غالب ’’مجموعۂ اضداد‘‘ ہیں اور یہی رنگا رنگی ہے جو ہم لوگوں کے لیے ’سوہانِ روح‘ بن گئی ہے۔
اگر اس پر یقین آ جائے کہ ان کی شخصیت کا جائزہ ممکن ہی نہیں ہے تو بحث ختم ہو جاتی ہے اور ان کی شاعری کے بارے میں یقین سے رائے دی جا سکتی ہے مگر ناتمامی اور تشنگی کا یہ مسلسل احساس ہی ان کی شخصیت اور شاعری کو اور بھی قابل توجہ بناتا ہے۔ جشن غالب (۱۹۶۹ء) کے بعد یہ خیال کیا جاتا تھا کہ نئے ناقدین غالب پر ’حملہ آور‘ ہوں گے اور غالب کی پرانی آرزو یعنی’’اڑیں گے پرزے‘‘ پوری ہوگی۔ تماشا تو خوب دھوم سے ہوا مگر کچھ نہ ہوا۔ مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ غالب آج بھی اردو تنقید پر خندہ زن ہیں۔ میری کیا بساط ہے کہ میں ان کی دیرینہ آرزو پوری کروں، میں تو صرف اتنا کہہ سکتا ہوں:
رکھیو غالب مجھے اس تلخ نوائی میں معاف
آج کچھ درد مرے دل میں سوا ہوتا ہے
غالب کی شخصیت پر لکھے گئے درجنوں مضامین، غالب کے خطوط اور ان کی شاعری کا تمام تر مطالعہ مجھے اس نتیجے پر پہنچاتا ہے کہ وہ ایک Precocious Child تھے، کم عمری میں بالغ ہو گئے تھے۔ بچوں کی نفسیات کے ایک امریکی ماہر ڈاکٹر اسپاک Dr. Spock کا خیال ہے کہ ایسے ذہین بچے اکثر اپنی ذہانت کا خود شکار ہو جاتے ہیں اور بہت جلد تازگی اور ندرت کھو بیٹھتے ہیں۔ یہ بچے شاید ان غنچوں کی طرح ہیں جو کھلتے ہی مرجھا جاتے ہیں مگر غالب اس تجزیے سے مستثنا نظر آتے ہیں۔ وہ خاصی کم سنی میں فارسی اور اردو زبانوں میں اعلیٰ پائے کے شعر موزوں کرنے کے اہل ہو گئے تھے، یہی نہیں پندرہ بر س کی عمر میں وہ آفات زمانہ کی تلخیوں سے بھی لطف اندوز ہونے کا سلیقہ جان گئے تھے۔ ان کے خطوط ان کی کھلی ہوئی شخصیت Open Personality کی ا چھی مثالیں ہیں مگر اس کے باوجود اپنی شخصیت کے سارے پہلو عیاں نہیں کرتے ہیں۔
وہ اپنی انا کے ساتھ خاکساری کے جواہر بھی پیش کرتے ہیں، وہ دوستوں کے دوست اور دشمنوں کے دشمن ہونے کے باوجود دوستی کے حدود اور دشمنی کی بیکرانی سے واقف ہیں۔ وہ شخص جو کم سنی میں یتیم ہو گیا ہو، جس کو اپنی ماں سے کوئی خاص محبت بھی نہ ہو، جس نے کم عمری سے آزادانہ جنسی زندگی گزاری ہو اور جو اپنی شخصیت کی تعمیر میں اتنا کوشاں بھی نہ ہو کہ ہر قدم پر احتیاط کرتا ہو، ایسے شخص کی زندگی سے ساری نقابیں اٹھ جائیں تووہ عریاں نظر آئے گا مگر غالب پھر بھی اپنی شخصیت کا کوئی نہ کوئی پہلو چھپا جاتے ہیں۔ جان بوجھ کر اپنے کو چھپانے والا شخص سہما ہوا اور اکثر بکتر بند نظر آتا ہے۔
غالب کی بے پناہ ذہانت ان کا مطالعہ کرنے والی نظروں کو خیرہ کر دیتی ہے۔ اگر یہ معلوم بھی ہو جائے کہ وہ بذلہ سنج تھے، شاعر نغز گو تھے، ہشت پہلو شخصیت رکھتے تھے، پھر بھی یہ احساس کیسے قائم رہتا ہے کہ غالب سے ملے لیکن غالب کو نہ سمجھ پائے۔ مجھے دو ایک ماہر غالبیات سے ملنے کا اتفاق ہوا ہے اور میرے مسلسل سوالات کے بعد بھی وہ میری تشفی نہیں کر سکے۔
غالب کی شخصیت میں خود پر خندہ زن ہونے کی جو بے مثال صلاحیت ہے وہ انہیں (شاید) پراسرار بنائے رکھتی ہے۔ حالی کے ’’حیوان ظریف‘‘ کی ذہانت، فطانت اور ندرت تجزیہ نگار کو مبہوت کر دیتی ہے۔ آپ لاکھ ان کی شخصیت کو مختلف خانوں میں بند کرنے کی کوشش کریں وہ بند بھی نظر آتے ہیں اور نہیں بھی۔ اور ان کی شخصیت کے ایک پراسرار پہلو پر تیز شعاعیں ڈالی جائیں یعنی ان کے طنز و مزاح کا گہرا تجزیہ کیا جائے تو وہ کبھی ایک دل جلے کی ہنسی ہنستے ہیں جیسے:
اور بازار سے لے آئے اگر ٹوٹ گیا
ساغر جم سے مرا جام سفال اچھا ہے
مگر یہ تبسم بھی پھیکا نہیں ہے اور معنی خیز ہے اور کبھی ایک ایسے دانشور کے تبسمِ زیرِ لب کا احساس ہوتا ہے جو دل ہی دل میں قہقہے لگاتا ہے مگر اس کے چہرے کی سنجیدگی پوری طرح قائم رہتی ہے، صرف آنکھوں کی چمک شوخ تر نظر آتی ہے:
کیوں نہ فردوس میں دوزخ کو ملا لیں یارب
سیر کے واسطے تھوڑی سی فضا اور سہی
وہ شخصیت جو اپنے ’’یارب‘‘ سے اتنے گہرے دوستانہ مراسم رکھتی ہو، اس کی وسعت اور گہرائی کا اندازہ لگانا: دشوار تو یہی ہے کہ دشوار بھی نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ غالب کی آزادانہ شخصیت اپنی آزادی کے حدود سے واقف تھی۔ وہ زخمی ہوکر اپنا ضبط و غم نہیں کھوتے بلکہ اپنی شکست کو بھی ایسے طنز آمیز تبسم سے قبول کرتے ہیں کہ فاتح بھی ان کو دیکھ کر دنگ رہ جائے۔ چارلی چپلین نے اپنی خودنوشت سوانح عمری میں کہیں لکھا ہے کہ ’’وہ مسخرہ کس کام کا جو دوسروں کو صرف ہنسا سکے۔‘‘ غالب تبسم کی زیریں لہر میں خاموش غم کو بھی اس طرح سمونے کا فن جانتے تھے کہ آدمی دکھی ہو کر بھی ان کی خندہ زنی میں شریک ہو جاتا ہے، بے دلی سے نہیں بلکہ کشادہ دلی سے:
ناکردہ گناہوں کی بھی حسرت کی ملے داد
یارب اگر ان کردہ گناہوں کی سزا ہے
اور اس شعر کا ’’اگر‘‘ گناہوں پر سوالیہ نشان لگا دیتا ہے۔ ناکردہ گناہوں کو جنسی تلذذ کی خواب بندی کہا جا سکتا ہے۔ غالب کی شخصیت کا بنیادی مطالعہ ہمیں حیرت میں ڈال دیتا ہے۔ وہ یتیم تھے مگر ان کا بچپن محرومیوں سے بہت دور تھا۔ انہیں اپنے باپ کی یاد بھی بہت کم آتی ہے۔ گو کہ خطوط میں وہ اپنے باپ اور چچا کی موت کا اکثر ذکر کرتے ہیں۔ خورشید الاسلام کا خیال ہے کہ ’’افسردگی اور تصوف سے دلچسپی کے اسباب ان کے تجربوں میں ڈھونڈنے چاہیے۔‘‘ یعنی یتیمی، کم عمری کی شادی اور ۲۵ برس کی عمر میں عشق۔ میری ناچیز رائے یہ ہے کہ بچے کو اگر شروع میں محرومی کا احساس نہ ہو تو یتیم ہونے کے باوجود اپنے والد کے سائے کا خواہاں نہیں رہتا ہے بلکہ اس پودے کی طرح تیزی سے بڑھتا اور پروان چڑھتا ہے جس پر کوئی برگد سایہ فگن نہیں ہوتا ہے، کیونکہ غالب کی شخصیت میں وسیع المشربی، رندی، شوخی اور طنز کے جو بنیادی عناصر ہیں وہ اسی وجہ سے اتنے گہرے اور پائیدار ثابت ہوتے ہیں کہ ان کی ترقی میں کوئی روک ٹوک نہ تھی۔
جنس کا مطالعہ کرتے ہوئے یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اس کو عام بنے بنائے پیمانے سے نہیں ناپا جا سکتا، اس لیے خورشید صاحب نے شخصیت کے نقوش اجاگر کرنے کے لیے جو پیمانہ بنایا ہے وہ اپنی جگہ تمثیلی ہوتے ہوئے بھی غالب کے لیے نامناسب ہے۔ ان کی کم عمری میں شادی بھی اسی لیے کی گئی تھی کہ انہیں آزادانہ زندگی بسر کرنے سے روکا جا سکے۔ اسی لیے انہوں نے شادی کو’بیڑی‘ کہا ہے، ورنہ وہ اپنی بیوی سے محبت نہ کرتے ہوئے بھی نفرت نہیں کرتے تھے۔ اس کا ثبوت اولادیں ہیں۔ ہاں ان کے عشق کے سلسلے میں قیاس آرائیاں کی جا سکتی ہیں۔ حمیدہ سلطان نے ایک مضمون میں لکھا تھا کہ ’’امراؤ بیگم نے ان کے (غالب کے) ذوق شعر کو بلند کیا، کردار کو پاکیزگی بخشی، آگرے کی بے راہ روی اور رنگ رلیاں دلّی کے مستقل قیام کے بعد تقریباً ختم ہو گئیں۔‘‘ حمیدہ سلطان کے اس بیان پر ڈاکٹر عبدالسلام خورشید نے صحیح نکتہ چینی کی ہے، اس لیے کہ آگے چل کر خود حمیدہ سلطان یہ بھی کہتی ہیں کہ ترک نامی ایک خاتون تھی جس سے مرزا کا عشق تھا۔ محترمہ کے الفاظ ہیں:
’’مرزا کی شاعری کا بے مثل حسن، انفرادی بانک پن جس نگہِ ناز کا عطیہ ہے، مرزا کے فکر کو جس دلکش خیال نے رنگینی و دل آویزی بخشی، اس شعلہ خُو حسینہ کے حسنِ صورت پر ہی نہیں حسنِ سیرت و ذہانت پر بھی مرزا فریفتہ تھے۔ بہت ممکن ہے کہ غالب کے ہر شعر میں جو دل کی دھڑکن سنائی دیتی ہے، وہ ترک کا عطیہ ہو۔‘‘ (اقتباس از مضمون ڈاکٹر عبدالسلام خورشید، نقوش غالب نمبر ص ۳۶۸، ۱۹۶۹ء)
یہ ایک بیوہ خاتون تھیں۔ ان سے غالب کا عشق ثابت کرنا ایک قسم کی قیاس آرائی ہے۔ اصل میں غالب کا کوئی ایک محبوب نہیں ہے۔ وہ نہ بھونرے ہیں اورنہ مگس، ان میں ان دونوں کی ایک ایک خوبی ہے یعنی حسن پرستی مگر یہاں بھی غالب کی دانشورانہ طراری کبھی سپر نہیں ڈالتی، وہ اپنے آپ کو کسی حسین سے کمتر نہیں سمجھتے تھے اور یہ خود نگری اور خود سری اس انا کو جنم دیتی ہے جو ان کی ہمیشہ ممد و معاون رہی اور تیزابی ذہانت کے ساتھ ساتھ وہ درد مند دل بخشا کہ اس کو کسی ایک نفسیاتی پیمانے سے نہیں ناپا جا سکتا ہے۔
کہا گیا ہے کہ جینیئس خود اپنا پیمانہ لے کر آتا ہے۔ جبھی تو غالب کی کم سنی، جوانی اور عمر کی خستگی کا اندازہ ایک پیمانے، ایک نظریے اور ایک معیار سے نہیں لگایا جا سکتا ہے۔ غالب کی شخصیت کو سمجھنے کے لیے غالب سے مستعار لے کر معیارات قائم کرنے ہوں گے، اس لیے کہ وہ صرف فخرِ عرفی اور رشک طالب نہیں تھے بلکہ ان سے اپنا الگ معیار رکھتے تھے۔
(ممتاز نقاد اور روایت شکن قلم کار باقر مہدی کے مضمون سے اقتباسات)