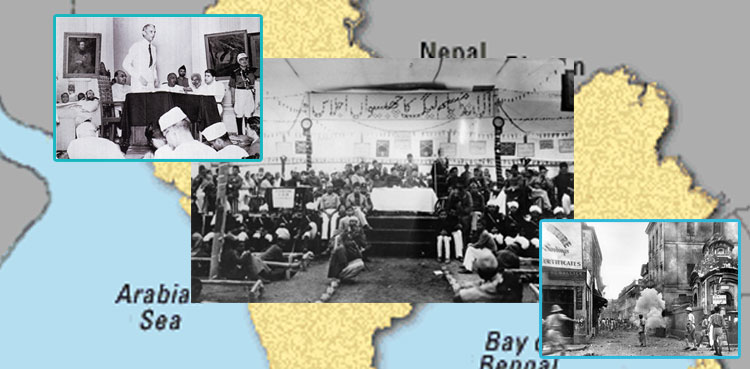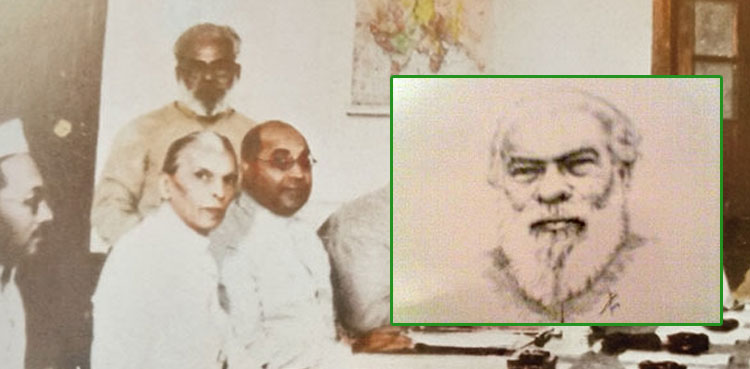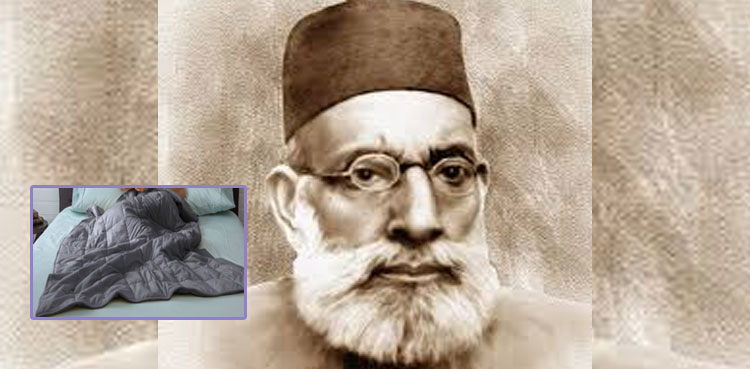لارڈ میکالے ایک انگریز مدبّر اور ایسا پالیسی ساز تھا جس نے برطانوی عہد میں ہندوستان میں اپنی ذمہ داریاں نبھائیں، لیکن وہ برصغیر میں متنازع بھی رہا کہ بحیثیت قوم ہندوستانیوں کے نزدیک میکالے ان کی تہذیب اور ثقافت کا دشمن اور اسی بنیاد پر قابلِ نفرت شخص تھا۔ لیکن دل چسپ بات یہ ہے کہ تقسیمِ ہند کے نتیجے میں پاکستان اور بھارت کے نام سے معرضِ وجود میں آنے والی دو ریاستیں آج بھی اسی لارڈ میکالے کی فکر اور پالیسیوں سے استفادہ کر رہی ہیں۔
میکالے کا تذکرہ بالخصوص ہندوستان میں تعلیمی نظام اور قوانین و تعزیرات کے حوالے سے کیا جاتا ہے۔ میکالے کے بارے میں ہندوستانیوں کی ایک عام رائے یہ تھی کہ وہ مغربی فکر اور تہذیب و ثقافت کو ہندوستان میں پروان چڑھانے اور ہندوستان کو اس کی تاریخی اور ثقافتی جڑوں سے الگ کرکے یہاں ایک طبقہ پیدا کرنا چاہتا تھا جو مغرب کی اقدار کی پیروی کرتا ہو۔ اس کے ثبوت میں اس کا یہ مقولہ ہر جگہ پڑھنے کو ملتا تھا: ”ہماری بہترین کوششیں ایک ایسا طبقہ معرضِ وجود میں لانے کے لیے وقف ہونی چاہییں جو ایسے افراد پر مشتمل ہو جو رنگ و نسل کے لحاظ سے تو ہندوستانی ہو لیکن ذوق، ذہن، اخلاق اور فہم و فراست کے اعتبار سے انگریز“۔
ہمارا نظامِ تعلیم بھی لارڈ میکالے کی دین ہے۔ وہ 25 اکتوبر 1800ء میں پیدا ہوا اور 1859ء میکالے اس دنیا سے کوچ کر گیا۔ وہ اپنے عہد کا ایک دانش ور تھا جو برطانوی پارلیمان میں شامل رہا۔ میکالے نے تاریخی اور سماجی و سیاسی موضوعات پر مضامین تحریر کیے اور شہرت پائی۔ وہ 1839ء اور 1841ء کی جنگوں میں ’’سیکریٹری آف وار‘‘ کے عہدے پر بھی فائز رہا۔ اس نے 1846ء اور 1848ء کے دوران ’’پے ماسٹر جنرل ‘‘ کی ذمہ داریاں بھی نبھائیں۔ انگلستان کی تاریخ پر شاہ کار کتاب بھی تحریر کی، اور برصغیر میں تعلیمی پالیسی ساز کے طور پر کام کیا مگر ہندوستانی عوام میں وہ صرف مغربی تہذیب اور ثقافت کا پرچارک مشہور تھا۔ لارڈ میکالے کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اسے یہ حق دیا گیا تھا کہ وہ جو بھی پالیسی نافذ کرنا چاہے، کر سکتا تھا۔ لارڈ میکالے نے جس نظامِ تعلیم کی داغ بیل ڈالی تھی، اس نے واقعی برِّصغیر کا تعلیمی ماحول یک سَر تبدیل کر دیا تھا جو ہندوستانیوں کی سوچ میں تبدیلی کا ذریعہ بن گیا۔ متحدہ ہندوستان میں اُس وقت کے کئی علما، فاضل شخصیات، مسلمان سیاسی راہ نماؤں اور دانش وروں نے بھی انگریزی زبان کی ترویج، اور جدید تعلیم کے لیے لارڈ میکالے کی تجاویز اور بعض نکات پر اعتراضات کیے تھے، لیکن اسے قبول بھی کر لیا گیا۔ یہ شخصیات سمجھتی تھیں کہ میکالے کی وجہ سے ہندوستانی اپنی تہذیب و ثقافت کو کم تر خیال کرنے لگے ہیں اور وہ مغربی کلچر کو قبول کررہے ہیں۔
ٹامس بیبنگٹن میکالے اس کا پورا نام تھا جو 1834ء میں ہندوستان کی سپریم کونسل میں بطور رکن قانون حلف اٹھانے کے بعد یہاں چار برس تک مقیم رہا۔ ہندوستان میں اس نے انڈین پینل کوڈ مرتب کیا۔ اس کا دوسرا بڑا کارنامہ اس تعلیمی یادداشت کی تصنیف تھا۔ اس کے فیصلوں نے ہندوستان کے تعلیمی مستقبل اور اس کے قانونی نظام پر اپنے گہرے اثرات مرتب کیے۔
میکالے کی مخالفت اور اس کی پالیسیوں پر نکتہ چینی کے باوجود اس انگریز کا پہلا کارنامہ ہندوستان میں جدید نظامِ تعلیم کی ترویج اور دوسرا مجموعۂ تعزیراتِ ہند کی تشکیل کہا جاتا ہے۔ اس کے وضع کردہ نظامِ تعلیم اور تشکیل کردہ مجموعۂ تعزیرات ہند کی جامعیت ملاحظہ ہو کہ لگ بھگ دو صدی بعد بھی برصغیر پاک و ہند میں ان دونوں نظاموں میں معمولی ترامیم تو کی جاتی ہیں، لیکن ان کا کوئی قابلِ قبول متبادل آج تک پیش نہیں کیا جاسکا۔ ہندوستانی تہذیب و ثقافت کا یہ غارت گر بھی کیسا نکلا کہ اس کی سربراہی میں جو مجموعۂ تعزیراتِ ہند مرتب کیا گیا، اسے پاکستان اور بھارت نے اپنے قیام کے بعد قبول بھی کیا اور ان دونوں ملکوں کی عدالتوں میں فوجداری مقدمات کا فیصلہ انہی کی بنیاد پر کیا جاتا اور مجرموں کو سزائیں سنائی جاتی ہیں۔ یہ قوانین غدر کے بعد برطانوی حکومت کے تحت ہندوستان میں نافذ کیے گئے تھے۔ یہ مجموعۂ تعزیرات پانچ سو گیارہ دفعات پر مشتمل ہے۔ میکالے کی ذہانت اور فہم کا اندازہ اس بات سے لگایا جاسکتا ہے کہ اس نے ان پانچ سو گیارہ دفعات میں جرم کی ہر شکل کو کچھ اس انداز سے سمو دیا ہے کہ اس پر بڑے بڑے قانون داں بھی حیران رہ جاتے ہیں۔ تعزیرات کا یہ نظام پاک و ہند کی سماجی زندگی میں بھی اس طرح رچ بس گیا ہے کہ اس سے زیادہ معقول سزائیں ہم آج بھی نہیں سوچ سکے ہیں۔ خود کشی کی کوشش سے لے کر قتلِ عمد تک، انفرادی لڑائی جھگڑے سے لے کر بلوے تک اور نفرت انگیز تقاریر سے لے کر ریاست کے خلاف بغاوت تک کے ہر جرم کی اتنی معقول سزا اس مجموعے میں لکھی گئی ہے کہ اس میں کوئی کمی بیشی مشکل نظر آتی ہے اور ہر قانون داں لارڈ میکالے کی طے کردہ سزا پر ہی متفق ہے۔
پاکستان معرضِ وجود میں آیا تو یہاں دستور ساز اسمبلی نے انہی قوانین کو ‘مجموعۂ تعزیراتِ پاکستان‘ کہہ کر منظور کر لیا۔ بعد میں معمولی اور جزوی تبدیلیاں تو کی گئیں مگر بیشتر کو بعینہ روا رکھا گیا۔
لارڈ میکالے کے مجموعۂ تعزیرات کا پندرہواں باب مذہبی منافرت کے بارے میں ہے۔ اس باب میں اس نے بتایا ہے کہ اگر کوئی شخص مذہب کی آڑ لے کر معاشرے کے کسی گروہ کو نشانہ بناتا ہے تو اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جانا چاہیے۔ اس باب میں تجویز کردہ سزاؤں کا خوف ایسا تھا کہ کئی برس تک برطانوی ہندوستان کا کثیر مذہبی معاشرہ بڑی حد تک مذہبی رواداری کے ساتھ قائم رہا لیکن بعد میں پاکستان اور بھارت میں بھی مذہبی تفریق اور تعصب نے کیا کیا رنگ دکھائے، یہ سب کے سامنے ہے۔ یہ بھی سچ ہے کہ متحدہ ہندوستان میں مخصوص ذہنیت اور مذہبی و ثقافتی تفاخر میں مبتلا راہ نماؤں نے اپنے زیرِ اثر طبقات میں جس طرح لارڈ میکالے کو اس کی پالیسیوں پر مطعون کیا اور اس کے اقدامات کو متنازع بنایا، ان کو ہندوستان میں فکری اور تعلیمی سطح پر انقلابی تبدیلیاں دیکھنے کے خواہش مند بعض حلقوں کے اکابرین نے تنقید کا نشانہ بھی بنایا تھا، اور اس سوچ کو ہندوستانی قوم کی پسماندگی اور مسلسل تنزلّی کا ذمہ دار قرار دیا تھا۔ آج کسی نہ کسی شکل میں میکالے کی سوچ بھی زندہ ہے اور اس کی پالیسیاں اور وضع کردہ قوانین بھی ہمارے لیے کارآمد ثابت ہو رہے ہیں۔