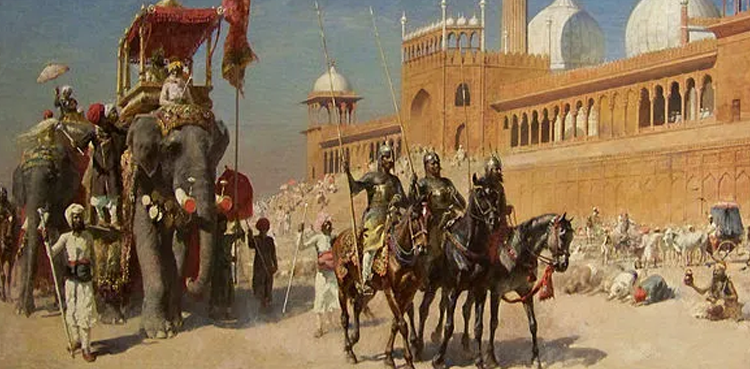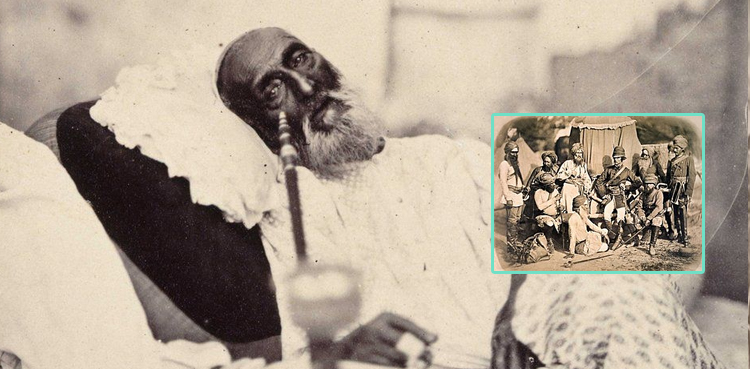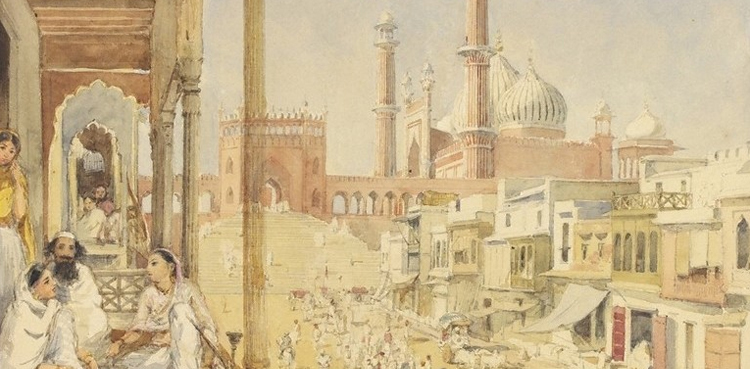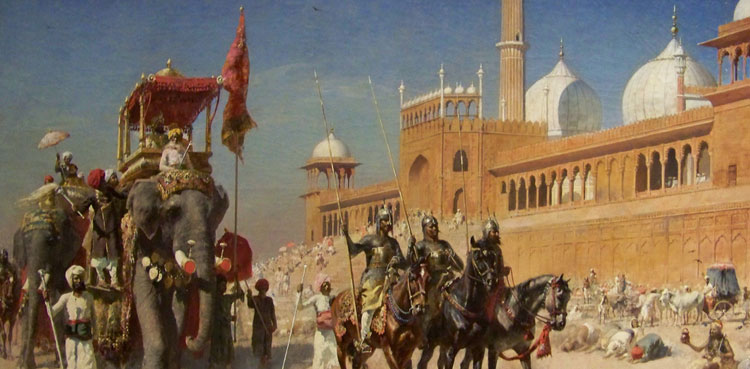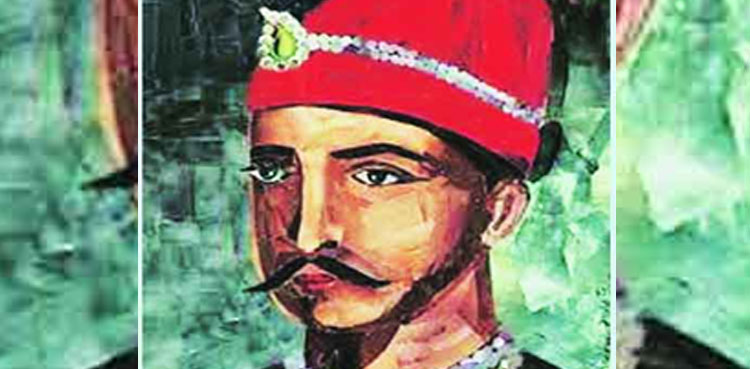اردو کے صاحبِ طرز ادیب، انشا پرداز خواجہ حسن نظامی نے غدر، مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر اور ان کے خاندان پر ٹوٹنے والی افتاد کو اپنی تحریروں میں نہایت دل سوز انداز میں جگہ دی ہے۔
ہندوستان کے آخری بادشاہ کی پوتی نرگس نظر پر انگریزوں کے خلاف ناکام بغاوت کے بعد کیا بیتی اور انھوں نے کیسے سخت اور کٹھن حالات میں زندگی گزاری، یہ سب خواجہ صاحب کے اس مضمون میں پڑھا جاسکتا ہے۔
قلعہ کی آخری رات
جس رات بہادر شاہ بادشاہ لال قلعہ سے نکل کر ہمایوں کے مقبرے میں گئے اور یقین ہوگیا کہ صبح انگریز دہلی کو مفتوح کر لیں گے تو نرگس نظر چپ چاپ جل محل کے کنارے پر کھڑی چاندنی کو دیکھ رہی تھیں۔ ان کا عکس تالاب میں پڑ رہا تھا اور ان پر اپنی دید کا ایک عجیب عالمِ محویت طاری تھا۔
یکایک ان کے باپ میرزا شاہ رخ اندر آئے اور انہوں نے کہا، ’’نرگس بیٹا! میں ابا حضرت (بہادر شاہ) کے ہمراہ جانا چاہتا ہوں۔ تم ابھی چلو گی یا سواری کا بندوبست کروں، صبح آجانا۔‘‘
نرگس نظر نے کہا، ’’ابا جان! آپ بھی ابھی نہ جائیے۔ پچھلی رات میرے ساتھ چلیے گا۔ میں دادا حضرت کے ساتھ جانا مناسب نہیں سمجھتی۔ انگریز فوج انہی کی تلاش کرے گی اور جو لوگ ان کے ساتھ ہوں گے، وہ سب مجرم سمجھے جائیں گے۔ اس لیے ہمایوں کے مقبرے میں دادا حضرت کے ساتھ جانا ٹھیک نہیں ہے۔ غازی نگر (غازی آباد) میں چلیے۔ وہاں میری انا کا گھر ہے اور سنا ہے بہت اچھی محفوظ جگہ ہے۔ گمنامی اختیار کر کے چلنا چاہیے۔ جب یہ بلا دور ہو جائے گی پھر یہاں آجائیں گے۔‘‘
میرزا نے کہا، ’’اچھا جیسی تمہاری رائے ہو۔ غازی نگر جانے کے لیے رتھوں کا بندوبست کرتا ہوں، تمہارے ساتھ کون کون جائے گا۔‘‘ نرگس نظر نے جواب دیا، ’’کوئی نہیں، صرف میں اکیلی چلوں گی، کیونکہ نوکروں کا ساتھ رکھنا بھی نامناسب ہے اور نوکر ساتھ جانے کے لیے تیار بھی نہیں معلوم ہوتے۔‘‘ میرزا یہ سن کر باہر چلے گئے اور نرگس نظر پھر ماہتاب اور عالم آب کو دیکھنے لگیں۔
کچھ دیر کے بعد نرگس نظر نے نوکر عورتوں کو آواز دی مگر کسی نے جواب نہ دیا۔ معلوم ہوا سب بھاگ گئے اور نرگس نظر سارے جل محل میں اکیلی ہیں۔ یہ پہلا موقع تھا کہ نرگس نظر نے حاکمانہ آواز دی اور جواب میں کوئی بھی نہ بولا۔ نرگس نظر گھبرا کر محل کے اندر گئیں۔ شمعیں روشن تھیں، مگر کوئی آدمی موجود نہ تھا۔ نرگس نظر کو اندر ڈر لگا اور وہ پھر صحن میں آ گئیں۔ قلعہ میں جگہ جگہ سے لوگوں کے بولنے کی آوازیں آرہی تھیں اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ چاروں طرف سے گھروں کے رہنے والے نکل نکل کر جا رہے ہیں۔ نرگس نظر نے بہت دیر باپ کی راہ دیکھی مگر وہ نہ آئے اور نرگس نظر گھبرا کر رونے لگیں۔
رات کے دو بجے ایک خواجہ سرا محل میں آیا اور اس نے کہا، ’’صاحب عالم نے فرمایا ہے کہ انگریز جاسوس میری تلاش میں قلعہ کے اندر اور باہر چاروں طرف پھیلے ہوئے ہیں۔ میں تمہارے ساتھ غازی نگر نہیں جاسکتا۔ سواری کا انتظام کر دیا ہے۔ تم خواجہ سرا کے ساتھ چلی جاؤ اور میں بھیس بدل کر کہیں اور چلا جاتا ہوں۔‘‘ نرگس نظر نے گھبرا کر کہا، ’’آخر کہاں جانے کا ارادہ ہے؟‘‘ خواجہ سرا بولا، ’’مجھے معلوم نہیں۔‘‘ نرگس نظر نے حاکمانہ لہجے میں کہا، ’’جا یہ معلوم کر کے آ کہ ابا حضرت کہاں جانے والے ہیں۔ وہ لباس بدل کر میرے ساتھ غازی نگر کیوں نہیں چلتے؟‘‘
خواجہ سرا فوراً واپس گیا اور نرگس نظر صحن میں ٹہلتی رہی۔ کچھ دیر کے بعد خواجہ سرا واپس آیا اور اس نے کہا، ’’ابا حضرت سائیس کے کپڑے پہن کر قلعہ کے باہر چلے گئے اور کوئی نہیں جانتا کہ کہاں چلے گئے۔ آپ کی سواری کے لیے رتھ تیار ہے۔‘‘ نرگس نظر کو رونا آ گیا اور ان کی زندگی میں یہ پہلا موقع تھا کہ انہوں نے نہایت بے کسی اور بے بسی کی حالت میں ہچکیاں لے کر آنسو بہائے۔ انہوں نے جواہرات اور زیورات کا صندوقچہ اور چند ضروری کپڑے ساتھ لیے جن کو خواجہ سرا نے اٹھا لیا اور جل محل سے نکلیں اور سوار ہونے سے پہلے مڑ کر جل محل اور اس کی آرائش کو بہت دیر تک کھڑے ہو کر دیکھا۔ پھر کہا، ’’خبر نہیں تجھ کو پھر دیکھنا نصیب ہوگا یا آج تو ہمیشہ کے لیے مجھ سے جدا ہو رہا ہے۔‘‘
رات کے تین بج چکے تھے۔ نرگس نظر رتھ میں بیٹھی غازی نگر (غازی آبادی) کی طرف جارہی تھیں۔ صبح آٹھ بجے غازی آباد پہنچ گئیں۔ راستے میں ان کو بہت لوگ آتے جاتے ملے، مگر کسی نے ان کے رتھ کی مزاحمت نہیں کی۔ غازی آباد میں نرگس نظر کی انّا کا گھر مشہور تھا۔ جوں ہی نرگس نظر انّا کے گھر کے سامنے رتھ سے اتریں، انّا دوڑتی ہوئی گھر کے باہر آگئی اور اس نے دونوں ہاتھوں سے شہزادی کی بلائیں لیں اور اندر لے جا کر بٹھایا اور اپنی حیثیت سے زیادہ خاطر مدارات کی۔
مصیبت
نرگس نظر دو تین روز انّا کے گھر میں آرام سے رہیں۔ یکایک خبر مشہور ہوئی کہ بادشاہ گرفتار ہوگئے اور کئی شہزادے قتل کر دیے گئے اور فوج غازی آبا د کو لوٹنے آرہی ہے۔ نرگس نظر نے جواہرات کا صندوقچہ انّا سے کہہ کر زمین میں دفن کرا دیا اور مصیبت کی گھڑی کا انتظار کرنے لگیں۔ تھوڑی دیر میں سکھ فوج غازی آباد میں داخل ہوئی اور اس نے باغیوں کی تلاش شروع کی۔ مخبروں نے کہا، ’’بادشاہ کی پوتی اپنی انّا کے گھر میں موجود ہے۔‘‘ دو سکھ سردار چار سپاہیوں کے ساتھ انّا کے گھر میں آئے اور انہوں نے سب گھر والوں کو پکڑ لیا۔ نرگس نظر کوٹھری میں چھپ گئی تھیں۔ ان کو بھی کواڑ توڑ کر باہر نکالا گیا اور بے پردہ سامنے کھڑا کیا گیا۔ سردار نے پوچھا، ’’کیا تم بہادر شاہ کی پوتی ہو؟‘‘ نرگس نظر نے کہا، ’’میں ایک آدمی کی بیٹی ہوں۔ بادشاہ کی اولاد ہوتی تو اس غربت زدہ گھر میں کیوں آتی۔ اگر خدا نے بادشاہ کی پوتی بنایا ہوتا تو تم اس طرح بے پردہ مجھ کو سامنے کھڑا نہ کرتے۔ تم ہندوستانی ہو، تم کو شرم نہیں آتی کہ اپنے ملک کی عورتوں پر ظلم کرتے ہو۔
سردار نے کہا، ’’ہم نے کیا ظلم کیا؟ ہم تو یہ دریافت کرتے ہیں کہ تم کون ہو؟ ہم نے سنا ہے کہ تم بہادر شاہ کی پوتی ہو اور تمہارے باپ نے بہت سے انگریزوں اور ان کی عورتوں اور بچّوں کو قلعہ کے اندر قتل کیا تھا۔‘‘ نرگس نظر نے کہا، ’’جو کرتا ہے وہی بھرتا ہے۔ اگر میرے باپ نے ایسا کیا ہوگا تو ان سے پوچھو۔ میں نے کوئی جرم نہیں کیا۔ میں نے کسی کو نہیں مارا۔‘‘ یہ سن کر دوسرا نوجوان سکھ سردار بولا، ’’ہاں تم تو آنکھوں سے قتل کرتی ہو۔ تم کو تلواروں اور ہتھیاروں سے مارنے کی کیا ضرورت ہے؟‘‘
نرگس نظر نے نہایت جرأت کے ساتھ جواب دیا، حالانکہ اس کی زندگی میں غیر مردوں سے بات کرنے کا یہ پہلا موقع تھا، ’’خاموش رہو۔ بادشاہوں سے ایسی بے تمیزی کے ساتھ بات نہیں کرتے۔ تمہاری زبان گدی کے پیچھے سے نکال لی جائے گی۔‘‘ نوجوان یہ سن کر بگڑا اور اس نے آگے بڑھ کر نرگس نظر کے بال پکڑ لیے اور ان کو روز سے جھٹکا دیا۔ بوڑھے سکھ سردار نے نوجوان سردار کو روکا اور کہا، ’’عورت کےساتھ ایسی زیادتی کرنا مناسب نہیں ہے۔‘‘ نوجوان سردار نے یہ بات سن کر بال چھوڑ دیے۔
کرایہ کی بیل گاڑی منگوائی گئی اور اس میں نرگس نظر کو سوار کیا گیا۔ انّا اور اس کے گھر والے بھی سب قید ہو کر پیدل ساتھ چلے۔ نرگس نظر سے پوچھا گیا، ’’تمہارا زیور اور روپیہ پیسہ کہاں ہے؟‘‘ انہوں نے کہا، ’’میں خود ہی زیور ہوں اور خود ہی سمجھنے والوں کے لیے جواہر اور دولت ہوں، میرے پاس اور کچھ نہیں ہے۔‘‘ یہ سن کر دونوں سردار خاموش ہوگئے اور بہلی کو دہلی کی طرف لے چلے۔
ہینڈن ندی کے پاس گاؤں کے جاٹوں اور گوجروں نے سکھ فوج والوں پر بندوقیں چلائیں اور دیر تک ان کی آپس میں لڑائی ہوتی رہی۔ سکھ تھوڑے تھے اور گاؤں والے زیادہ تھے۔ سکھ سب مارے گئے اور گاؤں والے قیدیوں کو اپنے ساتھ گاؤں میں لے گئے۔
گنواروں نے نرگس نظر کے جسم پر جو دو چار قیمتی زیور تھے، ان کو اتار لیا اور قیمتی کپڑے بھی اتروا لیے اور کسی چماری کا پھٹا ہوا لہنگا اور پھٹا ہوا کرتہ اور میلا دوپٹہ پہننے کو دے دیا۔ نرگس نظر نے رو رو کر اپنا برا حال کر لیا اور مجبوراً تن ڈھانپنے کو یہ کپڑے پہنے۔ تھوڑی دیر میں پاس کے گاؤں کے چند مسلمان گنوار آئے اور ان کے نمبر دار نے نرگس نظر کو گوجروں سے خرید لیا اور اپنے گاؤں میں لے گیا۔ یہ لوگ ذات کے رانگڑ تھے اور کچھ لوگ تگا قوم کے مسلمان تھے۔ نمبر دار نے اپنے لڑکے کا پیغام دیا کہ تیری شادی اس کے ساتھ کر دیں۔ یہ بڈھا آدمی تھا۔ اس کا لڑکا اگرچہ گنوار تھا، لیکن صورت شکل کا اچھا تھا۔ نرگس نظر نے ہاں کر لی اور گاؤں کے قاضی نے اس کا نکاح پڑھا دیا اور نرگس نظر تین چار مہینے نمبر دار کے گھر میں نئی دلہن بنی آرام سے بسر اوقات کرتی رہیں۔
دوسری مصیبت
انگریزوں کا قبضہ پوری طرح ہوگیا تھا اور ان کے جاسوس جگہ جگہ خبریں لیتے ہوئے پھر رہے تھے۔ کسی جاسوس نے دہلی کے حاکم کو خبر دی کہ میرزا باغی دستیاب نہیں ہوئے، مگر ان کی بیٹی فلاں گاؤں میں نمبردار کے گھر میں موجود ہے۔ انگریز حاکم نے اس گاؤں میں پولیس کو بھیجا۔ میرٹھ کی پولیس نے آکر گاؤں کا محاصرہ کر لیا اور نرگس نظر اور ان کے خاوند اور سسر کو گرفتار کر کے دہلی میں لایا گیا۔ حاکم نے نرگس نظر سے میرزا کے متعلق بہت سوالات کیے، مگر جب کوئی مفید مطلب جواب نہ ملا تو حکم دیا کہ نمبر دار اور اس کا بیٹا باغی معلوم ہوتے ہیں اور ان دونوں نے ایک باغی کی بیٹی کو پناہ دی ہے۔ اس واسطے ان دونوں کو جیل بھیج دیا جائے اور یہ عورت دہلی میں کسی مسلمان کے حوالے کر دی جائے۔
چنانچہ نمبر دار اور اس کا بیٹا دس دس سال کے لیے جیل بھیج دیے گئے اور نرگس نظر سے پوچھا گیا کہ وہ کس کے ہاں رہنا چاہتی ہے۔ شہزادی نے جواب دیا اگر میرے خاندان کے آدمی دہلی میں ہوں تو ان کے پاس بھیج دیا جائے۔ معلوم ہوا تیموریہ خاندان کے لوگ ابھی تک یا تو رو پوش ہیں یا جنگلوں اور دیہات میں مقیم ہیں۔ دہلی شہر میں ابھی کوئی نہیں آیا۔ اس واسطے نرگس نظر ایک فوجی مسلمان سپاہی کے حوالے کر دی گئیں جو ان کو اپنے گھر میں لے گیا۔ اس سپاہی کی بیوی موجود تھی۔
اس نے دیکھا کہ ایک قبول صورت جوان عورت گھر میں آئی ہے تو اس نے ایک دو ہتٹر اپنے خاوند کے مارا اور نرگس نظر کو بھی دھکا دے کر گھر سے باہر نکال دیا اور یہ پہلا موقع تھا کہ نرگس نظر کو کسی نے دھکا دیا۔ سپاہی گھر کے باہر آیا اور نرگس نظر کو ساتھ لے کر اپنے ایک دوست کے ہاں لے گیا۔ وہ بڑی عمر کے ایک مسلمان تھے اور گھر میں اکیلے رہتے تھے۔ انہوں نے شہزادی کا حال سنا تو رونے لگے اور بہت محبت کے ساتھ اپنے گھر میں جگہ دی اور نرگس نظر ایک رات آرام سے اس گھر میں رہیں۔
دوسری رات کو نرگس نظر سوتی تھیں کہ چند آدمیوں نے ان کا منہ اپنے ہاتھوں سے بند کیا اور اٹھا کر کہیں لے گئے۔ نرگس نظر نے ہر چند ہاتھ پاؤں مارے، مگر انہوں نے ایسا مضبوط پکڑا تھا کہ یہ جنبش نہ کر سکیں۔ وہ لوگ اسی گاؤں کے رہنے والے تھے جہاں کے نمبر دار کے بیٹے سے نرگس نظر کا نکاح ہوا تھا، مگر وہ دہلی کے قریب ایک گاؤں میں لے گئے اور وہاں ایک چھپر میں ٹھہرایا اور ایک چارپائی سونے کے لیے دے دی۔ یہ گاؤں بھی تگا مسلمانوں کا تھا۔
نرگس نظر جس گھر میں رہتی تھیں، وہ نمبر دار کا گھر تھا اور نمبر دار بہت نیک چلن آدمی تھا۔ تین چار سال تک نرگس نظر اس گھر میں رہیں۔ وہ سارے گھر کا کام کرتی تھیں، لیکن گوبر تھاپنا اور دودھ دوہنا ان کو نہ آتا تھا۔ چار سال کے بعد ان کا خاوند رہا ہو گیا اور وقت سے پہلے گورنمنٹ نے اس کو رہائی دے دی اور وہ نرگس نظر کو اس گاؤں سے اپنے گھر لے گیا، جہاں ساری عمر انہوں نے گزار دی اور ان کے کئی بچّے ہوئے اور 1911ء میں نرگس نظر کا انتقال ہو گیا۔