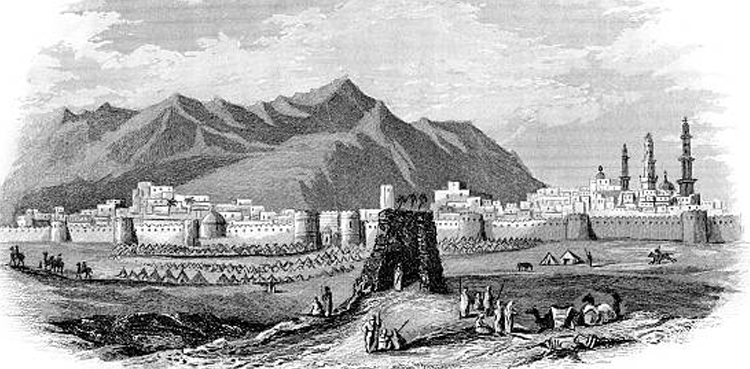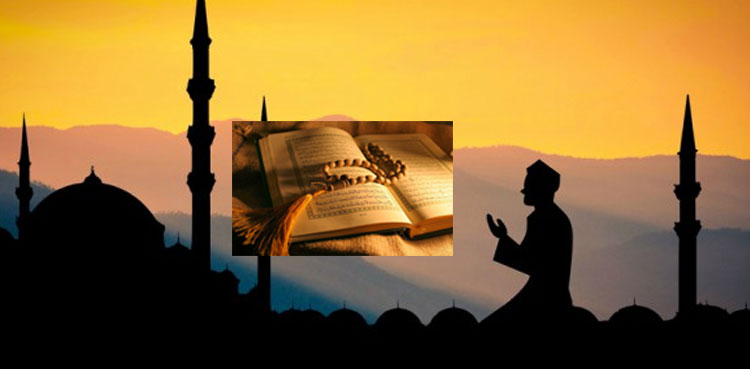’’مقدمۂ ابنُ صلاح‘‘ اصولِ حدیث میں معتبر تصنیف شمار کی جاتی ہے یہ علّامہ ابنُ الصلاح محدث کی تحریر کردہ مشہور کتاب ہے۔ انھوں نے امام زہری اور اموی خلیفہ عبد الملک بن مروان کا ایک مکالمہ با سند نقل کیا ہے جس سے حکومت یا سرداری کے لیے سیرت و کردار اور دینی خدمت کے جذبے کا سبق ملتا ہے۔ یہ واقعہ اُس دور میں مسلمانوں کی سیاسی فکر اور سماجی حالت کی عکاسی بھی کرتا ہے۔ ملاحظہ کیجیے۔
امام زہری جب عبدالملک بن مروان کے پاس پہنچے تو وہاں بادشاہ سے جو گفتگو ہوئی، اسے یوں رقم کیا ہے
عبدالملک: ’’زہری تم کہاں سے آئے ہو؟‘‘
زہری: مکہ سے
عبدالملک: تم نے وہاں کس کو سردار اور پیشوا چھوڑا؟
زہری: عطا بن رباح کو
عبدالملک: عطا بن رباح عرب ہے یا غلام (عجمی)؟
زہری: عطا غلاموں سے ہے
عبدالملک: عطا غلام ہو کر سردار و پیشوا کیوں کر ہوگیا؟
زہری: ’بالدیانۃ والروایۃ‘ دین داری اور حدیثوں کی روایت کی وجہ سے
عبدالملک: بلاشبہ اہلِ دین و اہلِ روایت ضرور سرداری کے لائق ہیں۔
عبدالملک: یمن کا سردار کون ہے؟
زہری: طاؤس بن کیسان ہیں
عبدالملک: عرب ہیں یا غلام (عجمی)؟
زہری: عجمی غلام
عبدالملک: پھر غلام سردار و پیشوا مسلمانوں کا کیونکر ہوگیا؟
زہری: جس وجہ سے عطا بن ابی رباح سردار و پیشوا ہوئے۔
عبدالملک: ضرور ایسا ہی مناسب ہے۔
عبدالملک: زہری! مصر والوں کا سردار و پیشوا کون ہے؟
زہری: یزید بن حبیب
عبدالملک: یزید بن حبیب عرب ہے یا غلام عجمی؟
زہری: غلام ہیں
عبدالملک: اور شام والوں کا سردار و پیشوا کون ہے؟
زہری: مکحول ہیں
عبدالملک: غلام ہیں یا عرب؟
زہری: غلام ہیں۔ نوبی قوم سے قبیلہ ہزیل کی ایک عورت نے انھیں آزاد کیا تھا۔
عبدالملک: اہلِ جزیرہ کی سرداری کس کے سر ہے؟
زہری: میمون بن مہران کے۔
عبدالملک: میمون غلام ہے یا عرب؟
زہری: غلام ہیں
عبدالملک: خراسان والوں کا سردار کون ہے؟
زہری: ضحاک
عبدالملک: ضحاک عرب ہیں یا غلام؟
زہری: غلام ہیں
عبدالملک: اہل بصرہ کا سردار و پیشوا کون ہے؟
زہری: حسن بن ابی الحسن ہیں
عبدالملک: غلام ہیں یا عرب؟
زہری: غلام ہیں
عبدالملک: کوفہ کی سرداری کس کے سر ہے؟
زہری: ابراہیم نخعی کے
عبدالملک: عرب ہیں یا غلام؟
زہری: عرب ہیں
عبدالملک: بھلا ہو تمھارا اے زہری! تم نے میرے دل سے بوجھ دور کر دیا، خدا کی قسم عرب کی سرداری کا سہرا غلاموں کے سر رہے گا اور غلام لوگ عرب کے پیشوا اور سردار بن جائیں گے۔ یہاں تک کہ انھی کے خطبے منبروں پر پڑھے جائیں گے اور عرب اس کے نیچے ہوں گے۔
زہری: ہاں اے امیر المومنین یہ تو اللہ کا امر اور اس کا دین ہے جو اس کی حفاظت کرے گا سردار و پیشوا ہوگا اور جو اسے ضائع کرے گا گر جائے گا۔
اس مکالمے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت مسلمانوں نے اسلام کے قانونِ مساوات و فضیلت کو کس طرح اپنایا ہوا تھا۔ یہی وہ طرزِ فکر تھا جس نے اس وقت غیر مسلموں کی بڑی تعداد کو اسلام کی جانب مائل کیا اورمسلمانوں نے اپنا اوج دیکھا۔