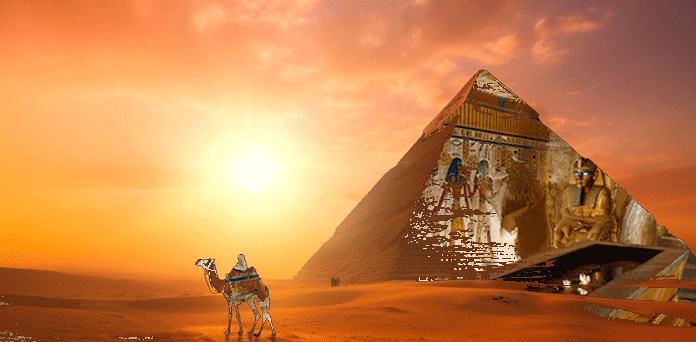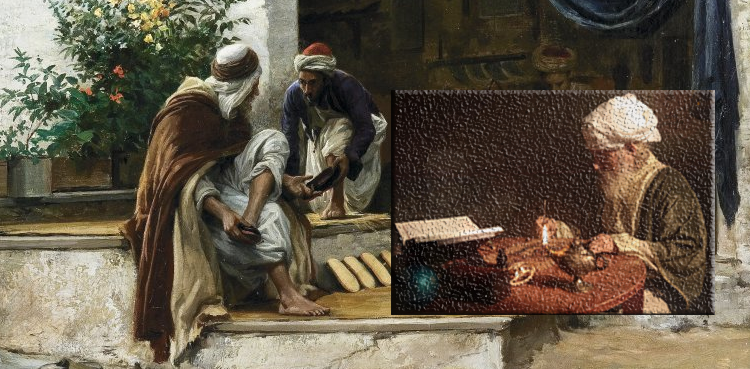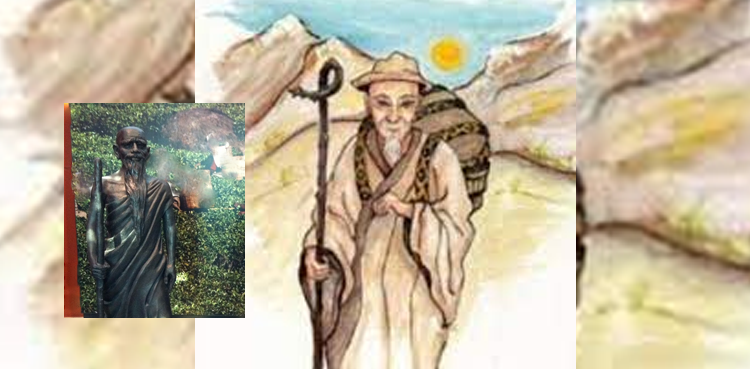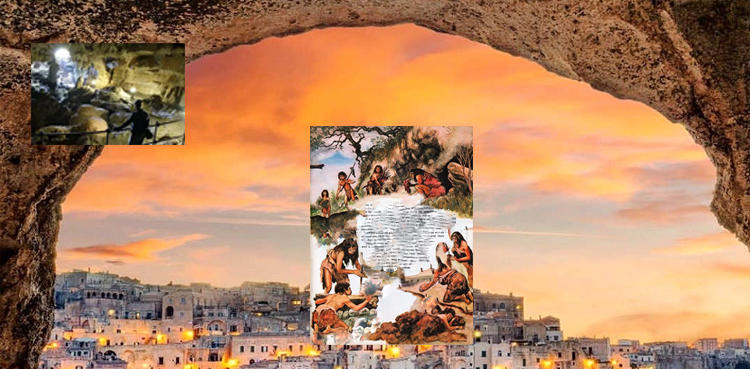مصری تہذیب اور اس کے قدیم ادوار اور وہاں دریافتوں کا جو سلسلہ جاری ہے، اس نے دنیا کو حیران کر رکھا ہے اور لوگ قدیم مصر اور وہاں کے لوگوں کے بارے میں جاننے میں گہری دل چسپی رکھتے ہیں۔ اہرامِ مصر کے بعد وہاں کی تہذیب و ثقافت اور معاشرتی حالات یقیناً اہلِ علم ہی نہیں عام لوگوں کے لیے بھی دل چسپ موضوع ہے۔
قدیم مصر میں عورت کا کردار اور مقام بھی اہم موضوع ہے اور محققین نے اس حوالے سے بعض تاریخی دستاویزات، مخطوطوں اور دریافت شدہ دیگر اشیاء کی مدد سے یہ جانا ہے کہ اس دور میں عورت کو معاشرے میں کس طرح دیکھا جاتا تھا۔ یہاں ہم مختلف خطّوں کے محققین کی مستند کتب کے اردو تراجم سے یہ پارے نقل کررہے ہیں جن میں قدیم مصر میں عورتوں کا مقام واضح کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔
تاریخی دستاویزات کے مطابق ایک دور میں عورتوں کو مرد سے کم تر درجہ میں رکھا گیا تھا جب کہ اس کے اگلے دور میں ان کو مرد کے برابر کے حقوق دے دیے گئے تھے۔ کچھ عورتیں تو باقاعدہ ریاستوں کی ملکہ تک بنائی گئی تھیں۔ اس کے علاوہ عورتوں کو کاروبار کرنے کی بھی اجازت تھی۔ شاہی خاندان کی عورتوں کو شادی کے لیے اپنے بڑوں سے اجازت لینی پڑتی تھی جب کہ عام عورتیں اپنی مرضی سے شادی کر لیا کرتی تھیں۔ قدیم مصری عورتوں کی سماجی درجہ بندی اور ان کے حالات کچھ اس طرح تھے:
شاہی خاندان کی عورتیں
شاہی خاندان کی عورتوں کی قدیم مصری معاشرے میں بہت اہمیت تھی۔ ان کی طاقت فراعین مصر کے برابر تو نہیں تھی لیکن شاہی عورتوں کا سرکاری نظام میں بہت اثر و رسوخ تھا۔ یہ عورتیں یا تو فرعون کی بیویاں ہوتیں یا اس کی باندیاں۔ ایک وقت میں فرعون بہت ساری بیویاں اور باندیاں رکھا کرتے تھے۔ ان عورتوں میں سے فراعین ایک عورت کو اپنا خاص مشیر بنا لیا کرتے تھے۔ اکثر یہ خاص عورت فرعون کی بہن یا سوتیلی بہن ہوتی تھی جس سے وہ نکاح کر لیا کرتے تھے۔ ان کے مطابق اس طرح شاہی خون پاک رہتا اور حکومت بھی ان کے پاس رہتی تھی۔
یہ خاص عورتیں فرعون کے ساتھ مل کر تمام شاہی کاموں میں اس کی معاونت کرتی تھیں۔ سفارتی معاملات میں ان کا اہم کردار ہوتا تھا۔ اس کے علاوہ ان عورتوں کے درمیان اقتدار حاصل کرنے کی جنگ اندرونِ خانہ چلتی رہتی تھی اور اکثر یہ خواتین محل میں فساد برپا کرتی رہتی تھیں۔ بعض عورتیں تو اتنی طاقتور ہوگئی تھیں کہ انہوں نے پورے مصر کی حکومت تک سنبھال لی تھی لیکن ایسے واقعات شاذ و نادر ہی رونما ہوئے تھے۔
حرم کی عورتیں
مصر کا ہر فرعون اپنے لیے خاص عورتوں کا ایک حرم قائم رکھتا تھا جو فرعون کو سکون و عیاشی کی سہولیات میسر کرنے کے لیے مختص تھا۔ ان عورتوں کی اکثریت ان خواتین پر مشتمل ہوتی جو غیر ملکی ہوتیں اور جنگ کے بعد غلام بنا کر یا پھر کسی غلام منڈی سے خرید کر یا فرعون کی منشا کے مطابق کسی کے بھی گھر سے اٹھا کر لائی جاتی تھیں۔ یہ عورتیں ناچنے، گانے، اور دیگر حرم کے مشاغل میں ماہر ہوا کرتی تھیں۔ ان کے فرائض میں یہ بات شامل تھی کہ بادشاہ کو دربار میں بھی محظوظ کریں۔ بادشاہ کے حرم میں صرف کنیزیں اور قیدی عورتیں ہی نہیں ہوتی تھیں بلکہ ان میں شرفا کی بیٹیاں اور وہ عورتیں بھی شامل تھیں جو بطور تحفہ بادشاہ کے پاس بھیجی جاتی تھیں۔
چونکہ حرم میں خواتین کی تعداد بہت زیادہ ہوا کرتی تھی اس لیے ایک عورت کو فرعون کے ساتھ سال میں ایک یا دو بار ہی رات گزارنے کا موقع ملتا تھا۔ اگر کوئی باندی فرعون کو پسند آجاتی تو پھر فرعون اس کو اپنے آس پاس رکھتا تھا۔ اگر فرعون کی بیوی اس کو لڑکا جن کر نہ دے پاتی تو فرعون اپنی من پسند باندی کے ساتھ تعلق قائم کر کے اس سے اولاد حاصل کرتا اور یہ لڑکا شہزادہ کہلاتا اور اسے بعد میں تخت پر بٹھایا جاتا۔
عورتوں کی ذمہ داریاں
اکثر عورتوں کا کام گھر سنبھالنا اور اولاد کی پرورش کرنا تھا۔ دیگر عورتیں یا تو دائی بن جاتیں، یا کپڑے بنانے والے کارخانوں میں کام کرتیں یا پھر گریہ کرنے والی، حاتھور دیوتا کی کاہنہ یا پجارن، یا پھر جسم فروشوں کے بازار میں کام کرنے لگ جاتی تھیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ عورت کو اس کی جنس کے مطابق کام دیا جاتا تھا اور یہ کام وقتا ًفوقتاً تبدیل بھی کر دیا جاتا تھا۔ ان کو کاروبار کرنے کی بھی اجازت تھی۔ طبیب بھی بننے دیا جاتا اور جب ضرورت نہیں ہوتی تو پھر ان کو صرف بچوں کی دیکھ بھال، ناچنے، گانے اور مردوں کا دل بہلانے کے کام میں لگا دیا جاتا تھا۔
غلام کی مالکن
قدیم مصر میں عام رواج تھا کہ عورتیں غلام کے طور پر صرف عورتوں کو ہی رکھتی تھیں لیکن بعض کو مرد غلام رکھنے کی بھی اجازت تھی۔ یہ مرد غلام عموماً ان کی جنسی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے رکھے جاتے اور اگر وہ غلام ایسا نہ کرتے یا کسی اور عورت کے ساتھ ناجائز تعلق بناتے تو ان کو مارا پیٹا جاتا اور سخت سزائیں دی جاتی تھیں۔
شادی
زرخیزی چاہے انسانوں میں ہو یا جانوروں میں یا فصل کی پیداوار میں، قدیم مصریوں کے نزدیک اس کی بہت اہمیت تھی۔ یہی وجہ تھی کہ مصری لوگ جلد سے جلد شادی کر کے بچّے پیدا کرنے کی خواہش رکھتے تھے۔ مصریوں کے ہاں محرمات سے شادی کی اجازت تھی اور شاہی خاندان تو اکثر اسی رسم کو اپنایا کرتے تھے۔ اس دور میں بہن بھائی کے درمیان شادی کا عام رواج تھا۔ اس کے علاوہ فرعون اپنی سلطنت کو اپنے ہی خاندان میں رکھنے کے لیے اپنی ماں، بیٹی اور دیگر محرمات کو بھی اس تعلق میں اپنا لیتے تھے۔
شادی کے لیے کوئی مذہبی یا قانونی رسوم ادا نہیں کی جاتی تھیں۔ اکثر نکاح والدین کی باہم رضامندی سے مقرر ہوتے اور سارے معاملات پہلے طے کر لیے جاتے تھے۔ کچھ مقامات پر محبت کی شادیاں بھی ہوئیں لیکن ایسا شاذ ہی ہوتا تھا۔ جب لڑکا پندرہ سے بیس سال کا ہوتا اور لڑکی بارہ سے چودہ سال کی ہوجاتی تو ان کی شادی کردی جاتی تھی۔ بادشاہ ایک سے زائد شادیاں کر سکتا تھا لیکن عام لوگ صرف ایک ہی شادی کرتےتھے۔ اس کے علاوہ عام لوگوں کو اجازت تھی کہ وہ ایک محبوبہ یا باندی رکھ لیں جس سے خواہش کے مطابق تسکین پوری کرسکیں۔
علیحدگی
شادی کے وقت دولھا دلھن یہ گمان کرتے کہ ان کا ساتھ مرتے دم تک قائم رہے گا لیکن ایسا ہمیشہ نہیں ہو پاتا تھا۔ ان میں سے کچھ جوڑوں کے درمیان طلاق بھی واقع ہو جاتی تھی۔ طلاق کے بعد مرد اور عورت الگ الگ رہا کرتے۔ طلاق قانونی طریقہ سے ہوتی تھی جس کے بعد مرد اور عورت کو دوسری شادی کی اجازت تھی۔ اگر مرد عورت کو طلاق دیتا تو اس پر واجب تھا کہ وہ عورت کا تمام جہیز واپس لوٹا دے بلکہ کچھ معاملات میں تو اس کا دگنا بھی لوٹانے کا کہا جاتا تھا۔ اگر عورت طلاق دیتی تو اس پر واجب تھا کہ جو اسے شادی کے وقت مرد کی طرف سے تحفہ ملا ہو، اس کی آدھی مقدار واپس کرے۔ طلاق کے بعد بھی مرد پر واجب تھا کہ وہ عورت کو نان نفقہ دیتا رہے جب تک وہ دوسری شادی نہ کرلے۔
لباس
مصری لباس میں زمانہ کےساتھ تبدیلیاں ہوتی رہیں۔ قدیم سلطنت کے دور میں عورتیں اور مرد نیم برہنہ رہتے تھے۔ جسم کا بالائی حصہ بالعموم کھلا رہتا تھا۔ پروہتوں کو بھی مجسموں میں نیم برہنہ دکھایا گیا ہے۔ سلطنت وسطی اور سلطنت جدید میں کُرتے، تہبند اور دستار کا اضافہ ہوا تھا۔ عورتوں کے لباس میں کُرتے اور تہبند کےعلاوہ ایک لمبا چوڑا دوپٹہ بھی شامل کیا گیا تھا جو شانے اور سینے پر پھیلا ہوتا مگر کھلا رہتا تھا۔ اونچے طبقے کی عورتیں ایک قسم کا تاج پہنتی تھیں۔ لباس پر گاڑھے اور زردوزی کا کام ہوتا تھا۔ بالوں کو تراشنے اور مانگ نکالنے کے بھی مختلف طریقے رائج تھے۔ رؤسا کے کپڑے بالعموم باریک دھاگے کے ہوتے تھے جن پر زر کا کام کیا جاتا تھا۔ منقش اور چھپے ہوئے کپڑوں کا استعمال بھی عام تھا۔ مرد و عورت دونوں مصنوعی بال کی ٹوپیاں پہنتے تھے۔ اونچے طبقے میں چپلوں کا رواج تھا۔غرض مصری زندگی میں نفاست اور خوش سلیقگی کے ساتھ ساتھ نزاکت اور عریانیت بھی آگئی تھی۔
(ماخذ: مختلف محققین کی کتب کے اردو تراجم)