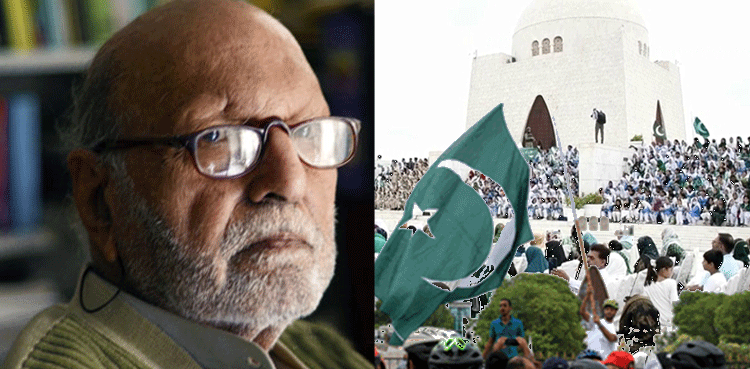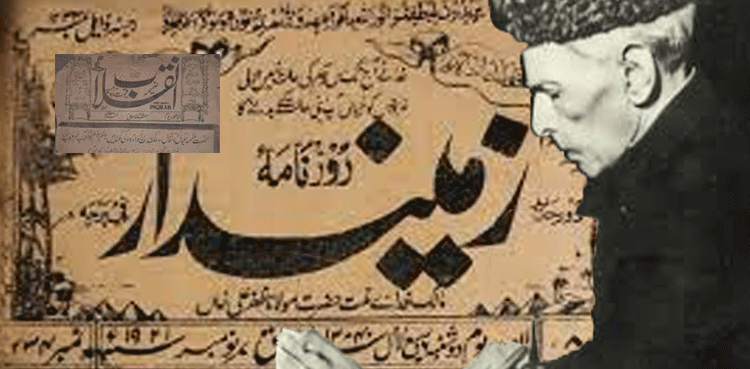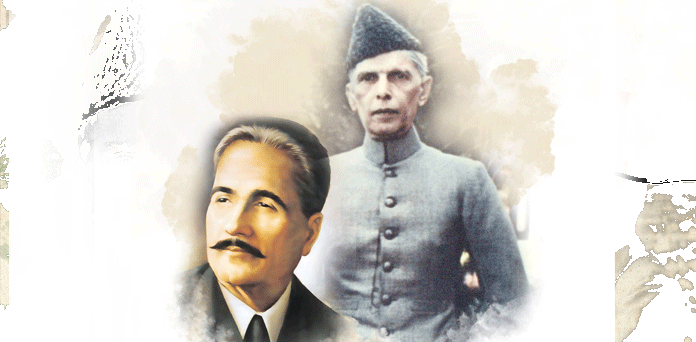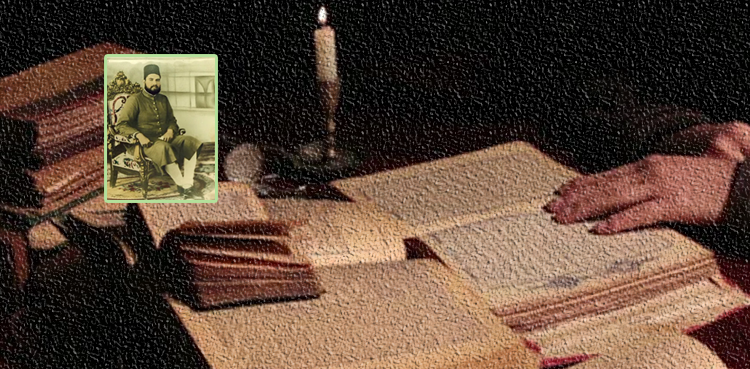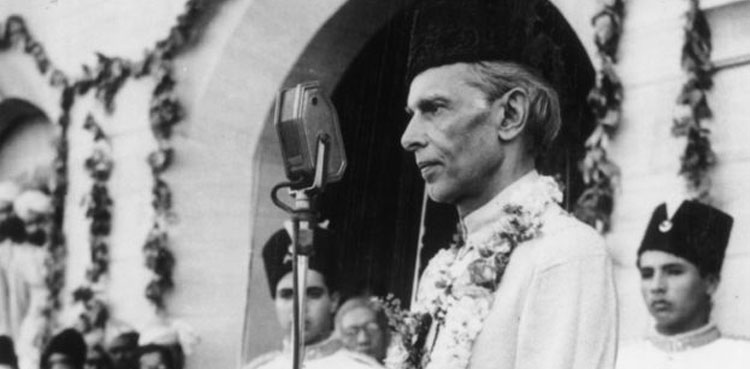تخلیقِ پاکستان کے بعد ادب میں جو تحریکیں رونما ہوئیں، ان میں پاکستانی ادب کی تحریک اور ارضی ثقافتی تحریک کو فنی اور فکری لحاظ سے اہمیت حاصل ہے۔ یہ دونوں تحریکیں بظاہر حلقہ اربابِ ذوق کے مثبت زاویوں کی توسیع نظر آتی ہیں اور ان کی فنی جہت میرا جی کے شعورِ ماضی سے پھوٹتی ہے۔
تاہم ان دونوں تحریکوں میں ترقی پسند تحریک کے خلاف ردعمل کا شدید جذبہ اور ارض وطن سے گہری وابستگی کا تصور بھی کارفرما تھا۔ ان عوامل کا اثر بھی ہے جو 1857ء کی جنگ آزادی کے بعد پیدا ہوئے اور جن سے برصغیر کی بیشتر تحریکوں نے جنم لیا۔ علامہ اقبال کی انفرادیت یہ ہے کہ انہوں نے امتِ مرحوم کا مرثیہ لکھنے اور مریضانہ ماضی پرستی میں مبتلا ہونے کے بجائے قوم میں خود اعتمادی پیدا کی، اسے فعال لہجہ عطا کیا اور زمانۂ حال میں ماضی کی عظیم روایت کی تجدید کرنے کے لیے اسے صحت مند ارتقا کی علامت بنا دیا۔ علامہ اقبال کی تحریک ان معانی میں ارضی ثقافتی تحریک بھی شمار کی جا سکتی ہے کہ انہوں نے فرد کو عروجِ سماوی حاصل کرنے کے باوجود پا بہ گل ہونے کا احساس دلایا۔
اقبال کی اس تحریک کا ہی نتیجہ تھا کہ ملک میں قومی شاعری کی ترویج ہوئی، غزل کی عجمی لے اور عشقیہ انداز میں تبدیلی واقع ہوئی اور علائم رموز اور موضوعات میں برصغیر کے مظاہر و مناظر کا استعمال ہونے لگا۔ اس تحریک کو ایک اور کروٹ میرا جی اور حلقۂ اربابِ ذوق کے ادبا نے دی۔
پاکستانی ادب کی تحریک
آزادی کے فوراً بعد ادب میں جو اوّلین تحریک رونما ہوئی اس نے ارض پاکستان کی نسبت سے زمین کے اور اسلامی نظریات کے حوالے سے، آسمان کے عناصر کی اہمیت کو تسلیم کیا اور نئے ادب کی تخلیق کے لیے اب دونوں کا امتزاج ضروری قرار دیا۔ چنانچہ اس تحریک نے ریاست سے وفاداری اور پاکستانی ادب کا سوال پیدا کیا۔ اس تحریک کے علمبردار حلقۂ اربابِ ذوق کے ایک رکن محمد حسن عسکری تھے اور اس کی نظریاتی اساس کو ڈاکٹر صمد شاہین، ڈاکٹر جمیل جالبی، ممتاز شیریں، سجاد باقررضوی اور سلیم احمد نے اپنے مضامین سے تقویت پہنچائی۔
پاکستان ادب کی تحریک ادبی سطح پر قومیت کو ابھارنے والی ایک اہم تحریک تھی، اس تحریک نے زمین کو آسمان کے تابع قرار دے کر قومی سطح پر ادب پیدا کرنے کی طرح ڈالی۔ چنانچہ اس پر سب سے پہلے مخالفانہ حملہ ترقی پسند تحریک نے کیا اور اس کی نظریاتی اساس کو دلیل سے رد کرنے کے بجائے اس تحریک کے ادبا سے عدم تعاون کا منصوبہ بنا لیا۔ ہر چند اس قسم کا سیاسی عمل ادب کے ارتقا میں رکاوٹ نہیں بنتا۔ تاہم المیہ یہ ہوا کہ اس تحریک نے اپنی نظریاتی بنیاد تو استوار کر لی، لیکن اس کی صداقت کو تخلیقی سطح پر ثابت کرنے کے لئے اچھے شاعروں اور افسانہ نگاروں کا تعاون حاصل نہ ہو سکا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ یہ تحریک معنوی اور تخلیقی طور پر زیادہ عرصے تک زندہ نہ رہ سکی اور ترقی پسند تحریک پر پابندی لگ جانے کے بعد جب اس کا ادبی حریف میدان سے ہٹ گیا تو تحریک دوبارہ حلقۂ اربابِ ذوق میں فطری طور پر ضم ہو گئی۔ چنانچہ حلقے کی تحریک میں انتظار حسین، احمد مشتاق، سجاد باقر رضوی، ناصر کاظمی اور مظفر علی سید جیسے ادبا نے تہذیبی شعور کا جواز پیدا کیا، معنوی طور پر یہ متذکرہ تحریک کا ہی حصہ نظر آتا ہے۔
ارضی ثقافتی تحریک
پاکستانی ادب کی تحریک نے جن فکری مسائل کو ابھارا تھا، ان کی نسبتاً بدلی ہوئی صورت ارضی ثقافتی تحریک میں رونما ہوئی۔ اس تحریک نے اقبال سے یہ نظریۂ اکتساب کیا کہ ثقافت اور اس کا مظہر ادب، زمین اور آسمان کے رشتوں سے متشکل ہوتا ہے اور ترقی پسند تحریک سے اس حقیقت کو اخذ کیا کہ تخلیق میں زمین بنیادی حیثیت رکھتی ہے۔ اس تحریک کا امتیازی نکتہ یہ ہے کہ اس نے مذہب کو زمینی رشتوں کی تہذیب کا ایک مقدس انعام اور انسانی شعور کو لاشعور میں پھوٹنے والا چشمہ قرار دیا۔ چنانچہ اس تحریک نے ’’سماجی ہمہ اوست‘‘ مرتب کرنے کے بجائے فرد کو اجتماع کا ضروری جزو قرار دیا اور اس کی انفرادیت کا اثبات بھی کیا۔ ترقی پسند تحریک نے زمین کو اہمیت عطا کی تو اس کا مقصد زمین کے واسطے سے ایک مادی نظام کی تشکیل اور ایک ایسے غیر طبقاتی معاشرے کا فروغ تھا جو زمین سے ایک دودھ پیتے بچے کی طرح چمٹا ہوا ہو۔ ترقی پسند تحریک کا یہ مسلک اپنی ممکنات کے لحاظ سے محدود اور مزاج کے اعتبار سے خالصتاً مادی تھا۔ ارضی ثقافتی تحریک نے زمین کے وسیلے سے نہ صرف ثقافتی عناصر کو قبول کیا بلکہ اجتماعی لاشعور کو ایک ارضی رشتہ قرار دے کر ادب اور فکری تشکیل میں نسلی اور روحانی سرمائے کو بھی ناگزیر قرار دیا۔ چنانچہ ارضی ثقافتی تحریک نے جسم کے مادی وجود کے بجائے جسم کے روحانی ارتقا کو اہمیت دی اور یوں آسمانی اور زمینی عناصر کے متوازن امتزاج سے اب اور فن کی نئی اور متنوع صورتیں پیدا کرنے کی سعی کی۔
ارضی ثقافتی تحریک کی نظریاتی اساس ڈاکٹر وزیر آغا کے تفکر کا نتیجہ ہے۔ ان کا اساسی مؤقف یہ ہے کہ ثقافت زمین اور آسمان کے تصادم سے جنم لیتی ہے۔ تاہم اس تصاد م میں آسمان کا کردار ہنگامی اور اضطراری ہے…آسمانی عناصر کے بغیر زمین بالکل بانجھ ہو کر رہ جاتی ہے۔
پاکستان کی ثقافت اور ادب کے بارے میں ڈاکٹر وزیر آغا کا مؤقف ہے کہ اس کی تشکیل میں مذہب کے گہرے اثرات کے علاوہ پاکستا ن کی مٹی، ہوا، موسم اور اس کی تاریخ نے بھی اہم کردار ادا کیا۔ پاکستان کی مٹی کی کہانی ہند اسلامی ثقافت کے دور سے بہت پہلے ان ایام میں پھیلی ہوئی ہے ، جب اس خطۂ ارض پر وادیٔ سندھ کی تہذیب نے جنم لیا تھا۔ پاکستان کی مٹی کی اس کہانی کا دوسرا پہلو داخلی ہے۔ یعنی اس نے قوم کی سائیکی میں ان تمام نسلی اثرات کو محفوظ رکھا ہے جو ہزاروں برس کے نسلی تصادم سے پیدا ہوئے ہیں۔ چنانچہ ادب کی تنقید میں اساطیری عناصر اور Archetypal Images کی دریافت ناگزیر ہے۔ گویا ارضی ثقافتی تحریک نے انسانی کے پورے ماضی سے رشتہ استوار کیا اور اب ادب کی تخلیق کو انسانی سائیکی کا کرشمہ قرار دیا۔ ہند اسلامی ثقافت کی ابتدا اس سرزمین سے ہوئی اور باہر سے آنے والے اثرات نے اس سرزمین کے مزاج کا حصہ بنتے گئے توں توں ثقافت میں بھی نئی پرتیں پیدا ہوتی گئیں۔ اس لحاظ سے یہ تحریک پاکستانی ثقافت اور ادب کی گہرائی اور تنوع کی نشاندہی کرتی ہے۔
پاکستان اور بھارت کی دو جنگوں نے اس تحریک کے ارضی اور روحانی تصور کو مزید تقویت دی۔ ان جنگوں کے بعد حب الوطنی اور ارض پاکستان سے روحانی وابستگی کا جذبہ شدت سے بیدار ہوا۔ اس کی صورت تو ’’سوہنی دھرتی‘‘ کے تصور میں ابھری اور دوسری صورت یہ ہوئی کہ شہروں اور قصبوں سے جذباتی وابستگی کا شدید ترین جذبہ پیدا ہو گیا۔ تیسرے شعرا نے نظریاتی تعصب سے بلند ہو کرارض وطن کی خوشبو کو جبلی سطح پر محسوس کیا اور اپنے گردوپیش کو شعری اظہار کے ساتھ منسلک کردیا۔ چنانچہ زمین کی خوشبو نہ صرف شاعری میں رچ بس گئی بلکہ یہ قاری کے مشامِ جان کو بھی معطر کرنے لگی۔
ارضی ثقافتی تحریک نے صرف نظریاتی اساس ہی مرتب نہیں کی بلکہ اس کے نقوش کئی ادبا کی تخلیقات میں بھی جلوہ گر نظر آتے ہیں، تنقید میں ڈاکٹر وزیر آغا کی کتاب ’’اردو شاعری کا مزاج‘‘ اس تحریک کی نظریاتی بوطیقا ہے۔ ڈاکٹر سہیل بخاری نے اردو زبان کے فطری ارتقا میں زبانوں کی آمیزش کو ناگزیر قرار دے کر اس تحریک کے ثقافتی مزاج کو ہی ابھارا ہے۔ مشتاق قمر، جمیل آذر، ڈاکٹر غلام حسین اطہر اور سجاد نقوی کی تنقید میں آسمانی اور زمین عناصر کا امتزاج موجود ہے۔ شاعری میں وزیر آغا کی بیش تر علامتیں ارضی ثقافتی پس منظر کی حامل ہیں۔ اعجاز فاروقی کی شاعری کی جڑیں پاکستان کے گہرے ماضی میں اتری ہیں۔ فسانے میں اس تحریک کو غلام ثقلین نقوی، صادق حسین، رشید امجد اور مشتاق قمر نے تقویت دی۔ غلام ثقلین نقوی کے افسانوں میں وطن محض ایک خطہ زمین نہیں بلکہ سانس لیتا ہوا ایک زندہ کردارہے جو اپنے تاثر کا اظہار بھی کرتا ہے۔ صادق حسین کے افسانے پاکستانی آرزوؤں، ولولوں اور تمناؤں کے جگمگاتے ہوئے مرقعے ہیں۔ مشتاق قمر نے ان کرداروں کو موضوع بنایا ہے جو ارض وطن کے لیے نقد جان پیش کرنے کا حوصلہ رکھتے ہیں۔ رشید امجد کے افسانوں میں شعور ماضی انسان کے مشترکہ نسلی سرمائے کی صورت میں ظاہر ہوا ہے اور وہ انسانی سائیکی کی ان لکیروں کو تلاش کرتا ہے جن کے اوّلین نقوش ٹیکسلا میں متحجر ہیں لیکن جن کی زندہ صورت پاکستان کے گلی کوچوں میں رواں دواں ہے۔
(ممتاز پاکستانی نقّاد، محقق اور شاعر ڈاکٹر انور سدید کے مضمون سے اقتباسات)