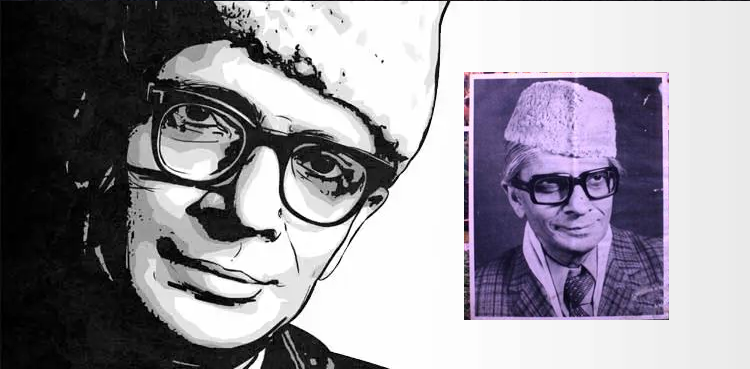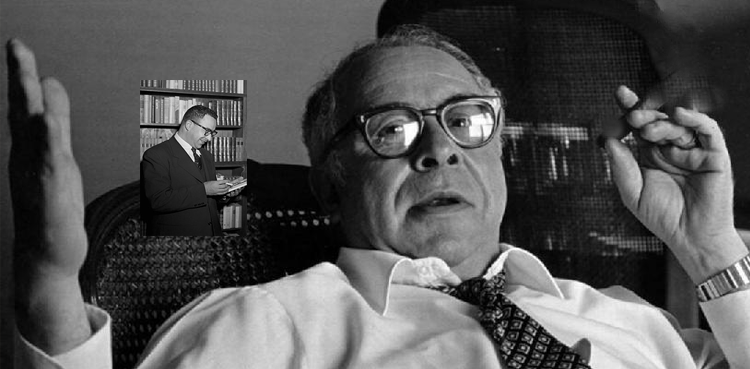ونسٹن چرچل کو دنیا ایک مدبّر اور زیرک سیاست داں اور سفاک حکم راں کہتی ہے۔ چرچل کو سخت متعصب، موقع پرست اور احساسِ برتری کا شکار بھی کہا جاتا ہے جس نے دوسری قوموں کی معاشرت اور مذاہب کی نہ صرف تحقیر کی بلکہ ان کے حوالے سے بے رحم اور سفاک ثابت ہوا۔ چرچل کی اکثر تقاریر اس کی کوتاہ بینی اور پست ذہنیت کا بھی ثبوت ہیں۔
تاریخ کے اوراق بتاتے ہیں کہ سَر ونسٹن چرچل گیارہ برس تک برطانیہ کا وزیرِ اعظم اور وہاں کے عوام کا ہیرو بھی رہا، لیکن برصغیر کی بات کی جائے تو یہاں وہ ایک سفاک حکم راں سمجھا جاتا ہے جو لاکھوں انسانوں کی موت کا ذمہ دار بھی تھا۔
اس سے قطع نظر اگر چرچل کے ذوق و شوق کی بات کی جائے تو وہ علم و فنون کا دلدادہ تھا۔ چرچل خود بھی ایک مصنّف اور بہترین مصوّر تھا۔ اس برطانوی سیاست داں اور لیڈر کے بارے میں مزید جاننے سے پہلے سر سیّد احمد خان کی ایک تحریر پڑھیے:
"انسان کی خصلتوں میں سے تعصّب ایک بدترین خصلت ہے۔ یہ ایسی بدخصلت ہے کہ انسان کی تمام نیکیوں اور اس کی تمام خوبیوں کو غارت اور برباد کرتی ہے۔ متعصّب گو اپنی زبان سے نہ کہے، مگر اس کا طریقہ یہ بات جتلاتا ہے کہ عدل وانصاف اس میں نہیں ہے۔ متعصّب اگر کسی غلطی میں پڑتا ہے تو اپنے تعصّب کے سبب اس غلطی سے نکل نہیں سکتا، کیوں کہ اس کا تعصّب اُس کے برخلاف بات سننے، سمجھنے اور اُس پر غور کرنے کی اجازت نہیں دیتا اور اگر وہ کسی غلطی میں نہیں ہے، بلکہ سچّی اور سیدھی راہ پر ہے تو اس کے فائدے اور اس کی نیکی کو پھیلنے اور عام ہونے نہیں دیتا۔”
سر سیّد جیسے عظیم لیڈر اور مصلح قوم نے تعصّب اور قوم پرستی کو بدترین قرار دیا ہے اور چرچل اسی کا شکار تھا جس نے بالآخر ہندوستان میں عوام کو بدترین حالات سے دوچار کیا۔ ایک موقع پر چرچل نے کہا تھا کہ اُسے ہندوستانیوں سے نفرت ہے۔ اس نے ہندوستان میں بسنے والوں کو وحشی قوم کہا تھا۔ وہ یہاں کے لوگوں ہی سے متنفر نہیں تھا بلکہ ہندوستان کے مختلف مذاہب کے لیے بھی اس نے اپنی بیزاری اور شدید ناپسندیدگی ظاہر کی تھی۔ تاہم نو آبادیاتی دور میں برطانوی حکومت کے بارے میں متضاد آرا پڑھنے کو ملتی ہیں۔ مغربی مصنّفین ہی نہیں اُس وقت کے بعض ہندو اور مسلمان راہ نما بھی برطانوی حکومت میں مختلف منصب پر فائز رہتے ہوئے چرچل کے اقدامات کو بُرا نہیں سمجھتے۔
دنیا دوسری جنگِ عظیم میں برطانیہ اور اس کے اتحادیوں کی جرمنی کے خلاف فتح کو چرچل کی دور اندیشی اور مدبّرانہ سوچ اور حکمتِ عملی کا نتیجہ قرار دیتی ہے۔ بعض سیاسی مبصرین، مؤرخین نے لکھا ہے کہ چرچل نہ ہوتا تو شاید آج دنیا کی سیاسی اور جغرافیائی تاریخ کچھ مختلف ہوتی، لیکن اس کے باوجود ونسٹن چرچل کی شخصیت آج بھی اکثر لوگوں کے لیے ناپسندیدہ ہے۔
برطانوی راج میں طوفان اور سیلاب کے ساتھ بنگال میں شدید قحط سے اموات اور مشرقِ وسطیٰ میں اسرائیل کے قیام میں چرچل کا کردار بھی موضوعِ بحث رہا ہے۔ بنگال میں قحط سے ہلاکتوں اور لاکھوں انسانوں کے متاثر ہونے کا زمانہ وہی ہے جب برطانیہ میں ونسٹن چرچل پہلی مرتبہ وزیرِ اعظم منتخب ہوا۔ نوآبادیات پر متعدد برطانوی اور ہندوستانی تاریخ نویسوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ اعلیٰ افسران نے اپنی حکومت کو تحریری طور پر قحط کی تباہ کاریوں اور لاکھوں انسانی زندگیوں کو درپیش خطرے سے آگاہ کرتے ہوئے خوراک اور دوسری امداد کی درخواست کی تھی، لیکن انھیں نظر انداز کر دیا گیا۔
کہا یہ بھی جاتا ہے کہ چرچل نے جان بوجھ کر لاکھوں ہندوستانیوں کو بھوکا مرنے دیا۔ یہ بات ہے 1942ء کی جب سمندری طوفان اور سیلاب کے باعث بنگال میں قحط پڑ گیا تھا اور خوراک نہ ملنے سے لاکھوں انسان لقمۂ اجل بن گئے، اُس وقت برطانوی وزیرِاعظم کا خیال تھا کہ مقامی سیاست دان بھوک سے مرتے ہوئے لوگوں کی بہتر مدد کرسکتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ برطانوی حکومت کے اس رویّے کے باعث بنگال میں صورتِ حال بگڑتی گئی اور ایک انسانی المیہ نے جنم لیا۔ چرچل کو امریکیوں کے استحصال کا ذمہ دار بھی کہا جاتا ہے۔ دراصل ونسٹن چرچل خود کو ایک برطانوی ہونے کے ناتے دنیا کی دیگر اقوام سے برتر خیال کرتا تھا اور اس بے جا احساسِ تفاخر نے اسے اپنے جیسے ہی کروڑوں انسانوں کی عزّتِ نفس کو مجروح کرنے پر آمادہ کر لیا تھا۔ اس کی نظر میں دنیا کی دیگر اقوام کا احترام نہیں رہا تھا۔
ونسٹن چرچل 30 نومبر 1874ء کو آکسفورڈ شائر میں پیدا ہوا۔ وہ کم و بیش دس سال برطانیہ میں وزارتِ عظمیٰ کے عہدے پر فائز رہا اور 24 جنوری 1965ء کو لندن میں چل بسا تھا۔
بحیثیت سیاست داں اپنا سفر شروع کرنے سے قبل چرچل ہندوستان کی شمال مغربی سرحد اور پھر جنوبی افریقہ میں ایک سپاہی اور اخباری نمائندے کی حیثیت سے خدمات انجام دے چکا تھا۔ 1901ء میں چرچل پہلی بار پارلیمنٹ کا رکن بنا اور بعد میں وزارتِ خزانہ اور داخلہ میں خدمات انجام دیں اور بعد میں وہ وزارتِ عظمٰی کے منصب پر فائز ہوا۔
چرچل برطانیہ کی کنزرویٹو اور لبرل پارٹی کا حصّہ رہا اور عملی سیاست کے ساتھ تصنیف و تالیف کا شغل بھی جاری رکھا۔ وہ متعدد کتب کا مصنّف تھا۔ چرچل نے بطور مصوّر کئی فن پارے تخلیق کیے جن میں ایک فن پارہ اس کا شاہکار مانا جاتا ہے جو مراکش کی مشہور جامع مسجد، مسجدِ کتبیہ کا ہے۔ یہ مسجد 1184ء میں تعمیر کی گئی تھی۔ یہ پینٹنگ چرچل نے دوسری عالمی جنگ کے دوران سابق امریکی صدر روز ویلٹ کے لیے بنائی تھی۔ چرچل کی بنائی ہوئی یہ تصویر عالمی شہرت یافتہ امریکی اداکارہ انجیلینا جولی کی ملکیت تھا جسے چند سال قبل ہی ایک کروڑ 15 لاکھ ڈالر (ایک ارب 80 کروڑ روپے) میں نیلام کیا گیا۔ چرچل کی اس کی پینٹنگ کو ٹاور آف کتبیہ کے نام سے محفوظ کیا گیا ہے۔ اس فن پارے میں چرچل نے مسجد کے مینار اور ارد گرد کی منظر کشی کی ہے۔ کہتے ہیں کہ اس مسجد کے ساتھ لگ بھگ دو ڈھائی سو کتابوں کی دکانیں موجود تھیں اور اسی مناسبت سے اسے مسجدِ کُتبیہ پکارا جانے لگا تھا۔
برطانیہ کی اس ممتاز مدبّر اور باتدبیر مگر متنازع شخصیت کو 1953ء میں ادب کا نوبیل انعام بھی دیا گیا تھا۔ چرچل کی زندگی کے مختلف ادوار کا احاطہ کرنے کے لیے کئی ابواب باندھنا ہوں گے، کیوں کہ بطور برطانوی وزیر مختلف جنگوں اور محاذوں کے دوران وہ اپنی رائے، بعض فیصلوں اور احکامات کی وجہ سے بھی نمایاں ہوا اور وزیراعظم کے منصب پر رہتے ہوئے اس نے بہت اہم اور ایسے فیصلے کیے جن کا تعلق برطانویوں اور دوسرے ممالک میں بسنے والوں کی زندگی سے تھا اس کے علاوہ وہ اپنے قلم اور مُوقلم کے ذریعے بھی اپنے نظریات اور افکار کا اظہار کرتا رہا جس پر بہت کچھ لکھا جاسکتا ہے۔