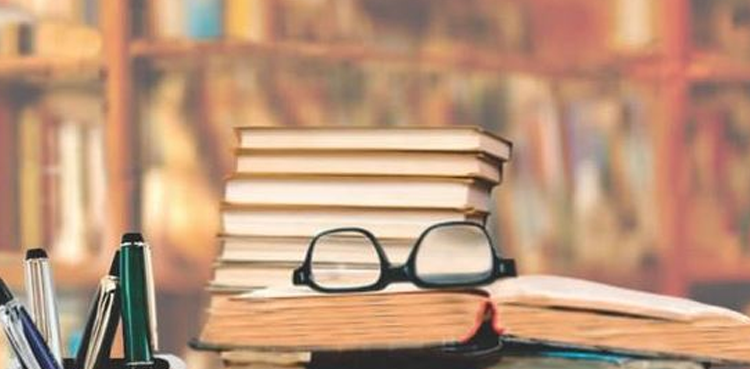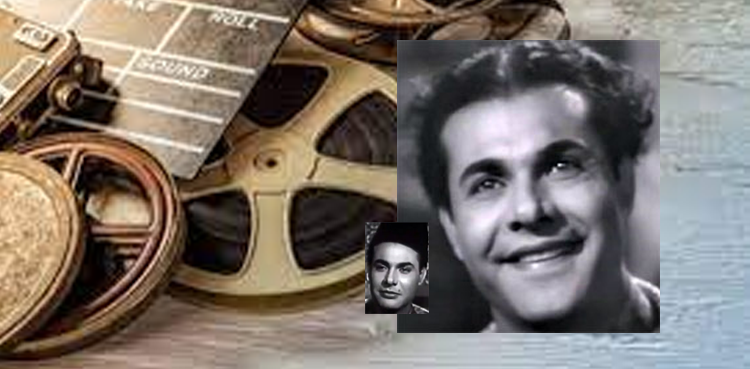اردو ادب میں محسن بھوپالی کا نام ایسے شاعر کے طور پر ہمیشہ زندہ رہے گا جس نے خود کو رائج اصنافِ سخن میں طبع آزمائی تک محدود نہیں رکھا بلکہ اپنے تخلیقی جوہر اور کمالِ فن سے کوچۂ سخن کو نکھارا اور اسے ایک نئی صنف ’’نظمانے‘‘ سے آراستہ کیا۔ آج اردو زبان کے ممتاز شاعر محسن بھوپالی کی برسی ہے۔
محسن بھوپالی نے اردو زبان میں غزل جیسی معتبر اور مقبول صنفِ سخن میں اپنے جذبات اور احساسات کو نہایت خوب صورتی سے بیان کیا اور ہر خاص و عام میں مقبول ہوئے۔ انھوں نے اپنی شاعری سے عام قارئین کی توجہ حاصل کی اور ہم عصر شعرا سے بھی داد پائی۔ اردو ادب کے نقّادوں نے بھی محسن بھوپالی کے فنِ شاعری کو سراہا ہے۔ محسن بھوپالی 17 جنوری 2007ء کو انتقال کرگئے تھے۔
محسنؔ بھوپالی کا اصل نام عبدالرّحمٰن تھا۔ انھوں نے 1932ء میں بھوپال کے قریب واقع ہوشنگ آباد کے ایک قصبے سہاگپور میں آنکھ کھولی۔ 1947ء میں ان کا خاندان پاکستان آگیا اور لاڑکانہ میں سکونت اختیار کی۔ محسن بھوپالی نے این ای ڈی انجینئرنگ کالج کراچی سے سول انجینئرنگ میں ڈپلومہ کورس کے بعد 1952ء میں محکمۂ تعمیرات حکومتِ سندھ میں ملازمت اختیار کر لی۔ ان کی ملازمت کا سلسلہ 1993ء تک جاری رہا۔ اسی عرصے میں انھوں نے جامعہ کراچی سے اردو میں ایم اے کی ڈگری حاصل کی۔
زمانۂ طالبِ علمی کے بعد نوکری کا آغاز ہوا، تب بھی محسن بھوپالی ادبی سرگرمیوں میں حصّہ لیتے رہے۔ ان کی شاعری بھی مختلف اخبارات، ادبی رسائل کی زینت بنتی رہی جس نے انھیں باذوق حلقوں میں متعارف کروایا۔ مقامی سطح پر منعقدہ مشاعروں میں شرکت اور علمی و ادبی حلقوں میں پہچان بنانے والے محسن بھوپالی کو کراچی اور ملک کے دوسرے شہروں سے بھی مشاعرہ پڑھنے کی دعوت ملنے لگی اور ان کا کلام ہم عصر شعراء اور باذوق سامعین نے بہت پسند کیا۔ بطور شاعر جلد ہی ملک گیر شہرت حاصل کرنے والے محسن بھوپالی نے شعر گوئی کا آغاز 1948ء میں کیا تھا۔
محسن بھوپالی کے مجموعہ ہائے کلام شکستِ شب، جستہ جستہ، نظمانے، ماجرا، گردِ مسافت کے عنوان سے شایع ہوئے۔ ان کی دیگر کتابوں میں قومی یک جہتی میں ادب کا کردار، حیرتوں کی سرزمین، مجموعۂ سخن، موضوعاتی نظمیں، منظر پتلی میں، روشنی تو دیے کے اندر ہے، جاپان کے چار عظیم شاعر، شہر آشوب کراچی اور نقدِ سخن شامل ہیں۔
یہ منفرد اعزاز بھی محسنؔ بھوپالی کو حاصل تھا کہ 1961ء میں ان کے اوّلین شعری مجموعے کی تقریب رونمائی حیدرآباد سندھ میں منعقد ہوئی جس کی صدارت زیڈ اے بخاری نے کی تھی اور کہا جاتا ہے کہ یہ کسی کتاب کی پہلی باقاعدہ تقریبِ رونمائی تھی جس کے دعوت نامے بھی تقسیم کیے گئے تھے۔
کئی مشہور اور زباں زدِ عام اشعار کے خالق محسنؔ بھوپالی کا یہ قطعہ بھی ان کی پہچان بنا۔
تلقینِ صبر و ضبط وہ فرما رہے ہیں آج
راہِ وفا میں خود جو کبھی معتبر نہ تھے
نیرنگیٔ سیاستِ دوراں تو دیکھیے
منزل انہیں ملی جو شریک سفر نہ تھے
محسن بھوپالی کا یہ شعر ملاحظہ کیجیے۔
غلط تھے وعدے مگر میں یقین رکھتا تھا
وہ شخص لہجہ بہت دل نشین رکھتا تھا
پاکستان کی معروف گلوکارہ گلبہار بانو کی آواز میں محسن بھوپالی کی ایک غزل آج بھی بہت ذوق و شوق سے سنی جاتی ہے جس کا مطلع ہے۔
چاہت میں کیا دنیا داری، عشق میں کیسی مجبوری
لوگوں کا کیا، سمجھانے دو، ان کی اپنی مجبوری
اردو میں ’’نظمانہ‘‘ وہ صنفِ سخن ہے جس کے موجد محسنؔ بھوپالی نے افسانہ نگاری بھی کی تھی۔ انھوں نے آزاد نظم کی ہیئت میں ایک تجربہ کیا اور اپنی ایجاد کو تخلیقی وفور کے ساتھ وجود بخشا جو اخبارات اور رسائل و جرائد میں ’’نظمانے‘‘ کے طور پر شایع ہوئے اور باذوق قارئین نے انھیں پسند کیا۔ ’’نظمانے‘‘ کو ہم افسانے کی منظوم اور مختصر شکل کہہ سکتے ہیں۔
محسن بھوپالی کی شاعری ان کی فکر و دانش اور وسیع مطالعہ کے ساتھ معاشرے کے مختلف طبقات پر ان کی گہری نظر اور قوّتِ مشاہدہ کا عکس ہے۔
انھوں نے معاشرتی موضوعات کے ساتھ سیاسی حالات کو بھی اپنی شاعری کا موضوع بنایا جس کی مثال ان کا یہ قطعہ بھی ہے۔
جاہل کو اگر جہل کا انعام دیا جائے
اس حادثۂ وقت کو کیا نام دیا جائے
مے خانے کی توہین ہے، رندوں کی ہتک ہے
کم ظرف کے ہاتھوں میں اگر جام دیا جائے
محسن بھوپالی نے جاپانی ادب کو اردو کے قالب میں ڈھالا اور ہائیکو میں بھی طبع آزمائی کی۔ انھیں ایک ایسے شاعر کے طور پر یاد رکھا جائے گا جس کا اسلوب منفرد اور کلام شستہ و رواں ہے۔ محسن بھوپالی کی شاعری انسانی جذبات و احساست کے ساتھ اُن مسائل کا احاطہ بھی کرتی ہے جس سے عام آدمی کی طرح ایک شاعر بھی متأثر ہوتا ہے۔
محسن بھوپالی کراچی کے علاقے پاپوش نگر کے قبرستان میں آسودۂ خاک ہیں۔


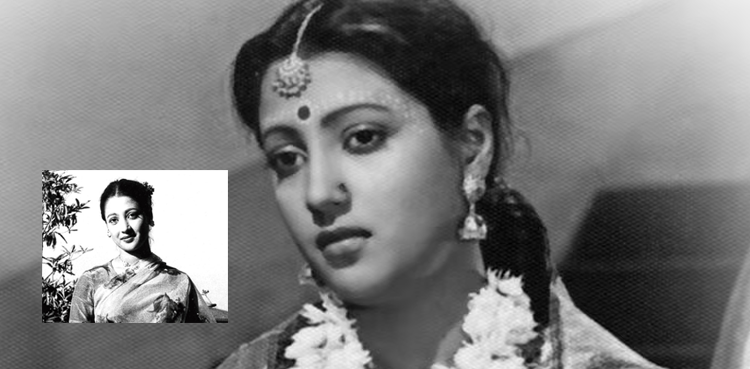



 "بات کورٹ کچہری تک گئی۔ ہائی کورٹ نے 27 دن کی کارروائی کے بعد 55 صفحات پر مشتمل فیصلہ دیا اور حکومت کے اس فعل کو غیر قانونی قرار دیا۔”
"بات کورٹ کچہری تک گئی۔ ہائی کورٹ نے 27 دن کی کارروائی کے بعد 55 صفحات پر مشتمل فیصلہ دیا اور حکومت کے اس فعل کو غیر قانونی قرار دیا۔”