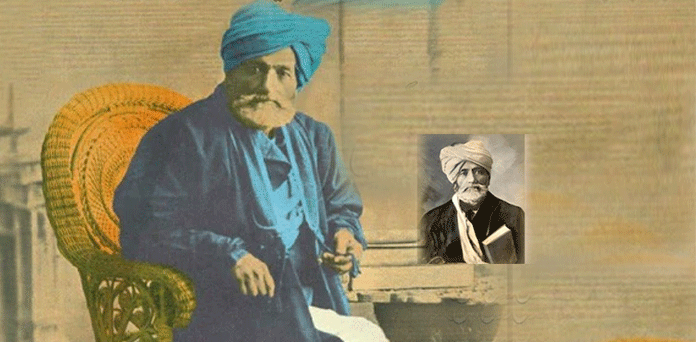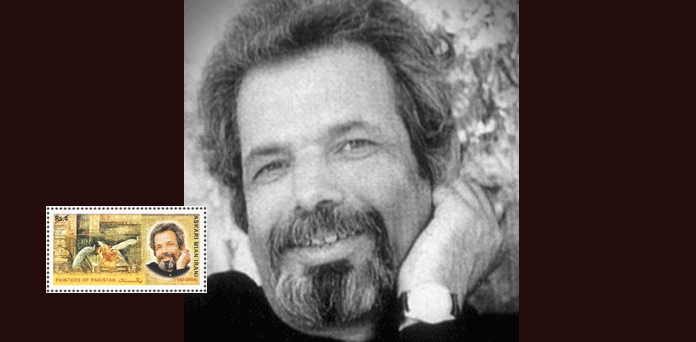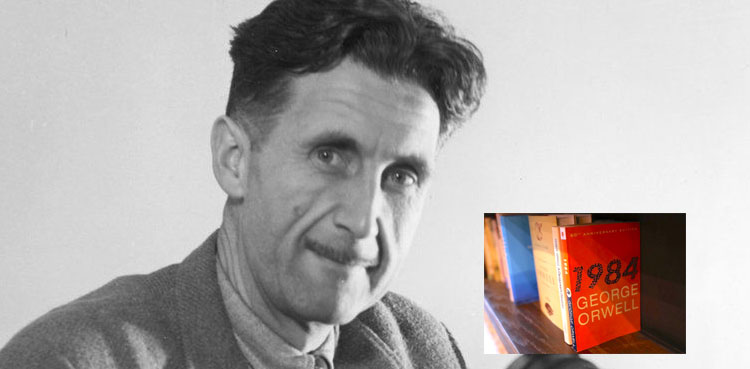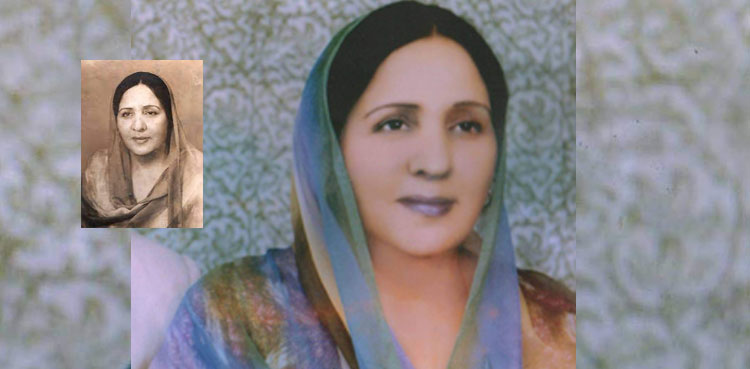اردو زبان کے معروف ناول نگار اور لکھنؤ سے نکلنے اردو کے مشہور ہفت روزہ اودھ پنچ کے مدیر منشی سجاد حسین کو آج کون جانتا ہے۔ اردو ادب اور صحافت کی دنیا کا یہ نام بڑا ہی نہیں بلکہ وہ نام تھا جس کے تخلیق کردہ کرداروں کو برطانوی ہندوستان اور تقسیم کے بعد بھی قارئین میں مقبولیت حاصل رہی۔
منشی سجاد حسین ڈپٹی کلکٹر منصور علی کا کوروی کے بیٹے تھے۔ وہ 1856ء میں کاکوری میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم گھر پر ہوئی۔ اس کے بعد انٹرنس کا امتحان پاس کیا اور مختلف قسم کے کام انجام دیے۔ فیض آباد چلے گئے اور کچھ دنوں تک فوجیوں کو اردو پڑھاتے رہے، پھر لکھنؤ واپس آکر 7 جنوری 1877ء میں اردو کا مشہور مزاحیہ اخبار اودھ پنچ نکالا۔ اس اخبار میں مزاحیہ اور طنزیہ مضامین کے علاوہ نظمیں اور غزلیں بھی شائع ہوتی تھیں۔ اودھ پنچ نے اردو نثر میں طنز و ظرافت کی روش کو عام کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ اس اخبار کی وجہ سے سرزمین ہند پر کئی نئے رسالوں کے لیے زمین ہموار ہوئی اور بعد میں اسی طرز پر اخبار نکالے گئے۔ اس اخبار نے مزاحیہ نگارشات کی اشاعت اور فروغ میں بڑا اہم کردار ادا کیا۔
منشی سجاد حسین ایک صحافی کے علاوہ ادیب اور ناول نگار کی حیثیت سے بھی پہچانے جاتے ہیں۔ ان کی تصانیف میں حاجی بغلول، طرح دار لونڈی، پیاری دنیا، احمق الذین، میٹھی چھری، کایا پلٹ اور حیات شیح چلی نمایاں ہیں۔ منشی سجاد حسین اپنے مزاح کی وجہ سے بہت مشہور تھے اور ان کے مضامین ہر خاص و عام کی توجہ حاصل کرلیتے تھے۔ مگر ان کا شمار اعلیٰ پائے کے ناول نگاروں میں بھی ہوتا ہے جو مزاحیہ ہی ہیں۔ ان کی زبان لکھنؤ کی بول چال کی زبان ہے اور اسی لیے ان کے کردار بھی عوام میں گویا اجنبی نہیں رہے تھے۔ ان کے تخلیق کردہ کرداروں میں مقبول ترین ان کے ناول کا کردار حاجی بغلول ہے۔
منشی سجاد کی تحریروں میں ہمیں مقصدیت ملتی ہے اور وہ سماج میں ناہمواریوں اور بدلتے ہوئے معاشی و معاشرتی پہلوؤں کی خامیوں کو اجاگر کرتے ہوئے اس پر تنقید کرتے رہے۔ حاجی بغلول منشی سجاد حسین کا وہ لازوال کردار ہے جسے ہر دور میں ناقدین نے سراہا اور ان کے ناولوں کو پسند کیا ہے۔
منشی سجاد حسین فالج کی بیمای کے سبب 22 جنوری 1915ء کو انتقال کر گئے تھے۔