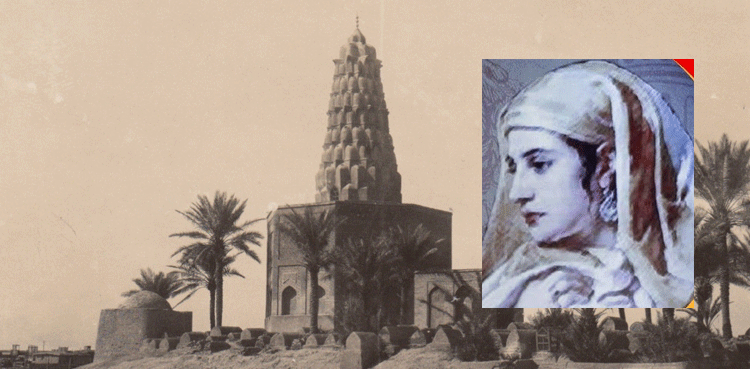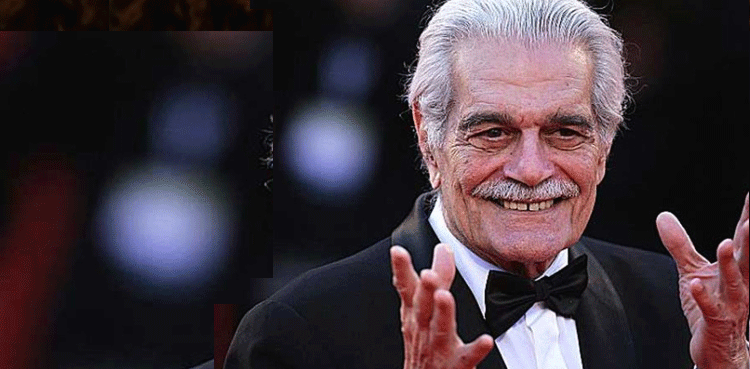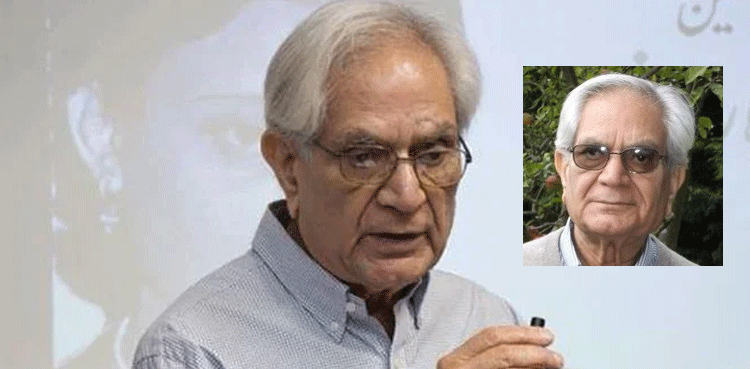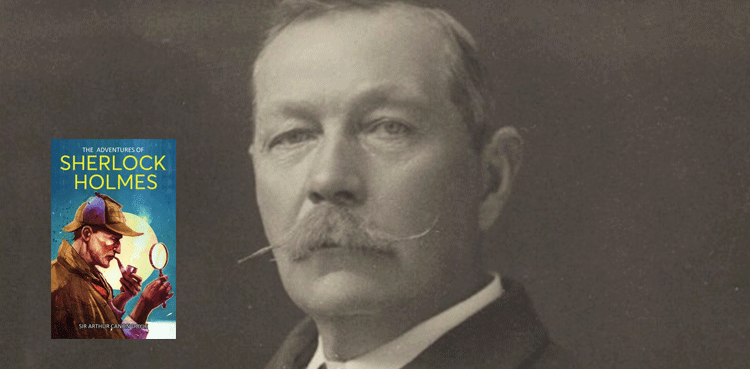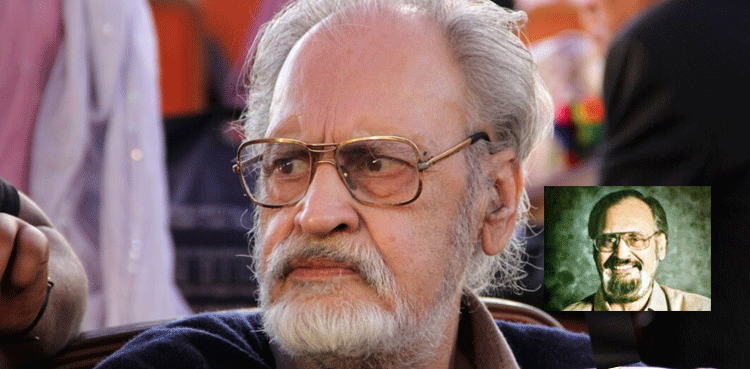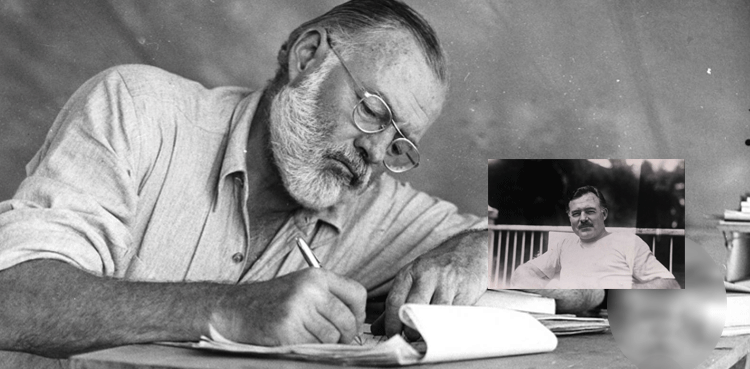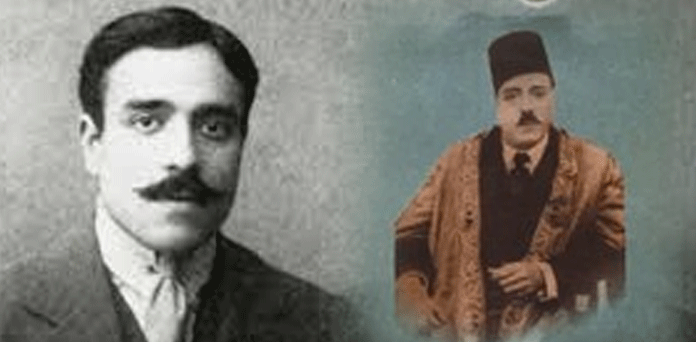سیّد راس مسعود کا نام اور ان کا تذکرہ ہمیشہ کیا جاتا رہے گا کہ وہ ہندوستان کی تاریخ اور مسلم تہذیب کا ایک معتبر حوالہ اور قد آور شخصیت ہیں، لیکن نوجوانوں کو بالخصوص ان کی علمی خدمات سے واقف ہونا چاہیے۔ متحدہ ہندوستان کی متعدد درس گاہوں اور جامعات کے لیے راس مسعود نے بحیثیت مدرس اور منتظم کار ہائے نمایاں انجام دیے۔ ایک ماہرِ تعلیم کی حیثیت سے انھیں ملک بھر میں بڑی عزّت اور تکریم کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔
راس مسعود، مصلح قوم اور ماہرِ تعلیم سر سید احمد خاں کے خاندان کے گلِ سرسبد تھے۔ ان کے والد مشہور ماہر قانون جسٹس سید محمود تھے۔ راس مسعود ان کے اکلوتے بیٹے اور سر سیّد احمد خاں کے پوتے تھے۔ سر سیّد نے اپنے پوتے کی ابتدائی تعلیم کا خوب اہتمام کیا۔ 1899ء راس مسعود کے والد انتقال کرگئے۔ راس مسعود نے میٹرک کا امتحان پاس کیا اور انٹرمیڈیٹ کا امتحان دیا نہیں تھا کہ حکومت ہند کی طرف سے ان کا تعلیمی وظیفہ لگ گیا۔وہ برطانیہ روانہ ہو گئے جہاں آکسفورڈ یونیورسٹی میں تعلیم مکمل کی۔ وہاں محمڈن اینگلو اورینٹل کالج کے سابق پرنسپل تھیوڈور موریسن کا گھر ان کا مستقر ٹھہرا۔ یہ ان شخصیات میں سے تھے جو راس مسعود کے دادا کے شریکِ کار اور ان کی علمی خدمات کے بڑے معترف بھی تھے۔ آکسفورڈ میں داخلہ کے لیے لاطینی کا امتحان پاس کرنا لازمی تھا۔ جس کے لیے ای ایم فورسٹر ان کے اتالیق مقرر ہوئے۔ اس طرح مسعود اور فورسٹر میں رفاقت کا آغاز ہوا اور وہ اچھے دوست بھی بنے۔ راس مسعود نے 1907 کو نیو کالج آکسفورڈ میں تعلیم کا آغاز کیا۔ تین سال بعد 1910 میں بی اے آنرز کی ڈگری حاصل کی اور پھر لنکنز اِن سے بیرسٹری کی سند لے کر 1912 میں ہندوستان واپس لوٹے۔ یہاں پٹنہ میں وکالت شروع کی۔ لیکن پھر اگلے سال ملازمت ملنے پر پٹنہ میں کالج کے پرنسپل کے طور پر ان کا تقرر ہوا۔ یہ تعلیم و تدریس کا شعبہ انھیں بہت بھایا اور اپنی صلاحیتوں اور محنت و لگن کے ساتھ راس مسعود نے حیدرآباد دکن میں ڈائریکٹر ایجوکیشن، علی گڑھ میں وائس چانسلر اور بھوپال میں بطور وزیرِ تعلیم جو خدمات انجام دیں وہ ناقابلِ فراموش ہیں۔ 1916 سے 1928 تک حیدر آباد دکن میں ان کا بڑا نام و مقام رہا۔ حضور نظام نے انھیں مسعود جنگ کے خطاب سے نوازا تھا۔راس مسعود پرائمری کی تعلیم کو بہت اہمیت دیتے تھے۔ 1921 میں پوری ریاست میں تعلیم مفت قرار دی گئی۔ انھوں نے پوری ریاست میں تعلیمی اداروں کا گویا جال بچھا دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ کتابوں کی اشاعت اور ان کی ترویج کا بڑا کام کیا۔ جامعہ عثمانیہ کے قیام کے لیے نظامِ دکن نے خصوصی دل چسپی لیتے ہوئے دل کھول کر رقم خرچ کی اور کلیہ جامعہ عثمانیہ کے پرنسپل راس مسعود مقرر ہوئے۔ متعدد عہدوں پر کام کرتے ہوئے جب جامعہ کے دستور کی تیاری کا موقع آیا تو اس میں بھی راس مسعود نے بڑا ہاتھ بٹایا اور جامعہ کا آئین اور قواعد و ضوابط مرتب کیے۔
وہ جب علی گڑھ میں وائس چانسلر کے عہدہ سے مستعفی ہوئے تو انگلستان چلے گئے اور واپس آنے پر نواب صاحب ریاست بھوپال نے ان کو وزیر تعلیم مقرر کیا۔ تادم آخر اس عہدہ پر فائز رہے اور خدمات انجام دیں۔ جس زمانہ میں وہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے وائس چانسلر تھے حکومت برطانیہ کی طرف سے ان کو نائٹ ہڈ کا خطاب عطا ہوا۔
راس مسعود نے خرابی صحت کی بناء پر حیدر آباد کی ملازمت سے 1928 میں استعفیٰ دیا تھا اور بغرضِ علاج انگلستان روانہ ہو گئے تھے۔ بعد میں بہ سلسلۂ علاج جب وہ جرمنی میں مقیم تھے تو ان کو دو متضاد عہدوں کی پیش کش ہوئی۔ حیدر آباد میں پولیٹیکل سیکرٹری کا عہدہ اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے وائس چانسلر کا۔ لیکن انھوں نے علی برادران کے کہنے پر علی گڑھ میں 1929 میں وائس چانسلر کا عہدہ سنبھالا۔ علی گڑھ یونیورسٹی کے تنِ مردہ میں راس مسعود نے دل سوزی اور دل جمعی سے نئی روح پھونک دی اور پانچ سالہ دور میں وہاں انقلابی تبدیلیاں رونما ہوئیں۔
سَر راس مسعود کے حالاتِ زندگی جاننے سے پہلے ان کے بارے میں یہ تحریر پڑھیے جو اردو کے ایک صاحبِ طرز ادیب سیّد یوسف بخاری دہلوی کی کتاب ”یارانِ رفتہ“ سے لی گئی ہے۔ وہ لکھتے ہیں:
سر راس مسعود کی شخصیت اور اُن کی زندگی کے کارنامے جو جریدہ عالم پر ثبت ہیں اس وقت میرا موضوع سخن نہیں۔ اکتوبر 1935 میں اپنے عزیز دوست پروفیسر محمد اختر انصاری علیگ کے ہاں علی گڑھ میں مہمان تھا۔ اسی مہینے کے آخری ہفتہ میں مولانا حالی مرحوم کا صد سالہ جشن (سال گرہ) پانی پت میں ہونے والا تھا۔
وہ جذبہ تھا یا صوتِ حالی، اسی خیالی رو میں اختر کے ہمراہ بہہ کر پانی پت میں جا نکلا۔ جب ہم وہاں پہنچے تو رات بھیگ چکی تھی۔ رضا کار جلسہ گاہ کے قریب ایک بہت بڑے میدان میں خیموں کی ایک عارضی بستی میں لے گئے۔ باقی رات ہم نے ایک خیمے میں گزاری۔ صبح ناشتے سے فارغ ہوتے ہی ہم نواب صاحب بھوپال کے استقبال کے لیے اسٹیشن چلے گئے۔
میں گاڑی کے انتظار میں پلیٹ فارم پر ٹہل رہا تھا کہ ناگاہ میرے کانوں میں ”یوسف“ کی آواز آئی۔ پلٹ کر دیکھا تو میرے قریب میرے عم بزرگوار شمس العلما سید احمد، امام جامع مسجد دہلی کھڑے تھے۔ فرمایا ”تم بھی جلسے میں آئے ہو؟“
”جی ہاں“ میں نے جواباً عرض کیا۔ فرمانے لگے۔ ”سنو نواب حمید اللہ خاں کے ہمراہ راس مسعود بھی آرہے ہیں، میرے ساتھ رہنا، موقع پاکر تمہیں اُن سے بھی متعارف کرا دوں گا۔ یہ مسعود رشتے میں میرا بھتیجا ہے۔“
یہ ہم رشتہ ہونے کی بات پہلے بھی میرے کانوں میں پڑچکی تھی۔ لیکن اُس کی کڑیاں آج تک پوری طرح نہیں ملیں۔ خیر میں تو اس لمحے کا پہلے ہی سے متمنی تھا۔ میں نے امام صاحب سے عرض کیا۔
”میں نواب سَر راس مسعود کو اپنی کتاب ’موتی‘ بھی پیش کرنا چاہتا ہوں۔“ یہ کہہ کر میں نے اُن کو اپنا رومال دکھایا جس میں وہ کتاب لپٹی ہوئی تھی۔
”اچھا! تو تم اس لیے یہاں آئے ہو۔“ معاً گاڑی آگئی۔ والیِ بھوپال کے شان دار استقبال اور اُن کی روانگیِ جلسہ گاہ کے بعد امام صاحب نے راس مسعود سے میرا تعارف کرایا،
”مسعود! یہ میرے چھوٹے بھائی حامد کا بڑا لڑکا یُوسف ہے۔ یہ تمہیں اپنی کتاب پیش کرنا چاہتا ہے۔“ سَر راس مسعود نے یہ سُن کر میرا سلام لیا اور مسکراتے ہوئے فرمایا، ”ہاہا! میرے بھائی کا بچہ یوسف ثانی! آؤ جانی میرے گلے لگو۔“
پھر کتاب لے کر فرمایا، ”میں اسے کلکتہ سے واپس آکر اطمینان سے پڑھوں گا۔ بھوپال پہنچ کر تمہیں اس کے متعلق کچھ لکھوں گا۔“
اس کے بعد ہم دونوں جلسہ گاہ میں گئے۔ امام صاحب آگے آگے میں اُن کے پیچھے پیچھے، جب اسٹیج کے قریب آئے تو امام صاحب کو اسٹیج پر جگہ دی گئی۔ میں فرش پر پہلی قطار میں ایک خالی کرسی پر بیٹھنے ہی والا تھا کہ سَر راس مسعود نے اپنی گردن کے اشارے سے مجھے اوپر بلایا۔ پھر اُنگلی سے دائیں طرف ایک کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ ایاز قدرِ خود بہ شناس کے مصداق یہ جگہ تو میرے خواب و خیال میں بھی نہ تھی۔
اس ایک روزہ اجلاس کی تمام کارروائی مقررہ نظام کے مطابق انجام پذیر ہوئی۔ اس نشست میں ان آنکھوں کو ڈاکٹر اقبال کا پہلا اور آخری دیدار نصیب ہوا۔
وہیں میرے کانوں میں وہ نوائے سروش بھی گونجی جس کی مجھے ایک مدّت سے تمنا تھی۔ وہ خطبہ حمیدیہ بھی سُنا جو والیِ بھوپال نے ارشاد فرمایا تھا اور وہ اعلان عطیہ بھی جو مرحوم راس مسعود نے والیِ بھوپال کے ایما پر کیا تھا۔
جلسے کے اختتام سے قبل راس مسعود نے حاضرین اسٹیج میں سے بعض کو وہ رقعات بھی تقسیم کیے جو جلسے کے بعد ظہرانہ کے متعلق تھے۔ رقعات دیتے وقت جب وہ میرے قریب آئے تو بااندازِ سرگوشی فرمایا، ”یوسف! تم بھی جلسے کے بعد ہمارے ہی ساتھ کھانا کھانا۔“ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ کاش اُس دعوت کا وہ فوٹو مجھے حاصل ہوتا جس میں، میں امام صاحب کے پہلو میں اور اُسی صف میں یکے بعد دیگرے نواب صاحب بھوپال، سر راس مسعود اور ڈاکٹر اقبال جیسے اکابرِ وقت شریک طعام تھے۔
سر راس مسعود 15 فروری 1889ء کو پیدا ہوئے تھے اور گھر پر مذہبی تعلیم کے ساتھ ابتدائی کتب کی مدد سے لکھنا پڑھنا سیکھا، پانچ سال کے ہوئے تو اسکول جانے لگے۔ بعد میں ان کو علی گڑھ کالج کے پرنسپل مسٹر موریسن اور ان کی بیگم کی نگرانی میں دے دیا گیا اور والد کی وفات کے بعد راس مسعود کی تعلیم و تربیت انھوں نے ہی کی۔ راس مسعود انجمن ترقیِ اردو کے بھی صدر تھے۔ تحریکِ آزادی اور مسلمانوں کے حق کے لیے انھوں نے اپنی تعلیمی مصروفیات سے وقت نکال کر تحریر و تقریر سے خوب کام لیا، لیکن ان کی پہچان ایک سیاسی مدبر کی نہیں ہے۔ راس مسعود کی تصنیف و تالیف کردہ کتب میں انتخابِ زرین، سرسیّد کے خطوط، اردو کے مستند نمونے شامل ہیں۔
شاعرِ مشرق علّامہ اقبال کے دوستوں اور احباب کا حلقہ خاصا وسیع تھا، لیکن جن لوگوں سے اُنھیں ایک گہرا اور دلی تعلق خاطر تھا، وہ گنے چُنے ہی تھے اور ان میں سر راس مسعود کا نام سر فہرست ہے۔ 1933ء میں آپ افغانستان کے دورہ میں اقبال کے ہمراہ تھے۔ اقبال نے ان کی اچانک وفات پر "مسعود مرحوم” کے عنوان سے نظم بھی لکھی تھی۔ راس مسعود 30 جولائی 1938ء کو وفات پاگئے تھے۔