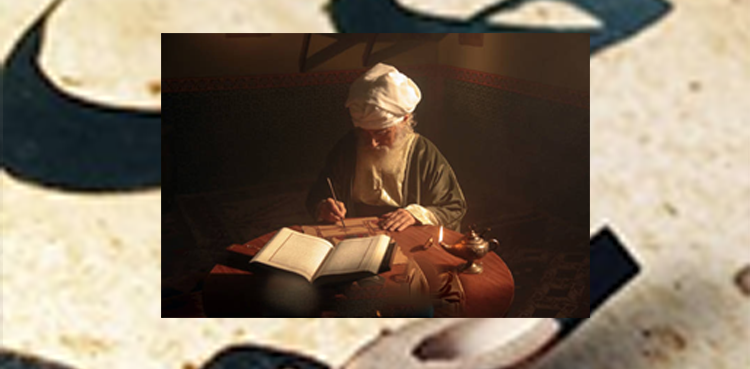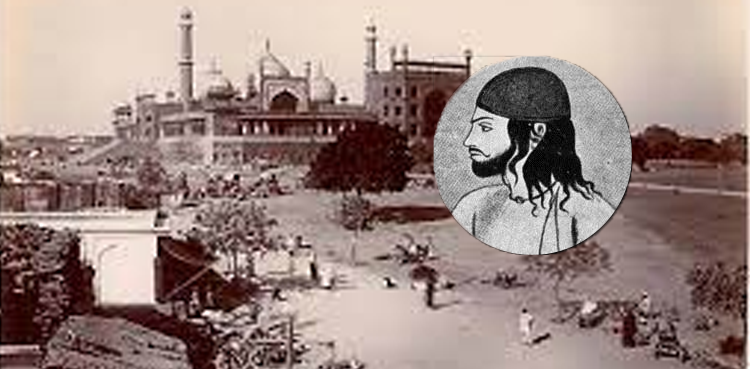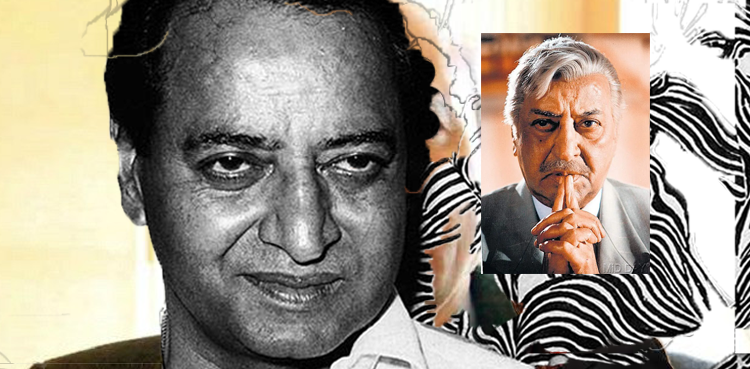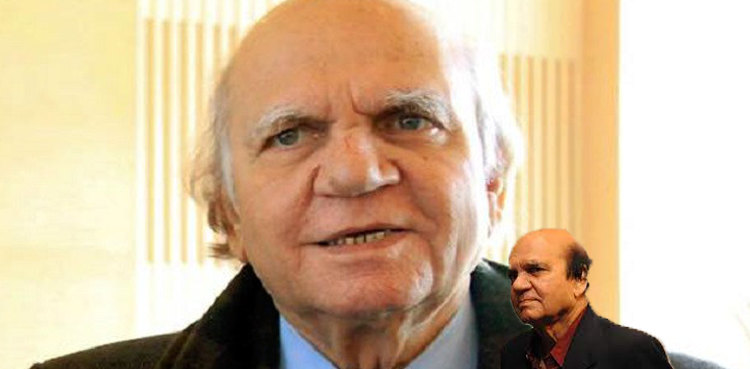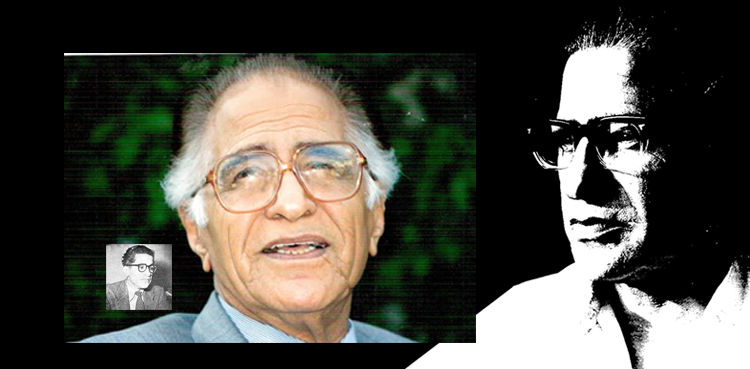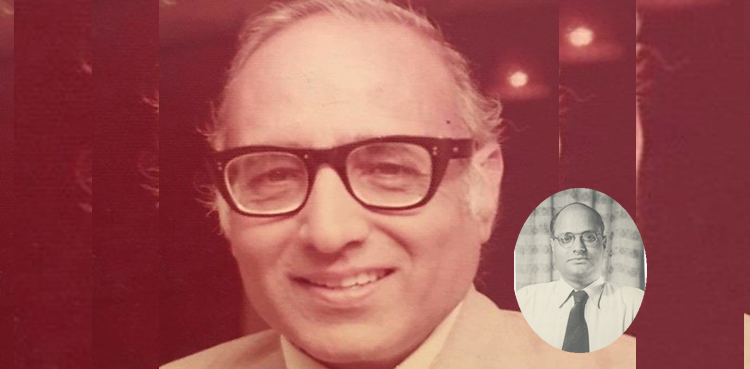دنیائے عرب میں خوش نویسی ایک ایسا فن رہا ہے جس سے پاکیزگی اور روحانی مسرّت کا تصوّر جڑا ہوا ہے اور اسی فن کی ایک نہایت ممتاز اور معروف شکل خطّاطی کو عالمِ اسلام میں باعثِ برکت و اعزاز سمجھا جاتا ہے ابنِ مقلہ عباسی دور کے ایک باکمال اور استاد خطّاط گزرے ہیں۔ وہ قدیم علمی و ثقافتی مرکز بغداد کے تین مشہور خطّاط میں سے ایک اور ایسے نادرِ روزگار ہیں جنھوں نے پہلی مرتبہ عرب دنیا میں فنِ خطّاطی کو قواعد و ضوابط کے ساتھ متعدد طرزِ تحریر دیے۔
20 جولائی 940ء کو ابنِ مقلہ اس دارِ فانی سے کوچ کرگئے تھے۔ محققین کے مطابق ان کا سنہ پیدائش 886ء ہے۔
ابنِ مقلہ عباسی دربار میں وزیر رہے اور سیاست میں ان کا بڑا عمل دخل تھا۔ تاریخ کے اوراق بتاتے ہیں کہ ابنِ مقلہ اپنے ابتدائی زمانہ میں ایک غیر اہم اور کم آمدن شخص تھے۔ ابنِ کثیر جیسے جیّد نے ابنِ مقلہ کے بارے میں لکھا کہ ان کے حالات ناگفتہ بہ تھے، لیکن قسمت نے پلٹا کھایا تو خلافتِ عباسیہ کا تین بار وزیر بنا۔ اسی طرح خطّاطی کی تاریخ سے متعلق کتاب میں سیّد محمد سلیم لکھتے ہیں کہ آغازِ کار میں ابنِ مقلہ دفترِ مال (دِیوانی) میں ملازم ہوا تھا۔ یہ ملازمت ایران کے کسی علاقے میں اُسے حاصل ہوئی تھی۔ بعد ازاں وہ ابی الحسن ابنِ فرات کا ملازم ہوا اور بغداد چلا آیا۔ بغداد میں اُس کی قابلیت کے جوہر کھلے اور یہاں اُس کی بیش بہاء قدر دانی بھی ہوئی۔ کہا جاتا ہے کہ روم و عرب کی جنگ کے بعد صلح نامہ اُس نے اپنے قلم سے لکھ کر روم بھیجا تھا جو وہاں فن (آرٹ) کے شاہکار کی حیثیت سے مدتوں شہنشاہِ روم کے خزانہ میں موجود رہا۔
کہتے ہیں کہ خلیفہ المقتدر باللہ نے 924ء میں ابنِ مقلہ کو وزیر مقرر کیا تھا۔ لیکن پھر ایک سازش کے نتیجے میں وہ روپوش ہونے پر مجبور ہوا اور یوں یہ عہدہ اس کے ہاتھ سے گیا، بعد میں حالات بہتر ہوئے تو وہ دربار میں پہنچا اور اسی منصب پر فائز ہوا۔ ابن مقلہ کو خلیفہ راضی باللہ کے زمانہ میں عروج حاصل ہوا۔ لیکن ایک مرتبہ پھر محلّاتی سازشوں کا شکار ہوا اور اس مرتبہ قید کے ساتھ سخت جسمانی تکالیف بھی جھیلنا پڑیں۔
قید خانے ہی کی صعوبتیں جھیلتے ہوئے ہی ابنِ مقلہ کا انتقال ہوا تھا۔ ابنِ مقلہ کا مکمل نام ابوعلی محمد بن علی بن الحسین بن مقلہ تھا۔ انھیں ابنِ مقلہ شیرازی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ ماہرِ فنِ تحریر اور خطّاط ابنِ مقلہ نے علومِ متداولہ کی تعلیم حاصل کی تھی۔ فقہ، قرأت، تفسیر اور عربی ادب میں ماہر تھے۔ انشاء اور کتابت و مراسلت پر زبردست گرفت تھی۔
بغداد میں ابنِ مقلہ نے اپنی قابلیت اور فن کا مظاہرہ اس طرح کیا کہ دربار سے عوام تک ان کی بڑی عزّت اور قدر کی گئی۔ دربارِ اکبری کے مشہور مؤرخ ابو الفضل نے اکبر نامہ میں لکھا ہے کہ ابنِ مقلہ نے آٹھ خطوط ایجاد کیے جن کا رواج ایران، ہندوستان، بلادِ روم اور توران میں ہے۔