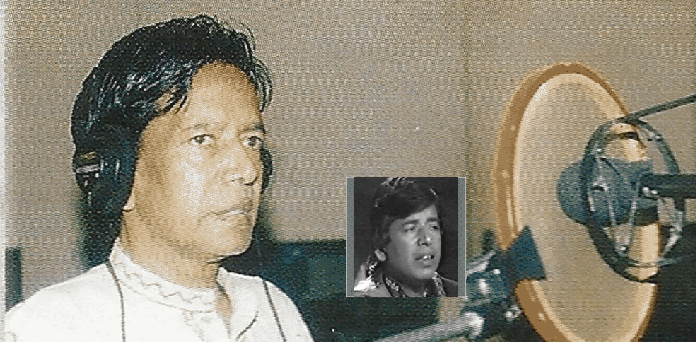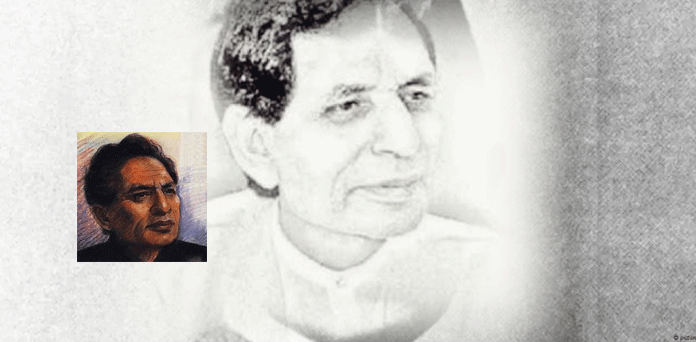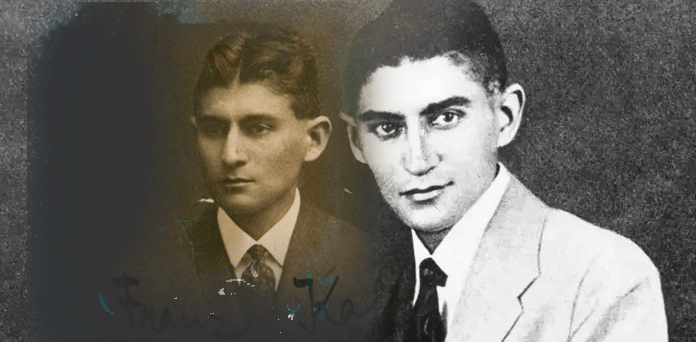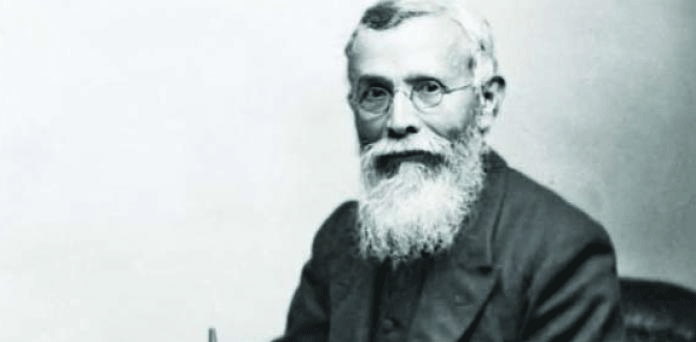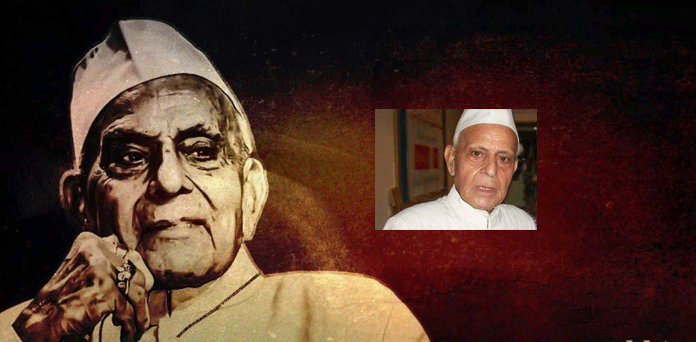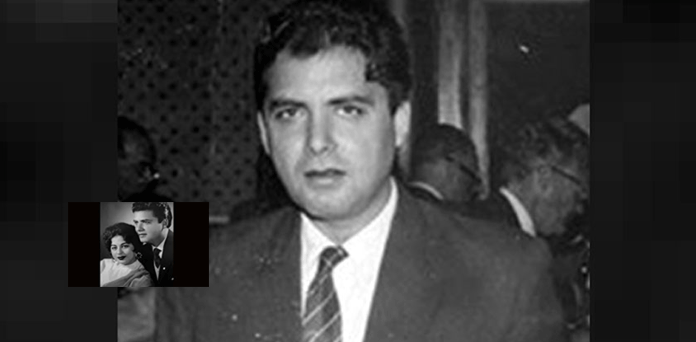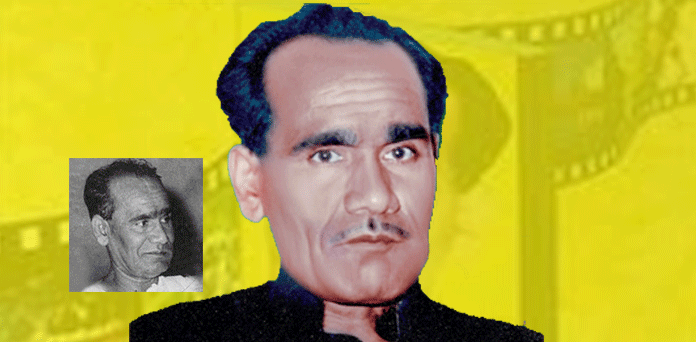بیسویں صدی کی ابتدائی دہائیوں میں یورپ کے جن اہلِ قلم اور ادیبوں نے اپنے تخلیقی کام کی وجہ سے نام و مرتبہ پایا اور دنیا بھر میں پہچانے گئے، ان میں سے ایک فرانز کافکا بھی ہے کافکا اپنے دور کا ایک نابغہ تھا جسے ستائش کی تمنا تھی اور نہ صلے کی پروا بلکہ وہ اپنی زندگی میں گویا گوشۂ گمنامی میں رہا اور اگر اس کا ایک دوست ‘وعدہ خلافی’ نہ کرتا تو شاید دنیا کافکا کو نہ جان پاتی۔
فرانز کافکا ایک اعلیٰ پائے کا ادیب تھا۔ اس کی آرزو تھی کہ بعد از مرگ اس کی تحریریں جلا دی جائیں۔ لیکن آج وہ سب تحریریں اُس کے ایک دوست کی وجہ سے عالمی ادب کا خزانہ ہیں۔ جرمنی کے معروف ادیب فرانز کافکا نے اپنے دوست میکس بروڈ کو وصیت کی تھی کہ وہ اس کی غیر مطبوعہ تخلیقات کو نذرِ آتش کر دے، لیکن میکس بروڈ نے کافکا اس کی وصیت پر عمل نہیں کیا۔
عالمی شہرت یافتہ جرمن افسانہ نگار کی کہانیاں بشمول اردو دنیا کی متعدد زباںوں میں ترجمہ کی گئیں۔ کافکا کے چند ادھورے ناول، افسانے اور اس کے تحریر کردہ خطوط بھی دنیا کے سامنے لائے گئے اور عین جوانی میں دارِ فانی سے کوچ کر جانے والے فرانز کافکا نے جیسے دوبارہ جنم لیا۔ فرانز کافکا کے ناول ’دی ٹرائل‘ اور ’دی کاسل‘ کو قارئین نے بہت سراہا اور ان کا کئی زبانوں میں ترجمہ کیا گیا۔ اس کی تماثیل جرمنی اور دنیا بھر میں مقبول ہیں۔
تین جون 1924ء کو کافکا چالیس سال کی عمر میں چل بسا تھا۔ کافکا کی پیدائش 1883ء میں چیکوسلاواکیہ کے ایک قصبے پراگ میں ہوئی۔ وہ یہودی گھرانے کا فرد تھا۔ کافکا نے ابتدائی تعلیمی مدارج طے کرتے ہوئے قانون میں ڈاکٹریٹ کی ڈگری لی۔ کافکا کا خیال تھا کہ والدین اسے پسند نہیں کرتے۔ وہ اپنی کئی محرومیوں اور مسائل کی وجہ سے خود کو حرماں نصیب اور بدقسمت خیال کرتا تھا۔ کافکا ذہین تھا، مگر خود اعتمادی سے محروم ہوگیا تھا۔ وہ نفیساتی طور پر حساسیت کا شکار ہوکر سب سے گریزاں رہا۔ کافکا نے شادی بھی نہیں کی تھی۔
قانون کی تعلیم مکمل کرنے کے بعد کافکا نے ایک انشورنس کمپنی میں ملازمت اختیار کرلی۔اس کے ساتھ قانون کی پریکٹس بھی شروع کردی۔ لیکن اسے ہمیشہ محرومی اور کم تر ہونے کا احساس ستاتا رہا۔ اس جرمن ادیب نے ایک مرتبہ خودکشی کی کوشش بھی کی مگر بچ گیا اور پھر اس کے دوست نے اس کو سنبھالا۔ بعد میں کافکا تپِ دق کی بیماری میں مبتلا ہو کر دنیا سے رخصت ہوا۔
کافکا کی ایک تمثیل ملاحظہ کیجیے جس کے مترجم مقبول ملک ہیں۔
ایک فلسفی ہمیشہ اسی جگہ کے ارد گرد گھومتا رہتا تھا جہاں بچے کھیلتے تھے۔ وہ جب کبھی بھی یہ دیکھتا کہ کسی بچے کے پاس لٹو ہے، تو وہ جھاڑیوں کے پیچھے تاک لگا کر بیٹھ جاتا۔ جیسے ہی لٹو گھومنے لگتا، فلسفی دوڑ کر جاتا اور اسے پکڑنے کی کوشش کرتا۔
وہ اس بات کی کوئی پروا نہ کرتا کہ بچے اسے اپنے کھلونے سے دور رکھنے کی کوشش کرتے۔ اگر وہ لٹو کو اپنے حصار میں لینے میں کامیاب ہو جاتا، تو جب تک لٹو گھومتا رہتا، فلسفی بھی خوش رہتا۔ لیکن پھر ایک ہی لمحے میں وہ لٹو کو زمین پر پٹخ دے مارتا اور آگے بڑھ جاتا۔ اسے یقین تھا کہ ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز کا علم اور شعور، مثلاً گھومتے ہوئے لٹو کا بھی، عمومی آگہی کے لیے کافی تھا۔ اسی لیے وہ خود کو بڑے مسائل پر غور و فکر میں مصروف نہیں رکھتا تھا۔ ایسا کرنا محنت اور نتائج کے حوالے سے اسے غیر سود مند لگتا۔
اسے لگتا تھا کہ کسی چھوٹی سے چھوٹی چیز کے چھوٹے پن کا بھی اگر واقعی علم ہو جائے، تو سب کچھ معلوم ہو جاتا ہے۔ اسی لیے تو وہ خود کو صرف ایک گھومتے ہوئے لٹو کے ساتھ ہی مصروف رکھتا تھا۔
یہی وجہ تھی کہ ہمیشہ جب کوئی لڑکا لٹو کو گھمانے کی تیاریوں میں مصروف ہوتا، تو اسے امید ہو جاتی کہ اب وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے گا۔ اس کے بعد جب لٹو گھومتا تو اپنے اکھڑے ہوئے سانس کے ساتھ وہ جیسے جیسے اس کا پیچھا کرتا، اس کی امید شعور میں بدلتی جاتی۔
لیکن پھر جیسے ہی وہ لکڑی کے اس فضول سے گول ٹکڑے کو ہاتھ میں لیتا تو اس کا جی متلانے لگتا۔ تب بچوں کی وہ چیخ پکار اور احتجاج بھی، جنہیں وہ تب تک سن نہیں پاتا تھا، اچانک اس کے کانوں کے بہت اندر تک پہنچنے لگتے۔ یہی چیخ پکار اور احتجاج اس کے وہاں سے فرار کا سبب بنتے، اسی طرح گرتے پڑتے، جیسے کسی لڑکے نے گھمانے کے لیے کوئی لٹو بڑے پھوہڑ انداز میں زمین پر پھینک دیا ہو۔