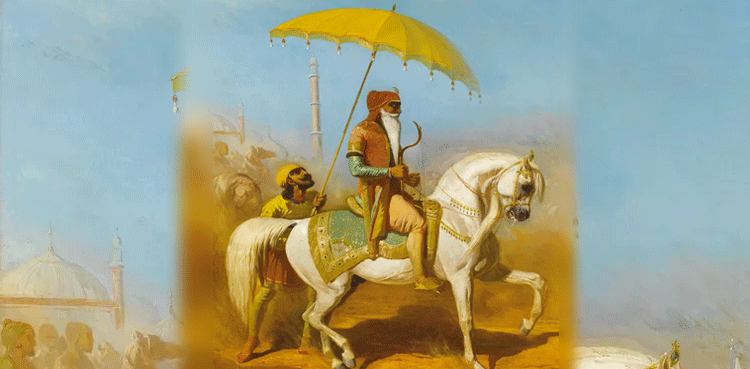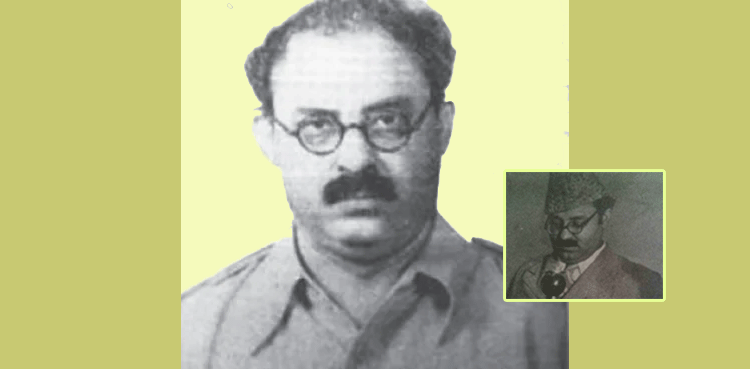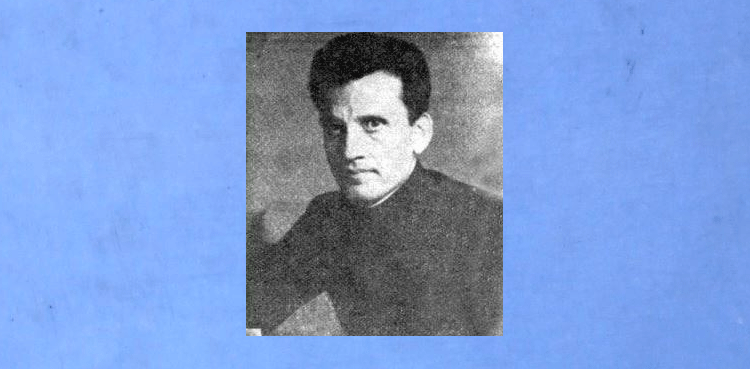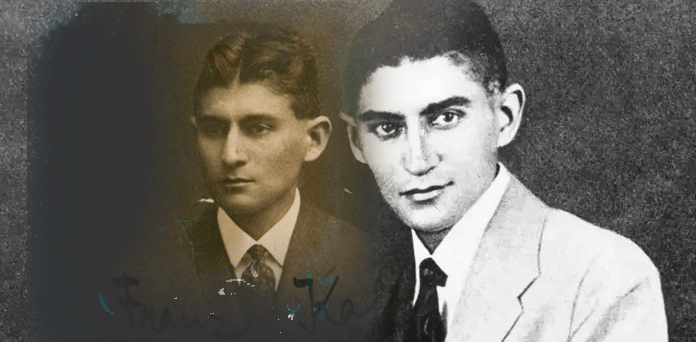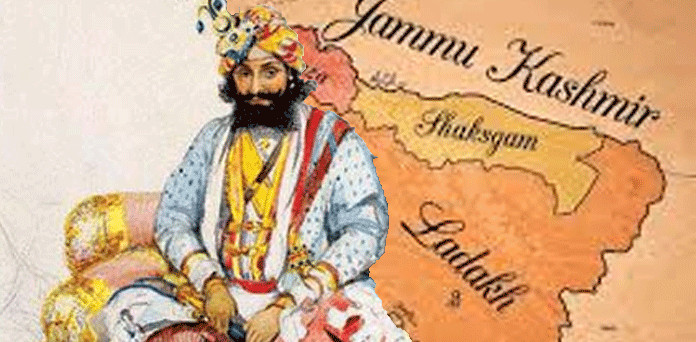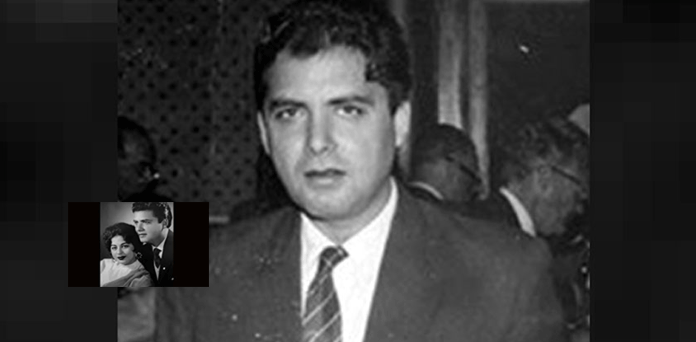ہندوستان پر قبضے کے بعد انگریزوں نے جس طرح یہاں سے اجناس اور اشیاء کی تجارت اور کاروبار سے خوب خوب مالی فوائد سمیٹے ویسے ہی قدرتی وسائل سے مالا مال ریاستوں کو بھی اپنے مفاد کی بھینٹ چڑھا دیا۔ جموں و کشمیر کا معاملہ کچھ ایسا ہی ہے جس میں انگریزوں نے اپنے مفاد کو ترجیح دی اور وہاں کے لوگوں کا سودا کردیا۔
جموں کا ہندو راجہ گلاب سنگھ جو اپنی رعایا پر ظلم و ستم ڈھانے کے لیے مشہور ہے، آج ہی کے دن چل بسا تھا۔ وہ سکھ سلطنت کے بانی اور مہاراجہ رنجیت سنگھ کی مہربانی سے جموں کا حاکم بنا تھا۔ اس کا تعلق ہندو ڈوگرا برادری سے تھا۔ یہ سنہ 1822ء کی بات ہے۔ بعد میں گلاب سنگھ نے کئی علاقوں پر اپنا تسلط قائم کرلیا جن میں راجوری، پونچھ، بدرواہ اور کشتوار اور کئی دوسرے علاقے شامل ہیں۔
پنجاب میں قدم جمانے کے بعد انگریزوں نے گلاب سنگھ کو مہاراجہ بنا دیا اور 1846ء میں معاہدۂ امرتسر کے تحت پچھتر لاکھ روپے میں کشمیر بھی اس کو دے دیا۔ جموں و کشمیر کا مہاراجہ بن کر گلاب سنگھ نے سفاکی اور قتل و غارت گری کا ایک باب رقم کیا اور اس کے دور میں لوگوں سے غیرانسانی سلوک کی بدترین مثالیں سامنے آتی رہیں۔ گلاب سنگھ کے مظالم کا ذکر ایسٹ انڈیا کمپنی کے گورنر جنرل سَر ہنری ہارڈنج کے اپنی بہن کے نام لکھے گئے ایک خط میں ملتا ہے جو دو مارچ 1846 کو ارسال کیا گیا تھا۔ اس خط میں وہ گلاب سنگھ کو ’ایشیا کا سب سے بڑا بدمعاش‘ لکھتے ہوئے بہن کو بتاتا ہے کہ گلاب سنگھ کو مہاراجہ بنانے کی وجہ کیا رہی اور اسے انگریز سرکار کی بدقسمتی لکھا ہے۔ اس مکتوب میں گورنر جنرل نے رقم کیا: ’بدقسمتی سے ان کی مدد کرنا لازمی ہے کیونکہ انھوں نے ہمارے خلاف جنگ میں حصہ نہیں لیا اور ان کی سرحدیں ہماری سرحدوں سے ملتی ہیں، ہم بغیر کسی مشکل ان کی حفاظت کر سکتے ہیں اور سکھوں کی سلطنت میں سے انھیں ایک ٹکڑا دے کر سکھوں کے مقابلے میں ان کی طاقت کو تھوڑا بڑھا سکتے ہیں۔‘
گلاب سنگھ کی ڈوگرا سلطنت سو برس سے زیادہ عرصہ قائم رہی جو بادشاہت پر مبنی مطلق العنان طرزِ حکومت تھا۔ برطانیہ میں بھی کشمیر کو ڈوگرا راجہ کے ہاتھوں فروخت کرنے پر کڑی تنقید کی گئی تھی، کیوں کہ اس رقم کو وصول کرنے کے لیے راجہ نے عام کشمیریوں پر بہت بھاری ٹیکس لگایا اور وصولی کے لیے ہر طرح کا جبر، زبردستی اور مظالم کیے گئے۔ ظالمانہ ٹیکس نظام کے علاوہ ڈوگرا دور میں بیگار کا بھی سلسلہ شروع ہوگیا تھا جس پر انگریز افسران نے بھی کڑی تنقید کی۔
ہندوستان میں برطانوی فوج کے ایک افسر رابرٹ تھورپ نے لکھا تھا کہ اس ناانصافی سے ’جدید تہذیب کی روح کی نفی ہوتی ہے اور اُس مذہب کے ہر اصول کے بالکل الٹ ہے جس کے پیروکار ہونے کا ہم دعوی کرتے ہیں۔‘
پنجاب میں سکھ حکم راں رنجیت سنگھ نے اپنے ایک منتظم گلاب سنگھ کو اپنے لیے خدمات انجام دینے کے صلے میں جمّوں کا راجا بنایا۔ گلاب سنگھ کا باپ رنجیت سنگھ کی جانب سے جمّوں کا انتظام دیکھتا رہا تھا اور اس کی موت کے بعد گلاب سنگھ کو یہ ذمہ داری منتقل ہوئی تھی جس میں وہ کام یاب رہا اور مہاراجہ کا اعتماد حاصل کرلیا۔ بعد میں انگریزوں سے وفا کر کے اس نے اپنی سلطنت قائم کر لی تھی۔
گلاب سنگھ ڈوگرا کا سنہ پیدائش 1792ء بتایا جاتا ہے جب کہ اس کی موت 1857ء میں آج ہی کے روز ہوئی تھی۔ انگریز افسران اور برطانوی امراء کے علاوہ متعدد برطانوی مؤرخین نے بھی گلاب سنگھ کی سفاکیوں کا ذکر کیا ہے۔ اس وقت علّامہ اقبال اور دیگر مسلمان اکابرین بھی گلاب سنگھ کے رعایا پر مظالم کی مذمت کرتے ہوئے انگریز سرکار کو مطعون کیا۔ اس حوالے سے یہ تحریر ملاحظہ کیجیے۔
"جمّوں سے تعلق رکھنے والے تین بھائی گلاب سنگھ، دھیان سنگھ اور سچیت سنگھ تھے۔ سکھ سلطنت میں یہ بااثر اور طاقت ور تھے۔ سکھ سلطنت میں کئی اہم عہدوں پر غیر سکھ رہے تھے اور جمّوں کے یہ بھائی بھی ان میں سے تھے۔ جمّوں اور پنجاب کے درمیان کوئی خاص جغرافیائی حدِ فاصل نہیں تھی۔ اور نہ ہی اس وقت سیاسی طور پر کچھ فرق تھا۔ لوگوں کا ایک دوسرے علاقے میں بہت آنا جانا تھا۔”
"لاہور سے سری نگر کے 180 میل سفر کے نصف راستے پر جموں شہر آتا تھا۔ جمّوں سے لاہور کا سفر، جمّوں سے سری نگر کے مقابلے میں بہت آسان تھا۔ اس لیے یہاں رہنے والوں کے زیادہ معاشرتی یا تجارتی روابط کشمیر کے مقابلے میں پنجاب سے تھے۔ آج پنجاب اور جمّوں کے درمیان سیاسی رکاوٹیں ہیں، لیکن سکھ حکومت کے وقت ایسا نہیں تھا۔ یہ عملاً پنجاب کی ایکسٹینشن تھی۔ جمّوں کے حکم رانوں کی پنجاب میں زمینیں تھیں اور یہی دوسری سمت میں بھی تھا۔”
"لاہور سکھ سلطنت کا دارُالحکومت تھا اور غیرسکھ آبادی کے لیے پرکشش شہر تھا۔ سکھ آرمی میں بہت سے مسلمان اور ہندو شامل تھے اور کچھ کرسچن بھی۔ اس میں یورپی افسر بھی شامل تھے۔ لاہور دربار میں ان سب کو ترقی کے مواقع میسّر تھے۔ اور ان ترقی کے مواقع سے گلاب اور دھیان سنگھ نے بہت فائدہ اٹھایا تھا۔ انھوں نے سکھ سلطنت کو بڑھانے میں بڑا کردار ادا کیا تھا۔ یہ رنجیت سنگھ کے معتمد تھے۔”
"1831ء میں ایک فرنچ مؤرخ نے لکھا ہے کہ “اگرچہ گلاب سنگھ ناخواندہ ہیں، لیکن رنجیت سنگھ کے پسندیدہ ہیں اور میرے خیال میں اگلے حکم ران بنیں گے۔” سکھ سلطنت نے ان بھائیوں کو اپنے علاقوں اور جاگیروں میں خودمختاری دی ہوئی تھی۔ (اس وقت میں سیاست کا طریقہ یہی ہوا کرتا تھا)۔”
"جب رنجیت سنگھ نے لاہور پر قبضہ کیا تھا تو گلاب سنگھ سات سال کے تھے۔ رنجیت نے 1808ء میں جموں کے علاقے پر قبضہ کر کے یہاں کی خودمختاری ختم کر دی تھی۔ اس وقت گلاب سنگھ کی عمر سترہ برس تھی اور وہ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے۔ ان کی شہرت جمّوں کی بغاوت کے دوران بڑھی۔ انھیں مقامی علاقے کا علم تھا۔ چالاکی اور سفاکی میں ان کی شہرت تھی۔ جمّوں حکومت کرنے کے لیے مشکل جگہ تھی۔ یہاں پر لوگوں پر کنٹرول رکھنا اور ٹیکس وصول کرنا آسان نہیں رہا تھا۔ اپنی دہشت کی وجہ سے گلاب سنگھ ٹیکس نکلوانے میں اتنے مؤثر رہے تھے کہ ایک مؤرخ نے انھیں “جمّوں کا ویمپائر” کہا ہے۔”